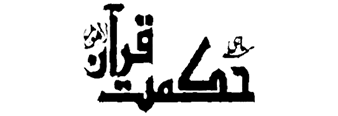(تعلیم و تعلم) مباحث ِعقیدہ (۲۱) - مؤمن محمود
8 /مباحث ِعقیدہ(۲۱)مؤمن محمود
صفت کلام پر گزشتہ ابحاث کا خلاصہ
پچھلی تین نشستوں میں صفت ِکلام کے حوالے سے گفتگو کی گئی تھی اور یہ دیکھا گیاکہ کلام سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت یعنی کلامِ نفسی ہے اور اس پر دلیل اللہ کا وہ کلام ہے جو الفاظ اور حروف کی صورت میں ہم تک پہنچا ‘ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں ۔ صرف یہی قرآن ہی اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اس سے قبل بھی جو کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی کلام اللہ ہیں اور وہ بھی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ِقدیمہ جو صفت کلام نفسی ہے ‘اس پر دلیل ہیں۔ یہ صفت ِکلام جس کو ہم قرآن کہتے ہیں اور جو الفاظ اور حروف کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے‘ یہ بھی نظماً اور معناً یعنی لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ۔ لفظ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے لیکن یہ ایک براہِ راست مخلوق ہے جس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ۔لہٰذا لفظ بھی اللہ کی طرف سے ہے‘ معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ نہ اس میں اللہ کے رسول ﷺکا کوئی دخل ہےنہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا کوئی دخل ہے ۔دونوں ہی پیغامبر ہیں جنہوں نے یہ پیغام پہنچایا ہے۔ صرف قرآن مجید سے تعلق کے حوالے سے بات کی گئی کہ قرآن مجید کا لفظ اس کے معنی سے ہماری نسبت سے بڑا ہے ۔اگرچہ قرآن مجید کا لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت ِکلام کے مقابلے میں تو نہیں ہے کیونکہ صفت ِکلام قدیمہ اور لامحدود ہے جبکہ لفظ مخلوق اور محدود ہوتا ہے ‘لیکن ہماری نسبت سے لفظ اس لیے بڑا ہے کہ ہم لفظ کے اندر جتنے معنی پوشیدہ ہیں ان کو کبھی بھی مکمل طور پر برآمد نہیں کر سکیں گے اور لفظ ہمیشہ نئے معنی دینے کے لیے مستعد رہے گا ۔ معنی میں ہمارے ذہن اور فہم کا عمل دخل ہوتا ہے لیکن لفظ میں انسانی کاوش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ۔لفظ جس طرح پہنچا ہے اسی طرح ہم نے پڑھنا ہے اور تواتر کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ پڑھنا کس طریقے پر ہے ۔ وہ بھی گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یعنی سیدنا جبرائیل ؑسے اللہ کے نبی ﷺ اور پھر ہم تک تواتر کے ساتھ یہ بات پہنچ گئی۔
پچھلی نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے لفظ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے ۔یعنی جس طرح قرآن مجید کے معنی سے ہم تعلق جوڑتے ہیں ‘لفظ سے بھی اسی طریقے پر تعلق جوڑا جائے ۔ پھر اس کی کچھ وضاحتیں کی گئی تھیں کہ جیسے علم تجوید بھی کُل کا کُل ایک فن اور علم ہے کہ لفظ پڑھنا کیسے ہے۔ خود اس علم نے بہت ترقی کی ہے اور بڑے بڑے قراء پیدا ہوئے۔ یہ علم بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ لفظ سے جڑنا ہے ۔ لفظ کی حسن ادائیگی کس طرح کی جائے گی‘ اس کے مخارج کیا ہیں اور اس کی صفات کیا ہیں ۔اتنی باریکیاں ہیں اس علم میں کہ ہم انہیں سمجھ بھی نہیں سکتے۔ بڑے بڑے قراء یہ باریکیاں سمجھتے ہیں اور ان کے اعتبار سے تلاوت کرتے ہیں ‘اور وہ تلاوت پھر ہمارے کانوں کو بہت خوش نما اور خوب صورت محسوس ہوتی ہے۔یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہم معنی کا انکار نہیں کر رہے تھے‘لیکن آج کل چونکہ قرآن مجید کو ایک فکری کتاب بنا دیا گیا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ قرآن ایک آلہ ہے ۔ آپ کو یہ الفاظ سننے کو ملیں گے کہ قرآن آلۂ انقلاب ہے ‘قرآن آلۂ فلاں ہے اور فکر کو پہنچانے کا ذریعہ ہے‘ حالانکہ قرآن بالذات ان مقاصد کے لیے نہیں ہے۔ قرآن تو فی نفسہٖ مقصود ہے۔ یہاں تک کہ کئی دفعہ کچھ خاص قسم کے معنی پر ارتکاز کی وجہ سے ایسی باتیں بھی سننے کو مل جاتی ہیں کہ اگر آپ قرآن کے ذریعے دعوت دے رہے ہیں اور لوگ قرآن سے جڑ رہے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں ہماری فکر یا جماعت سے نہیں جڑتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ گویا کئی دفعہ آپ کی تحریک ‘جماعت یا فکر قرآن کے برابر ہو جاتی ہے یعنی قرآن سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے جڑ جاؤ۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ‘قرآن تو ایک بڑی عظیم شے ہے ۔دین کبھی بھی کسی جماعت کے برابر تو نہیں ہوتا ۔یعنی دین سے جڑنے کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی خاص تحریک یا جماعت سے جڑنا ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے گا اس کے ہاں بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے اور وہ فرقہ بننے کا رجحان (tendency) اپنے اندر رکھے گا‘ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جماعت سے جڑنا ہی دین ہے اور دین سے جڑنے کا مطلب ہماری جماعت سے جڑنا ہے۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی وجہ سے قرآن مجید کے الفاظ اور خصوصاً تلاوت کا جوایک ذوق پیدا ہوا اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے اجنبیت دور کرنے کے لیے اور اس سے ایک نوع کا انس پیدا کرنے کے لیےقرآن کے لفظ سے جڑنا ضروری ہے ‘وگرنہ انسان قرآن مجید سے نہیں جڑتا ‘وہ کچھ افکار اور معنی سے جڑ جاتا ہے جن کو وہ قرآن سمجھ رہا ہوتا ہے‘ حالانکہ قرآن اور اس کے درمیان ایک نوع کا حجاب برقرار رہتا ہے۔ قرآن سے جڑنے کا مطلب ہے لفظ ِقرآن سے جڑنا اور اس کے نتیجے میں معنی سے جڑنا ۔قرآن سے جڑنے کا صحیح طریقہ یہی ہے۔ اللہ کے نبیﷺ کے جو وظائف بتائے گئے ہیں ان میں بھی یَتْلُوْا عَلَیْھِمْ اٰیٰتِہٖ ماقبل ہے اور تعلیم کتاب و حکمت مابعد ہے۔ علماء نے یہ بات بالکل صحیح اخذ کی ہے کہ تلاوتِ آیات فی نفسہٖ مقصود ہے ‘یعنی معنی اور تعلیم ِکتاب و حکمت کی طرح تلاوتِ آیات بھی فی نفسہٖ مقصود ہے۔
امام احمد بن حنبلؒ کا قول
اس ضمن میں امام احمد بن حنبل ؒ کے بیٹے عبداللہ نے اپنے والد محترم سےیہ بات نقل کی ہے کہ امام احمد بن حنبلؒ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خواب میں دیکھا -----اور دیکھنے سے مراد یہی ہے کہ ایک مثالی صورت میں دیکھا جو بھی ایک خواب کی دنیا ہوتی ہے -----تو انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا : آپ تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ کیا ہے ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : کَلَامِیْ‘کہ یہ میرا کلام ہے یعنی مجھ تک پہنچنے کا سب سے مختصر راستہ میرا کلام ہے۔ سیدنا احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا :بِفَھمٍ اَو بِدُونِ فَھمٍ؟ یعنی سمجھ کے پڑھنے سے آپ کے قریب ہوں گے یا بدونِ فہم بھی یہ قرب حاصل ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: بِفَہْمٍ وَبِدُونِ فَہْمٍ یعنی چاہے فہم کے ساتھ ہو‘ یا دونِ فہم ہو دونوں صورتوں میں قرآن مجید میرے قریب کرے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کلامِی الَّذِی خَرَجَ مِنِّی یعنی میرا وہ کلام جس کا صدور مجھ سے ہوا ہے۔گویا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے قریبی ذریعہ قرآن مجید ہے۔
جب ہم فتنوں والی روایات پڑھتے ہیں تو امام بیہقی علیہ الرحمہ نے’’ شعب الایمان‘‘ میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مشہور روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا:((اِنَّھَا سَتَکُوْنَ فِتْنَۃٌ)) کہ عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا‘تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا : مَا الْمَخْرَجُ مِنْھَا یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ؟ کہ اس میں سے نکلنے کی جگہ کیا ہے ؟ اللہ کے نبیﷺ نے جواب دیا:((کِتَابُ اللہِ‘ فِیْہِ نَبَاُ مَا قَبْلَکُمْ....الخ))۔ بہرحال یہ ایک طویل حدیث ہے جو قرآن مجید کی فضیلت پر ہے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم چونکہ فتنوں کے زمانے میں ہیں اور کوئی شخص اس کا منکر نہیں ہو سکتا‘ فتنے چاروں طرف ہیں تو قرآن مجید سے ایک صحیح تعلق یعنی تعلق بالقرآن قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تعلق اہل ِقرآن یا منکرین ِحدیث یا جدّت پسند لوگوں کی طرز پر نہیں ہوگا‘ بلکہ جس طریقے پر ہمارے سلف صالحین قرآن سے جڑتے چلے آئے اور تمام ائمہ قرآن کی تلاوت سے گہرا شغف رکھتے تھے۔ خواہ ہم یہاں بیان کرتے رہیں کہ امام ابن تیمیہؒ اور امام غزالیؒ میں ایسے ایسے اختلافات تھے اور ابن تیمیہؒ نے ابن عربیؒ کو یہ کہا اور امام غزالی کو یہ کہا لیکن اگر ان کی ذاتی زندگی پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب اپنی ذاتی زندگی میں قرآن مجید سے جڑے ہوئے تھے اور ایک اعلیٰ درجے کی للہیت ‘ اخلاص اور تعلق مع اللہ رکھتے تھے۔
امام ابن تیمیہؒ اور تلاوت ِقرآن
امام ابن تیمیہؒ کی جب دمشق میں سجن/ جیل میں وفات ہوئی تو ان کے شاگرد ان کے ساتھ موجود تھے ۔ اس سے پہلے کئی کئی سال وہ قید ہوتے رہے لیکن آخری قید جس میں وفات ہوئی وہ چند مہینے کی تھی۔شاگرد فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ ؒ صرف قرآن کی تلاوت کرتے تھے ۔پہلے تو وہ قید میں تصنیف و تالیف بھی کرتے رہے تھے لیکن آخری قید میں صرف قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہی ان کی وفات ہوئی ۔وقت آخر یہ آیات زیر تلاوت تھیں:
{اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِیْ جَنّٰتٍ وَّنَـہَرٍ(۵۴) فِیْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیْکٍ مُّقْتَدِرٍ(۵۵)}
’’یقیناً متقین باغات اور نہروں (کے ماحول) میں ہوں گے۔ بہت اعلیٰ راستی کے مقام میں اُس بادشاہ کے پاس جو اقتدارِ مطلق کا مالک ہے۔‘‘
ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ اس مختصر عرصے میں صرف جیل میں۸۰ دفعہ قرآن پڑھ چکے تھے ‘یعنی پانچ سات مہینے کے دوران مستقل ان کا یہ معمول تھا۔اسی طرح امام غزالی ؒ کی کتاب’’ آداب تلاوت القرآن‘‘ دیکھیں تو وہ روزانہ پڑھنے کاجتنا نصاب بتاتے ہیں اس سے انسان پریشان ہو جائے گا۔ گویا سب ائمہ کے درمیان فکری‘تعبیراتی اور عقائد کی فروعات میں جوبھی اختلافات ہوں لیکن ذاتی زندگی میں وہ للہیت کا ایک نمونہ تھےاور تعلق بالقرآن رکھتے تھے۔
جدل و جدال سب گمراہی ہے
ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم جدال اور جدل کی دنیا میں مشغول ہو گئے ۔ فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا اور اس نے اس کے جواب میں یہ کہا ۔اس کو اختصار میں فنقلہ کی دنیا کہتے ہیں۔ جس طرح حمدلہ ہوتا ہے یعنی الحمدللہ کہنا ‘بسملہ (باسم اللّٰہ کہنا)ہے‘ حوقلہ (لا حول ولا قوۃکہنا) ہے‘ اسی طرح فنقلہ ہے: فان قالوا قلت قیل قال قالوا وغیرہ ۔ تو یہ فنقلہ (جدل) کی دنیا میں ہم بہت آگے ہوتے ہیں کہ اس کے جواب میں ہم نے یہ آیت quoteکی‘ اس کی فکر کا جواب یہ ہے ‘اس کا ردّ یہ ہے ‘ فلاں گمراہ ہو گیا اور فلاں حق پر ہےوغیرہ ۔یعنی جدال کی دنیا میں بہت زیادہ مگن ہیں۔ جو سچا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ‘ اللہ کے دین کے ساتھ ‘ اللہ کے کلام کے ساتھ اور اس کے رسولﷺ کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا‘ جس کی وجہ سے اس جدل اور جدال میں بھی بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ فکری یا کچھ دینی اختلاف سے ہماری چھلانگیں لگتی ہیں سیدھی شخصیات پر اور پھر ہم ان کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیتوں پر حملے کرتے ہیں ‘حکم علی الباطل بالباطل کا ارتکاب کرتے ہیں ۔ یہ سب باتیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ جدل کی دنیا تو بہت نمایاں ہے اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے دین کا دفاع کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے جو بنیادی اخلاقیات درکار ہوتی ہیں وہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتیں ۔اللہ کے نبی ﷺ نے اس بات کی طرف یوں اشارہ کیا :
((مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ ھُدًی کَانُوْا عَلَیْہِ اِلَّا اُوتُوا الْجَدَلَ)) (رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ)
یعنی کوئی قوم گمراہ نہیں ہوتی ہدایت کے بعد جس ہدایت پر وہ تھے مگر یہ کہ انہیں جدل دے دیا جاتا ہے کہ لڑو مرو ایک دوسرے سے ۔اگرچہ جدال کوئی ممنوع شے نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں کہا ہے : وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِیْ ھِیَ اَحْسَنُ ۔عربی زبان میں یہ حصر کا اسلوب ہے یعنی صرف اس طریقے پر جو احسن ہے۔ بِالَّتِیْ ھِیَ اَحْسَنُ میں گویا حسن کی بھی نفی ہے ۔ اگر جدال کرنا ہے تو احسن طریقے پر کرنا ہے‘اس کے بغیر جدال چھوڑ دو۔ احسن طریقے پر جدال اس وقت ہوتا ہے جب آپ واقعی دین سے سچا تعلق رکھتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو جدال کرتے تھے اور ہمیں خطرہ ہوتا تھا کہ دوسرے صاحب کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ جو ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے تھے کہ حق اس کے منہ پر ظاہر ہو اور ہم قبول کرلیں۔ یہ نہ ہو کہ حق ہمارے منہ پر ظاہر ہو اور اگلا بندہ اس حق کے انکار کی صورت میں کچھ ایسی بات کہہ دے جو کفر یا فسق یا بدعت تک پہنچا دے۔ بہرحال کلام اللہ محض ایک کلامی مبحث نہیں ہے بلکہ یہ زندہ کتاب ہے‘ جیسے اقبال نے کہا ؎
ایں کتابِ زندہ قرآنِ حکیم!
حکمت اُو لایزال است و قدیم
اس سے زندہ تعلق ہونا چاہیے ‘جومحض معنی سے نہیں ہوتا ۔ زندہ تعلق کے لیے لفظ سے تعلق جوڑنا پڑے گا۔ یہ پچھلی نشست کا خلاصہ تھا۔
لاعین و لا غیر کا مطلب
صفاتِ معنی سات ہیں‘جن میں سے آخری تین صفات رہ گئی ہیں ۔وہ تین صفات ہیں: صفت ِحیات ‘ صفت ِ سمع اور صفت ِبصر۔ صفات ِمعنی سے مراد صفات ِوجودیہ ہوتی ہیں یعنی ذات پر ایک صفت کا اضافہ ہوتا ہے جسے محض ذہنی اور اعتباری سمجھنا چاہیے‘ یہ اضافہ خارج میں نہیں ہوتا۔ ذہنی اور اعتباری طریقے پر یہ ذات سے الگ شے ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا عین نہیں ہے ۔خارج میں بس ذات ہی ہوتی ہے ‘اس کی صفات اس کا غیر نہیں ہوتیں تو اسی لیےہم کہتے ہیں کہ یہ غیر بھی نہیں ۔ لَا ھُوَ عَیْنٌ وَلَا ھُوَ غَیْرٌ۔ صفات کے بارے میں ایک توجیہہ یہ ہے کہ ذہنی اور فکری اعتبار سے اس میں تمایز ہے ‘فرق ہے ‘اختلاف ہے۔ خارجی اعتبار سے کسی قسم کا کوئی فرق واقع نہیں ہے۔ جتنی بھی ہم صفات پڑھ رہے ہیں یہ صفاتِ معنی ہیں۔ اس سے قبل ہم صفات ِسلبیہ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں کسی صفت ِوجودی کا اثبات مراد نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے نقائص کی نفی ہوتی ہے ۔اس سے قبل ہم نے ایک صفت ذاتیہ نفسیہ پڑھی جو صفت ِوجود ہے۔
صفت ِحیات
علماء نے کہا کہ یہ صفت ازلیہ ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ اس کی تعریف ہے :
صفۃ ازلیۃ وجودیۃ قائمۃ بذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ لا تتعلق بشیٔ
ابھی تک ہم نے جتنی صفات پڑھی ہیں وہ متعلق ہوتی ہیں ‘ جیسے ہم نے ارادہ پڑھا تو اللہ کا ارادہ ممکنات سے متعلق ہوتا ہے ۔ ہم نے علم کے بارے میں پڑھا کہ یہ ممکنات سے‘ واجبات سے‘ مستحیلات سے متعلق ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر ہم نے اللہ کی قدرت کے بارے میں پڑھا کہ یہ ممکنات سے متعلق ہوتی ہیں۔ لیکن یہ صفت خارج میں کسی سے متعلق نہیں ہوتی‘ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی صفت ِحیات خارج میں متعلق ہو کر ہمیں حیات ملتی ہے۔ نہیں‘ اللہ کی صفت ِحیات خارج میں تو کہیں نہیں پائی جاتی ۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کسی مخلوق میں نہیں ہوتی۔ ہاں صفت ِ قدرت مخلوق سے اس لیے متعلق ہوتی ہے کہ صفت ِقدرت سے مخلوق وجود میں آتی ہے ۔ اس کا وجود میں آنا صفت ِ قدرت سے ہوتا ہے لیکن صفت ِحیات بھی اسے صفت ِقدرت سے حاصل ہوگی۔ یعنی انسان کو جو حیات حاصل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ِقدرت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ صفت کسی ممکن سے یا خارج میں متعلق نہیں ہوتی بلکہ یہ اللہ کی ازلی صفت ہے ‘سابقہ ہے ‘وجودیہ ہے ۔اس سے کیا ہوتا ہے پھر ؟کہتے ہیں: تقتضی صحۃ العلم یعنی اس کی وجہ سے جو علم والی صفات ہیں وہ صحیح قرار پائیں گی ۔ یعنی جس ہستی میں بھی علم اور ادراک کی صفت ہوگی وہ لازماً حیات رکھتی ہوگی ‘اس لیے کہ علم اور ادراک کی سمجھ صفت ِحیات کے بغیر نہیں آ سکتی ۔گویا یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا صفت ِعلم اور صفت ِسمع اور صفت ِبصر سے متصف ہونا سمجھ میں آتا ہے ۔صفت ِحیات کیا ہے: صفۃ ازلیۃ ثابتۃ قدیمۃ لذات اللّٰہ سبحانہ و تعالیٰ لا تتعلق بشی۔ یہ کسی شے سے متعلق نہیں ہے: تقتضی صحۃ العلم صحت ِعلم کی مقتضی ہے اور گویا صفت ِعلم اس کا مقتضا ہے۔
صفت ِحیات عقلی صفت ہے
صفت ِحیات کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ عقلی صفت ہے ‘یعنی صرف نقل سے ثابت نہیں ہے بلکہ عقل سے بھی ثابت ہے ۔اس لیے کہ علم اور ادراک کی صفت یا قدرت اور ارادے کی صفت اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آسکتیں۔ گویا صفت ِحیات اس کے لیے ایک شرط ہوئی ۔صفت ِحیات باقی تمام صفات ِمعنی کے لیے شرط کی حیثیت رکھتی ہے ۔اگر یہ شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ آپ یوں کہیں گے کہ صفت ِحیات خود صفت ِعلم نہیں ہے ‘صفت ِحیات خود صفت ِسمع وبصر نہیں ہے بلکہ ان سے خارج ایک الگ صفت ہے لیکن یہ صفات اس کے بغیر پائی نہیں جا سکتی ہیں۔ یہ شرط اور مشروط کا جو تعلق ہے یہاں یہ اصولِ فقہ والا نہیں ہے۔ یعنی جب علم کلام میں آپ بول رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ یہاں بھی سبب اور شرط میں اس طرح فرق کریں کیونکہ یہ اس وقت کلام کی بحث ہے ‘جس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ صفت اس کے بغیر نہیں پائی جائے گی۔ یعنی صفت ِعلم صفت ِحیات کے بغیر نہیں پائی جا سکتی ۔ آپ کہیں ایک شے میت ہے لیکن عالم ہے ‘فاضل ہے ‘ صاحب قدرت ہے ‘ صاحب ارادہ ہے ‘سمیع ہے ‘بصیر ہے ‘علیم ہے ‘لیکن حی نہیں ہے‘ تو یہ بات عقل تسلیم نہیں کرے گی۔ لہٰذا یہ صفت ِعقلی ہے اور شرط ہے باقی تمام صفات ِمعنی کے لیے۔ باقی قرآن مجید میں اس کا اثبات ہے اور بعض بزرگوں کی رائے میں الحیّ اور القیُّوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں یا اسمائے عظمیٰ میں سے ہیں۔ آیت الکرسی : اَللہُ لَآ اِلٰــہَ اِلَّا ہُوَج اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ج اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحی ہے‘ القیوم ہے ۔ پھر حیات اور قیومیت میں جو نقص وارد ہو سکتا ہے اس کی نفی کر دی کہ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَـۃٌ وَّلَا نَوْمٌ ط ۔گویا اونگھ آ جانا ‘نیند کا آ جانا یہ سب حیات میں نقص کی علامات ہیں ۔ ان تمام علاماتِ نقائص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات منزہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ ہی کو محض حی کہا گیاہے ۔ سورۃ المؤمن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بہت سی نعمتیں گنواتے ہیں‘اس کے بعد فرماتے ہیں:
{فَتَبٰـرَکَ اللہُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ(۶۴) ہُوَ الْحَیُّ لَآ اِلٰــہَ اِلَّا ہُوَ فَادْعُوْہُ مُخْلِصِیْنَ لَہُ الدِّیْنَ ط }
’’تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے ‘اُس کے سوا کوئی معبود نہیں ‘پس اُسی کو پکارو اُس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔‘‘یہاں ھُوَ الْحَیُّ بھی حصر کا صیغہ ہے۔
توکّل اور صفت ِحیات کی باہمی نسبت
پھر توکل کو کئی جگہوں پر حیات کے ساتھ جوڑا گیا ہے:
{وَتَوَکَّلْ عَلَی الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَمُوْتُ }
یعنی توکل کرو اُس حی پر جس پر موت نہیں آتی۔ اس میں بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر وہ ہستی کہ جو قابلِ فنا ہے ‘قابلِ زوال ہے ‘جو ختم ہو جائے گی وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس پر تکیہ رکھیں ‘اس پر بھروسا کریں‘ اس پر توکّل کریں ۔ توکّل کے لیے جو صفت اپنے متوکّل علیہ میں چاہیے وہ بھی صفت ِحیات ہے جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو۔ یہ تین سورتیں ہیں جو ایک ترتیب کے ساتھ آئی ہیں :سورۃ الفرقا ن ‘ سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل ۔ ان تینوں سورتوں کے آخر میں واحد کے صیغے میں اللہ کے نبی ﷺ کو توکّل کا حکم دیا جاتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں آیا:
{وَتَوَکَّلْ عَلَی الْحَیِّ الَّذِیْ لَا یَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِہٖ ط وَکَفٰی بِہٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِہٖ خَبِیْرَا(۵۸) }
’’اور آپؐ توکّل کیے رکھئے اُس زندئہ جاوید ہستی پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی‘ اور اُ س کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے۔اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔‘‘
اس کے بعد سورۃ الشعراء کے آخر میں آیا:
{ وَتَوَکَّلْ عَلَی الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ(۲۱۷) الَّذِیْ یَرٰىکَ حِیْنَ تَقُوْمُ(۲۱۸) وَتَقَـلُّبَکَ فِی السّٰجِدِیْنَ(۲۱۹) اِنَّہٗ ہُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ(۲۲۰) }
’’اور (اے نبیﷺ!) آپ بھروسا کیجیے اُس(اللہ) پر جو بہت زبردست‘ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔اور (وہ دیکھتا ہے) آپ کے آنے جانے کو سجدہ کرنے والوں میں۔یقیناً وہ سب کچھ سننے والا ‘سب کچھ جاننے والا ہے۔‘‘
تو وہاں بھی توکّل کو دو اور صفات سے جوڑا۔ توکّل کیجیے اس ہستی پر جو غالب ہے اور رحمت والی ہے جو آپ کو دیکھتی ہے جب آپ سجدہ کرنے والوں کے درمیان رات میں چکر لگاتے ہیں۔ سورۃ النمل میں ہے:
{فَتَوَکَّلْ عَلَی اللہِ ط اِنَّکَ عَلَی الْحَقِّ الْمُبِیْنِ(۷۹) }
’’تو (اے نبیﷺ!) آپ توکّل کیجیے اللہ پر۔ یقیناً آپؐ ہی واضح حق پر ہیں۔‘‘
اس میں لفظ جلالہ(اللہ) آ گیا جو تمام صفات کا جامع ہے ۔تو ان تین سورتوں میں ایک خوبصورت سا ربط ہے۔ تینوں ایک ساتھ ہیں اور تینوں ہی کے آخر میں اختتام سے تقریباً ایک جیسے فاصلے پر ایک آیت آتی ہے جس میں توکّل کا حکم ہے۔ تینوں سورتوں میں توکّل کے بارے میں اللہ کے نبیﷺ کو واحد کے صیغے میں خطاب ہے۔ بہرحال صفت ِحیات میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ خارج میں کسی شے سے متعلق نہیں ہوتی۔ گویا اللہ کی صفت ِحیات کسی کو حاصل نہیں ہوئی ۔ ہم زندہ ہیں ‘اور بھی بہت سی چیزیں زندہ ہیں اور ہماری زندگی بہت ناقص ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ آخرت کی زندگی جو اللہ کی حیات کے مقابلے میں ناقص ہی ہوگی‘ اس کو فرمایا کہ بس وہی زندگی ہے لیکن اِس کو توزندگی ہی نہیں کہا ۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :
{وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَۃَ لَہِیَ الْحَیَوَانُ } (العنکبوت:۶۴)
’’اور آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے۔ ‘‘
حیوان بس وہی ہے۔ یہاں حیوان مصدر ہے حیات کا‘ یعنی حَیِیَ یَحْیٰی کا مصدر ہے۔
صفت ِسمع و بصر
ان دو صفات کے بارے میں علماء میں ایک اختلاف ہوا کہ یہ صفات ِعقلیہ ہیں یا صفات ِسمعیہ ! ابھی تک ہم جتنی بھی صفات پڑھ رہے تھے وہ عقلی تھیں ۔عقلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سماع سے ثابت نہیں ہیں۔ سماع سے تو ثابت ہیں لیکن متکلمین کا منہج تھا کہ وہ ہر اس شے کو عقل کے ذریعے ثابت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جس پر نبی کی نبوت کا دارومدار ہے ‘تاکہ circular reasoning (دور)لازم نہ آ جائے۔ اگر ہم نبی کے قول سے خدا کا اثبات کریں تو پہلے خدا کا اثبات ہوگا تونبی کا نبی ہونا ثابت ہوگا ۔اس لیے وہ کہتے ہیں پہلے ہم خدا کا خدا ہونا ثابت کریں گے اور وہ محض عقلی دلائل سے کریں گے ‘ اس کے بعد نبوت کا اثبات کریں گے اور پھر جب نبی کا اثبات ہو جائے گا تو اب نبی جو خدا کے بارے میں بتائیں گے وہ ہم من و عن تسلیم کر لیں گے۔ یہ ایک مکمل منہج ہے ۔انہوں نے کہا کہ : یہ جو صفت ِسمع و بصر ہے یہ اس معنی میں عقلی ہے یا سمعی؟
صفات ِسمع و بصر سمعی ہیں
اکثر علماء اور متکلمین کی رائے ہے کہ یہ صفاتِ سمعیہ ہیں ‘عقلیہ نہیں ۔مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے صفت ِعلم کے بارے میں دیکھا کہ اس سے ہر شے منکشف ہو جاتی ہے انکشاف ِتام کے ساتھ ‘اس میں کسی قسم کا کوئی غموض ‘ ابہام اور پوشیدگی باقی نہیں رہتی تو پھر مزید عقلی طور پر صفت ِسمع و بصر کی بھی کوئی حاجت نہیں رہتی‘ کیونکہ صفت ِعلم یہ کام کر ہی رہی ہے۔ البتہ چونکہ شریعت نے علم کے ساتھ صفت سمع و بصر کا بھی اثبات کیا ہے لہٰذا ہم صفت ِسمع و بصر کا اثبات کریں گے اور یہ مانیں گے کہ اس سے ایک نوع کا ادراک حاصل ہوتا ہے جو غالباً صفت ِعلم سے نہیں ہو رہا ۔ یہ بات متکلمین نے مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ صفت ِسمع وبصر سے ایک نوع کا ادراک ہو رہا ہے جو صفت ِعلم سے نہیں ہو رہاتو گویا ماننا پڑے گاکہ صفت ِعلم سے وہ ادراک نہیں ہوا تھاجواس سے ہو رہا ہے ۔پھر آپ نے ساتھ یہ بھی بتایا تھاکہ صفت ِعلم سے انکشافِ تام ہوجاتا ہے۔ اگر انکشافِ تام ہوگیا توہرنوع کا ادراک ہوگیا۔ اگر ہرنوع کا ادراک ہوگیا تویقیناً وہ ادراک بھی ہو گیا جو صفت ِسمع و بصر سے ہوا۔پھر ان کی حاجت ہی کیا رہی؟ اصلاً اس کا جواب یہی ہے جیسے امام رازی اور بہت سے بزرگوں نے کہا کہ ہم نے اس کا اثبات شرع کی وجہ سے کیا ہے ‘یعنی نقل کی وجہ سے ‘وحی کی وجہ سے ‘کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ میں سمیع اوربصیر ہوں اور ساتھ اپنے آپ کو علیم بھی کہا ہے تو یقیناً ان الفاظ میں ترادف نہیں ہے بلکہ کچھ نوع کا اختلاف ہے چاہے وہ اختلاف ہمارے فہم میں نہ آئے۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا تو ہم بھی صفت سمع و بصر کا اثبات کریں گے۔
جن علماء نے کہا کہ یہ عقلی بھی ہو سکتی ہے ‘ اس پر اگرچہ اعتراض بہت سے بنتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ غور کریں تو یہ صفاتِ سمع و بصر صفاتِ کمال ہیں کہ نہیں؟ امام غزالی علیہ الرحمہ نے جس طریقے پر صفت ِکلام کو ثابت کیا تھا کہ کمال ہے اور کمال محض ہے اسی طریقے پر انہوں نے کہا کہ بھئی ان صفات میں بھی کمال تو ہے‘ ہاں اس میں کچھ نقص بھی ہے۔ وہ نقص ہم منزہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ نقص ہے آلہ کا ہونا یعنی کسی واسطے سے دیکھنا۔ وہ واسطہ ہماری آنکھ ہے۔ پھر خاص کنڈیشنز میں دیکھنا ‘خاص شرائط کا پایا جانا یہ سب انسانی نقص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ماوراء ہے۔ اللہ ہر شے کو دیکھتے ہیں ‘جس کے لیے نہ جہت میں ہونا ضروری ہے ‘نہ روشنی کی ضرورت ہے‘ نہ حدقہ یعنی آلے کی ضرورت ہے ۔ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ماوراءہیں لیکن محض دیکھنا تو صفت ِکمال ہے۔ اسی طرح محض سماعت تو صفت ِکمال ہے اور اللہ تعالیٰ تمام آلائشوں سے جو انسان کے ساتھ لگی ہیں‘ ان سے منزہ ہیں۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عقلی طور پہ بھی ان صفات کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے ان کے جواب میں کہا کہ نہیں ‘دیکھو یہ تو تمہیں پتہ چل گیا ہے نا کہ نقل میں سمع و بصر کا اثبات کیا گیا ہے تو اب تمہیں عقلی طور پر بھی چیزیں سمجھ میں آرہی ہیں ۔اگر بالفرض نقل میں اثبات نہ کیا گیا ہوتا تو پھر صفت ِعلم ہی کافی ہو جاتی‘ کسی کو کوئی ضرورت پیش نہ آتی کہ وہ صفت ِسمع وبصر کا اثبات کرے۔واللہ اعلم !
متکلمین پر ایک بے بنیاد اعتراض
یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ متکلمین پر جو یہ اعتراض ہے کہ یہ نقل کو اور وحی کو اہمیت ہی نہیں دیتے‘ بالکل باطل ہے۔ نعوذ باللہ ‘ایسا ہو نہیں سکتا اور یہ بہت ہی بچگانہ قسم کے کچھ اعتراضات ہیں۔ پورا علم کلام کھڑا ہی اس پر ہے کہ شبہات کا رد کیا جائے اور عقائد دینیہ کا اثبات کیا جائے۔ جیسے آج کل فقہ پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ مثلاًیہ کہ ایک قرآن و حدیث ہوتی ہےاور ایک فقہ ابو حنیفہ ہوتی ہے۔ فقہ ابو حنیفہ یا فقہ شافعی کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ قرآن و حدیث تو اور شےہے اور یہ فقہیں شاید بائبل یا گیتا یا وید ہوں گی! یہ عجیب سی باتیں آج کل سننے کو مل رہی ہیں‘ حالانکہ پہلے یہ کسی کے دماغ میں بھی وارد نہیں ہوتی تھیں۔ کسی نے کبھی بھی یہ دوئی نہیں بنائی کہ ایک طرف فقہ ہوتی ہے اور ایک طرف قرآن و حدیث ہوتاہے جبکہ فقہ کوئی اورشے ہے جو کہیں سے آگئی ہے ۔یہ اعتراض فی زمانہ ہوگیا۔ اسی طرح فی زمانہ یہ بھی ہوگیاکہ علم الکلام کادین اور عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے اور متکلمین تو فلسفیانہ اور منطقیانہ بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دین تو بڑا سادہ سا تھا ‘انہوں نے اس کو کافی الجھادیا ۔ یہ ایک بے بنیاد بات ہے کیونکہ علم الکلام کا دین ہی سے تعلق ہے‘ وہ دین ہی کا بیان ہے۔ اگر آپ صرف ’’المستصفٰی‘‘ میں امام غزالی علیہ الرحمہ کامقدمہ پڑھیں جو علوم پر ہے تو بہت مفید ہو گا۔ اس سے علوم کے مراتب کا پتہ چلتا ہے کہ ایک علم کا دوسرے سے تعلق کیا ہے۔ پورا خریطہ سمجھ آ جاتا ہے کہ علوم کا نقشہ کیا ہے اور اس نقشے میں کون سا علم کس جگہ پر ہوتا ہے ۔ اس کا اپنے ساتھ والے علم سے اور اوپر والے سے اور نیچے والے سے ربط کیا ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں ۔
علم الکلام / عقیدہ اصل العلوم ہے
جب انہوں نے وہ خریطہ بیان کیا تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ سب سے اوپر علم یعنی اس اعتبار سے کہ تمام علوم اس سے مستمد ہوتے ہیں اور وہ کسی سے مستمد نہیں ہے یا اس کا مستمد کوئی نہیں ہے‘ وہ علم کلام ہے۔ مثال کے طور پرآپ اصولِ فقہ میں حکم شرعی کی تعریف بتانے جا رہے ہیں: خطاب اللّٰہ المتعلق! خطاب اللہ کے لفظ میں آپ یہ بات پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے ‘خطاب فرماتے ہیں تو یہ خود اصولِ فقہ سے ثابت نہیں ہو رہا ہوتا۔اس کے لیے اصولِ فقہ کے پاس علم کلام کی بنیاد ہے کہ علم الکلام میں ‘علم عقیدہ میں‘ علم اصولِ دین میں اللہ کا متکلم ہونا ثابت ہو چکا ہے ۔ اب ہمیں یہ بحث یہاں نہیں کرنی ۔چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہر علم استمداد کر رہا ہوتا ہے اصول الدین سے ۔ کسی زمانے میں دیکھنے کی ایک نظر یہ تھی اور ایک نظر اب پیدا ہوئی ہے جس میں قرآن و حدیث کے نام پر تمام روایتی علوم سے پیچھا چھڑانے کی کوشش ہے ۔ پھر نتیجتاًان لوگوں کا قرآن و حدیث کا ایسا فہم ہوگا کہ جس کے درمیان ۱۳۰۰ سال کا خلا واقع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک پوری تاریخ غائب ہو جاتی ہے‘ پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث سے جڑے ہوئے ہیں۔
ایک بحث امام غزالیؒ نے ’’المقصد الاسنٰی‘‘ میں فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا ہم اپنی صفات کی گہری انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتے ہیں اتنی ہی خدا کی صفات کی گہری انڈرسٹینڈنگ حاصل ہوتی ہے۔ باقی خدا کی صفت کی حقیقت تو کسی کو نہیں معلوم ہو رہی ہوتی ۔البتہ آپ ارادے کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے ارادے پر زیادہ سے زیادہ غور کریں گے اور کچھ باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی تو باقی تمام نقائص کو نکال کر کسی نوع کی مشابہت آپ ثابت کریں گے ۔ فرماتے ہیں کہ حقیقتاً اللہ کو خود اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور ہم اللہ کو جتنا بھی جانتے ہیں وہ صفات کے نتائج کے اعتبار سے جانتے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اگر صفت ِقدرت کے نتائج زیادہ دیکھنا شروع کردیں یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مشاہدے ہو رہے ہیں اور پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح افعال صادر فرما رہے ہیں ‘ بہت سی چیزیں ملکوت کی نظر آرہی ہیں تو پھر آپ کو یقیناً گہرا فہم حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کےتعلق پر مبنی ہے۔ آپ کوجو درسی تعریف حاصل ہوگی وہ سب برابر ہیں۔ صفات معنی میں ایک ہی تعریف چل رہی ہے لیکن ان میں گہرائی اللہ تعالیٰ سے تعلق کے نتیجے میں حاصل ہوگی۔ کلام اللہ سے گہرا تعلق بھی متکلم سے گہرے تعلق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اصلاً چیزیں درسی اعتبار سے نہیں کھلیں گی کہ آپ علم الکلام کی کتابوں پر کتابیں پڑھتے چلے جائیں۔ نہیں!اس سے کچھ بنیادی چیزیں اور کچھ مباحث زیادہ پتہ چل جائیں گے لیکن معرفت اس وقت ہوگی جب آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں سفر شروع کر دیں گے۔ وہ معرفت بھی ہمیشہ اپنے تمام مراحل میں ناقص رہے گی ‘کامل نہیں ہوگی۔
صفت ِسمع وبصر کی تعریف
اس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا۔ امام ابو الحسن الاشعریؒ اور متکلمین ایک طرف ہیں جبکہ امام سعد الدین التفتازانی جن کی شرح مقاصد اور شرح العقائد کتابیں ہیں‘دوسری جانب ہیں۔وہ اختلاف میں بتا دیتا ہوں۔ صفت سمع کیا ہے:
صفۃ ازلیۃ ثبوتیۃ قائمۃ بذات اللّٰہ تعالیٰ تتعلق بجمیع الموجودات
یہ جمہور کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ِازلی جو ثابت ہے اور متعلق ہے تمام موجودات سے۔ اس حوالے سے امام سعد الدین تفتازانیؒ فرماتے ہیں: تتعلق بالمسموعات صرف مسموعات سے متعلق ہے۔ صفت ِسمع کی بات ہو رہی ہے اور منطقی طو رپر بھی یہ بات سمجھ میں آرہی ہے لیکن جمہور علماء نے کہا کہ نہیں ‘ہماری بات میں زیادہ logicہے۔ یعنی صفت ِسمع ان چیزوں سے متعلق ہوگی جن کو سنا جاتا ہے‘ یہ سعد الدین تفتازانی ؒکہہ رہے ہیں۔ جمہور متکلمین بشمول ابو الحسن الاشعری ؒ فرما رہے ہیں : تتعلق بجمیع الموجودات! یعنی صفت ِ سمع کا صرف مسموعات سے نہیں بلکہ تمام موجودات سے تعلق ہے۔وہ کیسے ؟کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ صرف آواز نہیں سنتےبلکہ ہر شے جس کو ہم آواز نہیں بھی کہتے وہ بھی اللہ کے حق میں مسموع ہوتی ہےاور اللہ اسے سنتا ہے ۔ہو سکتا ہے جدید سائنس ہمیں بتائےکہ اس میں سے بھی آواز کی کچھ wavesنکل رہی ہیں اور جمہور متکلمین کے مذہب کے حق میں بات جا رہی ہو۔ ٭
( ٭ جا رجو اگیمبن ایک بہت مشہور اطالوی مفکرہے۔ اس کا ایک ٹویٹ ہے‘ جو اُس نے ۳۰ اکتوبر۲۰۲۳ء کوکیا۔ یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں:
" Scientists from the School of Plant Sciences at the University of Tel Aviv announce in the last few days that they had recorded with the help of special ultra --- sound micro phones, the screams of pain that plants make when they are cut or lack of water. "
’’تل ابیب یونیورسٹی کے اسکول آف پلانٹ سائنسز کے سائنس دانوں نے گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا کہ انہوں نے خصوصی الٹرا ساؤنڈ مائیکرو فونز کی مدد سے اس درد کی چیخوں کو ریکارڈ کیا ہے جو پودے کے کٹ جانے یا پانی کی کمی سے پیدا ہوتی ہیں۔‘‘
اُس کے بعد کہتے ہیں: There are no micro phones in Gaza یعنی ’’غزہ میں کوئی مائیکرو فون نہیں ہیں!‘‘ یہ ہے تہذیب جو پیدا کی گئی ہے‘ یعنی وہ طاقت پیدا کر لی کہ پلانٹس کی سسکیاں سنی جا سکیں۔)
فی الحال یہ گلاس پڑا ہوا ہے ‘اگر اس میں سے کوئی آواز پیدا نہیں ہو رہی تو میری صفت ِسمع اسے کیچ نہیں کر سکے گی۔ میرے لیے یہ مسموع صرف تب ہوگا جب اس میں آواز پیدا ہو گی۔ یہ امام سعد الدین تفتازانی علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں۔ جمہور متکلمین کہتے ہیں نہیں ‘یہ بھی اصلاً قیاس الغائب علی الشاہد کی ایک قسم ہے جس میں امام سعد الدین تفتازانی کو غلطی لگ گئی کہ انہوں نے سمجھا کہ جس طرح ہم بھی مسموع شے کو جب تک اس میں سے آواز پیدا نہ ہو نہیں سن سکتے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں سن سکتے۔ ایسے نہیں ہے ‘بلکہ اللہ ہر موجود شے کو سنتا ہے۔
جمہور علماء کے ہاں صفاتِ سمع و بصر تمام موجودات سے متعلق ہیں
یہی بات آپ صفت ِبصر میں بھی سمجھ لیں۔ صفت ِبصر میں امام سعد الدین تفتا زانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مبصرات کو دیکھتا ہے۔ یعنی جو دکھائی دینے والی چیزیں ہیں ان کو دیکھتا ہے۔ جمہور نے کہا کہ نہیں‘ تمام موجودات کو دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے لیےکوئی شے مبصر نہیں ہوتی مگر خاص خاص ماحول میں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے لیکن شاید دیکھتا نہیں۔ جمہور کہتے ہیں کہ اللہ ہر شے کو جانتا ہے ‘ہر شے کو سنتا ہے ‘ہر شے کو دیکھتا ہے۔ اس کی صفت ِسمعی بھی متعلق ہے تمام موجودات سے ‘جس کی دلیل قَدْ سَمِعَ اللہُ قَوْلَ الَّتِیْ تُجَادِلُکَ فِیْ زَوْجِہَا کی آیت ہے۔جب ظہار کا معاملہ ہو گیا تو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی ﷺ کے پاس آئیں۔ وہ شکایت کر رہی تھیں اور چپکے چپکے بول رہی تھیں‘ یعنی حجرے میں تھیں لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی آواز نہیں آرہی تھی اور شکوہ کر رہی تھیں کہ یہ کیا ہوا اور انہوں نے مجھ سے ظہار کر لیا۔ اللہ کے نبی ﷺکہہ رہے تھے کہ تم ان پر حرام ہو گئی ہو اور وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے‘ایسا نہیں ہونا چاہیے ‘ وَتَشْتَـکِیْٓ اِلَی اللہِ وہ اللہ سے شکوہ کررہی تھیں۔ انہوں نے اپنی دردناک کہانی بھی سنائی کہ اکل شبابی میری جوانی اس نے کھا لی، ونصرت لہ بطنی میں نے اس کے لیے حمل اٹھایا‘ بچے پیدا کیے‘ اب جب میں بوڑھی ہو گئی تومجھ سے ظہار کر لیا۔ اس پر جب آیات نازل ہو گئیں کہ:
قَدْ سَمِعَ اللہُ قَوْلَ الَّتِیْ تُجَادِلُکَ فِیْ زَوْجِہَا وَتَشْتَـکِیْٓ اِلَی اللہِ ق وَاللہُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَکُمَاط اِنَّ اللہَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ (۱)
’’اللہ نے سن لی اُس عورت کی بات (جو اے نبیﷺ!) آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں اور وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے۔ اور اللہ سن رہا ہے آپ دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا‘ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔‘‘
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ حدیث نقل کی اور اس کے شروع میں الفاظ بیان کیے :الحمدللّٰہ الذی وسع سمعہ کل شیٔ! ’’تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی سماعت نے ہر شے کو گھیر لیا۔‘‘ تو اس میں بھی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ واللہ اعلم!
اسی طرح {اِنَّ اللہَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ(۲۸) } (لقمان)اور {اِنَّہٗ بِکُلِّ شَیْ ئٍ بَصِیْرٌ(۱۹)}(الملک) جیسی آیات بھی قرآن میں کثرت سے واقع ہوئی ہیں‘ تو انہوں نے کہا کہ صفت سمع و بصر تتعلق بکل الموجوداتہے ‘ صرف مسموعات اور مبصرات سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ واقعی بات ایسی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو سنتے ہیں۔ {اِنَّہٗ سَمِیْعٌ قَرِیْبٌ(۵۰) }(سبا) یقیناًاللہ تعالیٰ ہر شے کے قریب ہے اور سن رہا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے۔
صفت ِسمع و بصر کا نتیجہ :مراقبہ
بعض علماء نے کہا کہ صفت ِسمع و بصر سے جو شے پیدا ہونی چاہیے وہ مراقبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ‘اس کی رقابت میں اور اس کی نگرانی میں ہر وقت ہونے کا احساس۔ سورۃ القیامہ کی آیت ہے:
{ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰی نَفْسِہٖ بَصِیْرَۃٌ(۱۴) وَّلَوْ اَلْقٰی مَعَاذِیْرَہٗ (۱۵) }
’’ بلکہ انسان تو اپنے نفس کے احوال پر خود ہی خوب بصیرت رکھتا ہے‘اور چاہے وہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔‘‘
اس کی ایک شرح یہ بھی کی گئی ہے کہ انسان کو ایک نگاہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰی نَفْسِہٖ بَصِیْرَۃٌ(۱۴) یعنی انسان کو ہر وقت ایک نگاہ دیکھ رہی ہے ۔ایک تو اس کا ترجمہ واضح ہے کہ ہر انسان اپنے اوپر ایک نگاہ رکھتا ہے‘ بصیرت رکھتا ہے۔ وَّلَوْ اَلْقٰی مَعَاذِیْرَہٗ چاہے وہ کتنے ہی عذر پیش کر دے۔ دوسری تفسیر بھی ثابت ہے صحابہؓ سے کہ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰی نَفْسِہٖ بلکہ انسان کے اوپر ایک بصیرۃ ہے‘ایک دیکھتی ہوئی آنکھ جو اسے ہر وقت دیکھ رہی ہے۔وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے۔ وَّلَوْ اَلْقٰی مَعَاذِیْرَہٗ چاہے وہ کتنے ہی پردے کیوں نہ لٹکا لے۔ مَعَاذِیر‘مَعْذِرَۃ کی جمع بھی ہے جو معذرت ہوتی ہے اور مِعْزَار کی جمع بھی ہے جو پردے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ ترجمہ یہ بنے گا کہ ایک نگاہ انسان کو دیکھ رہی ہوتی ہے چاہے وہ کتنے ہی پردے کیوں نہ لٹکا لے ۔ یہ جوکیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللّٰہ سامعی‘ اللّْٰہ ناظری کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ‘سن رہا ہے تو اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللہَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سماعت ‘ بصارت اور رقابت کو پیش نظر رکھا جائے اپنے ہر عمل میں ‘ اپنے تمام خواطر میں‘ اپنے احساسات اور خواطر قلبیہ میں۔ یہ صفت ِسماعت و بصارت کا اثر ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ صفت ِسمع تھی اور یہ تتعلق بجمیع الموجودات ہے ۔ اسی طرح صفت ِبصر کی تعریف ہے :
صفۃ ازلیۃ ثابتۃ لذات اللّٰہ سبحانہ وتعالیٰ تتعلق بجمیع الموجودات!
چنانچہ صفاتِ سمع و بصر بھی تمام موجودات سے متعلق ہیں۔
موجودات سے مراد
لفظ موجودات سے کیا مراد ہے ؟ معلومات تو اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کی بھی ہے جو مستحیل ہیں‘یا جو ابھی موجود نہیں ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم تو متعلق ہے بکل الممکنات،بکل الواجبات وبکل الجائزات! یہاں جب کل الموجودات کہا تو اس میں سے ایک معدوم کو نکالا‘ یعنی معدوم اللہ کے علم میں ہے لیکن چونکہ خارج میں موجود نہیں ہے اس لیے یہ صفت اس سے متعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مستحیل اشیاء تو خارج میں موجود بھی نہیں ہو سکتیں لیکن اللہ ان سب کو جانتا ہے ۔یہ ایک فرق کیا گیا صفت ِعلم اور صفت سماعت و بصارت میں کہ صفت ِعلم تو تمام چیزوں سے متعلق ہے جبکہ صفت ِبصر تمام چیزوں سے متعلق نہیں بلکہ جو چیزیں موجود ہو جاتی ہیں‘ صرف ان سے متعلق ہے۔ اس میں ساری ممکنات شامل نہیں بلکہ صرف وہ جوموجود ہیں اور واجبات بھی‘ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارکہ ‘تو اللہ تعالیٰ اپنی ذاتِ مبارکہ کو سنتا ہے اور دیکھتا ہے ۔موجودات میں جو سب سے بڑھ کر موجود ہے وہ واجب الوجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ِسمع و بصر بھی ان سے متعلق ہے ‘یعنی اللہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ یہ درست ہے اور علماء نے ایسے ہی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں‘ کیونکہ کوئی موجود اس سے اوجھل نہیں ہے۔ صفت ِعلم اس سے بہت زیادہ وسیع معنی میں ہے ۔ جن لوگوں نے کہا کہ یہ صفاتِ سمع و بصر عقلی نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ ہیں تو بہت وسیع لیکن بالآخر وہ بھی صفت ِعلم کا ایک جزو بنیں گی۔ یعنی یہ صفات صفت ِعلم کے بہت سے پہلوئوں میں سے ایک پہلو میں شمار ہوں گی۔ اگرچہ ان صفات کے تعلقات میں تخصیص ہو جائے گی اور وہ صفت ِعلم کی طرح تمام واجبات‘ جائزات اورمستحیلات سے متعلق ہونے کی بجائے صرف موجودات سے متعلق ہوں گی۔ واللہ اعلم!
سات صفات جن کو ہم صفات ِمعنی کہتے ہیں‘ اس میں ماتریدیہ نے ایک صفت ِتکوین کااضافہ کیا ہے۔چنانچہ صفت ِتکوین آٹھویں صفت کے طور پہ بیان کر دی جاتی ہے۔ کچھ اس میں مزید اضافہ کرتے ہیں‘ گویااپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں اگر تم نے صفت ِعلم کوصفت ِسمع و بصر سے الگ کیا تو ہم صفت ِادراک کو بھی لے آتے ہیں‘ کیونکہ ادراک بھی تو ایک نوع کی فرق شےہے۔لہٰذا وہ صفت ِادراک کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تاہم عمومی طور پرسات ہیں یا آٹھ ہیں۔ سات اشاعرہ کے ہاں اور آٹھ ماتریدیہ کے ہاں۔
صفت ِتکوین
آٹھویں صفت ’’تکوین ‘‘ہے ‘جس کو صفت ِافعال بھی کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے افعال حادث ہوتے ہیں لیکن صفت ِتکوین ان کے ہاں حادث نہیں بلکہ صفت ِقدیمہ ہے جس کے ذریعے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہوا؟ اشاعرہ نے کہا کہ صفت ِقدرت کافی ہے بس افعال کو سرزد کرنے کے لیے ‘یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس صفتِ قدرت ہے اور اس سے تعلق کی وجہ سے چیزیں وجود میں آتی چلی جاتی ہیں۔ صفت ِقدرت ہی سے صفت ِفعل برآمد ہوتا ہے۔ ماتریدی حضرات نے کہاکہ صفت ِقدرت بالکل اپنی جگہ پر ہے جبکہ قدرت ہونا اور ہے اور کسی شے کا بالفعل ہو جانا اور ہے ‘تو انہوں نے بالفعل والے کام کو صفت ِتکوین سے تعبیر کیا۔ جن لوگوں نے اس موضوع اختلاف پر کتابیں لکھی ہیں جیسے ابن کمال الباشا علیہ الرحمہ جو امام سیوطی کے ہم عصر تھے‘ ان کی کتاب ہے: مسائل الاختلاف بین الاشاعرۃ و ماتریدیۃ! انہوں نے فرمایا کہ صفت ِتکوین میں یہ اختلاف لفظی ہے‘ معنوی نہیں‘ یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بس انہوں نے ایک صفت ِتکوین کا اضافہ کیا ہے اور اس سے کسی قسم کے معنی میں کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا۔ یہ اختلاف ِلفظی شمار ہوگا ‘اختلاف ِمعنوی شمار نہیں ہوگا۔
بہرحال صفات کی بحث اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل ہو گئی ہے۔ ہماری جو ترتیب ہے عقیدے کی اس میں الٰہیات ‘ نبوات اور سمعیات میں سے الٰہیات کا پہلا مبحث تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی صفات واجب ہیں۔ یہ بحث آج اختتام کو پہنچی۔الحمد للہ!
نوٹ برائے تصحیح
(۱) مباحث عقیدہ کی پچھلی قسط کے آخری پیراگراف میں ایک جملہ ’’معنی سے جڑنا پہلی ترجیح ہے‘‘ غلطی سے لکھا گیا۔ جملہ فی نفسہٖ درست ہونے کے باوجود سیاق و سباق سے غیر متعلق تھا۔ سیاق و سباق میں ’’لفظ‘‘ قرآن کی اہمیت بیان کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ معنی سے جڑنا یقیناً مقصود ہے لیکن لفظ کو بائی پاس کر کے نہیں بلکہ لفظ سے تعلق پہلے قائم کیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے معنی تک پہنچا جائے گا۔
(۲) پچھلی قسط کی تیسری ہیڈنگ’’ لفظ کے ذریعے مراداتِ الٰہی تک پہنچنے کی صلاحیت وہبی ہے‘‘ میں یہ تصحیح کر لیجیے کہ ’’وہبی‘‘ یہاں اصطلاحی معانی میں نہیں ہے کہ مراداتِ الٰہی کا بیان بھی الفاظ کی طرح ہی ہو چکا ہے‘ بلکہ ان معنی میں ہے کہ لفظ سےاس کی قطعی مرادات تک پہنچنے کے اسباب بھی مہیا کیے گئے ہیں جن کے درست استعمال سے انسان ان کے حقیقی معانی کو پاسکتاہے۔