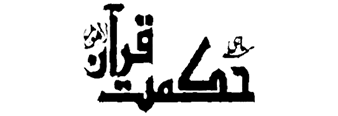(فکر و نظر) علم العقیدہ‘ سعید عبد اللطیف فودۃ اور عصرحاضر - مکرم محمود
9 /علم العقیدہ‘ سعید عبد اللطیف فودۃ اور عصرحاضر
تحریر و ترجمہ: مکرم محمود
مسلمانوں کو درپیش علمی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ دورِ حاضر و موجود میں مسلمانوں کے کلاسیکی علوم کی معنویت و مطابقت ہے۔ اس ضمن میں مختلف رویّے اور علمی آراء ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک طرف وہ طبقہ ہے کہ علم جس کے حافظے تک محدود ہے اور جو چیز جس طرح سے ملی ہے اس میں موجودہ حالات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے کسی قسم کے تغیر کا روا دار نہیں۔دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو اپنے ماضی پر شرمندہ ہے اور اپنے بڑوں کے علمی حاصلات کو دورِ حاضر سے بالکلیہ غیر متعلق سمجھتا ہے۔ دونوں طرف کی آراء اور رویے انتہا پسندی کےعکاس ہیں۔درحقیقت زمانہ ایک بدلتی ہوئی حقیقت ہے ‘اس سے آنکھیں بند کرنا ممکن نہیں۔زمانے سے آنکھیں چار کیے بغیر ’’اَنْ یَکُوْنَ بَصِیْرًا بِزَمَانِہٖ ‘‘ (وہ ہو زمانے پر نگاہِ بصیرت رکھنے والا) کا تقاضا پورا نہیں کیا جاسکتا۔ کیا ماضی کے علمی حاصلات جو صدیوں کے بحث مباحثے ‘اعتراضات اور ان کے جوابات کے بعد ایک واضح موقف اور مرتب علم کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں‘ ان کو صرف اس لیے قابلِ ترک قرار دیا جائے کہ ان کا تعلق ماضی سے ہے؟یہ دیکھے بغیر کہ وہ علمی اصول اور واضح موقف جن شبہات کو دور کرنے اور جن اعتراضات کے جوابات دینے کے نتیجے میں سامنے آئے ‘کیا وہی اعتراضات و شبہات نئے الفاظ میں اب پیش نہیں کیے جا رہے؟ کیا وہ اصولِ کلیہ صرف انہی مسائل و اعتراضات کے لیے تھے یا ان کے ذریعے اور بھی بہت سے ممکنہ مسائل اور اعتراضات کو حل کیا جا سکتا ہے؟ ان حاصلاتِ علم/علمی اصولوں کی صحیح معرفت و فہم کے ساتھ ان کے اور عصرِ حاضر کے درمیان مطابقت کے مسئلہ پر معروضی انداز میں غورو فکر کیے بغیر ان کو محض ماضی کی چیز ہونے کی وجہ سے متروک قراردینا کہاں کا انصاف اور عاقلانہ رویہ ہے؟ ’’اَلْحُکْمُ عَلَی الشَّیْئِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِہٖ‘‘ (کسی شے پر حکم لگانا اس کے صحیح تصور کے بعد ممکن ہے)کے قاعدہ کو کہاں تک نظر انداز کیا جاتا رہے گا؟
یاد رہے کہ یہاں بات’’تہذیب ‘‘،’’ طاقت ‘‘[یہ ایک امر واقعی ہے کہ اس حوالے سے ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ ہمارے علوم اور ہماری روایت اب اپنے پیچھے تہذیبی طاقت اور نظاماتی اساس نہیں رکھتی۔ اس مسئلے کو جب علوم کی تشکیل کے لیے بنائے استدلال بنایا جاتا ہے تو پھر مسئلہ پیچیدہ اور نازک ہو جاتا ہے۔ ان میں ایک تعلق ضرور ہے مگر یہ دونوں الگ الگ مسائل ہیں۔ جہاتِ تعلق اور امتیاز کے صحیح تعین کے بغیر قائم کیے جانے والا موقف کچھ سنگین نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔تجدد اور تجدید کے درمیان ایک باریک سی لائن ہے۔ اِدھر سے اُدھر جاتے دیر نہیں لگتی اوراکثر لوگوں کو اس کااندازہ نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ کلاسیکی علومِ دینیہ پر کامل دسترس اور تبحر کا نہ ہونا ہے اور اس بات سے عدمِ واقفیت ہے کہ ہمارے کلاسیکی نظم و ضبط (disciplines) اپنے اندر ایک اصولی ہم آہنگی رکھتے ہیں ۔ ایک کو چھیڑنے سے دوسرے بھی چھڑ جاتے ہیں اور متجددین کے لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے۔] اور’ ’سسٹم ‘‘ کے سیاق میںنہیں کی جارہی بلکہ علمی اعتراضات و شبہات ‘ الٰہی متن فہمی کے اصولوں اور دین کے اصولوں کی معروضی بنیادوں پر قطعی اثبات کے تناظر میں کی جا رہی ہے۔اس ضروری وضاحت کے بغیر خلط ِمبحث کا امکان تھا۔ بہرحال اس موضوع پر بات کرنا اس وقت مقصود نہیںہے۔ مقصود ایک بڑے آدمی کا تعارف ہے جو کلاسیکی عقلی علوم پر عبوراور دورِ حاضر کی اجمالی مگر ٹھوس معرفت رکھتے ہیں ۔انہوں نے اپنے تئیں دورِ جدید میں مسلمانوں کے کلاسیکی عقلی علم یعنی علم الکلام کی مطابقت و معنویت پر کلام کرنے کی کوشش کی ہے۔
استاذسعید عبد اللطیف فودۃ بلاشبہ عہدِ حاضر کے ایک بڑے متکلم ہیں۔ آپ کا تعلق اردن سے ہے‘ اصلاً آپ فلسطینی ہیں۔آپ کا سن پیدائش ۱۹۶۷ء ہے۔بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں جبکہ ابھی تصنیف و تالیف کا کام ماشاء اللہ جاری ہے۔دورِ حاضر میں اتنی کثیر التصانیف شخصیت مشکل ہی سے کوئی اور ملے گی۔ علم اصول الدین آپ کا خصوصی موضوع ہے‘ خاص طور پر علم العقیدہ والکلام۔ آپ کو ایک بڑا متکلم قرار دیے جانے کی وجہ آپ کا علمی و تحقیقی کام اور تصانیف ہیں نہ کہ یوٹیوب ویڈیوز۔ علمی خدمات پرآپ کو ’’ناصِرُالسُّنَّۃ‘‘ کا خطاب دیا گیا ہے۔ آپ کلاسیکی علم الکلام کے احیاء کے داعی ہیں‘ اس میں کچھ ضروری تغیر و تبدل کی ضرورت کے قائل ہونے کے ساتھ۔ اس سلسلے میں آپ کے بہت سے شاگرد بھی اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔
قدیم علم کلام کو مکمل طور پر ترک کر دینے اور اس کی ہیئت اور اصولوں کو مکمل طور پر بدل دینے کی ضرورت کا نعرہ بلند کرنے والے اصل میں دانستہ یا نادانستہ تجدد کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ کسی بھی کلاسیکی علم سے ضروری واقفیت اور بعض جہات پر مکمل دسترس کے بغیر اس علم کی تجدید کی کوشش تجدد کو جنم دیتی ہے۔ ایسی کوششیں اکثر اپنے زمانے سے حد سے زیادہ تاثر لینے کے نتیجے میں سامنے آتی ہیں۔ یہ بات بجا ہے کہ ہم ایک منفرد اور جدید عہد میں زندہ ہیںجو عہدِ ما سبق سے بہت حد تک مختلف ہے ۔اس کی وجوہات میں ہماری کمزوری‘ مغربی تہذیب کا ہمہ گیر استیلاء اور ٹیکنالوجی خاص طور پر سائبر ٹیکنالوجی میں ترقی ہے ‘ جنہوں نے ہمارے اسلوبِ ہستی اور اندازِ تعلق کو بدل دیا ہے۔کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت میں کوئی اساسی تبدیلی واقع ہو گئی ہے یا انسانی عقل جو عطیۂ خداوندی ہے‘ کسی اور عقل میں تبدیل ہو گئی ہے؟ ایسا قطعاً نہیں ہے ‘ورنہ شاید ایک نئے دین کی احتیاج ہوتی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ فطرت اور عقل کے مسخ ہونے کے امکانات حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور انسان کے خارج سے متعلق ہونے کے انداز میں ایک اساسی تبدیلی واقع ہو چکی ہے۔ لیکن کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علوم کی تشکیل بھی اس مسخ شدہ فطرت اور عقل کو بنیاد بنا کر کی جائے؟ ظاہر ہے کہ abnormalityکو معیار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ معیار عاقلوں کو ہی قرار دیا جائے گا چاہے پاگلوں کی کثرت ہو جائے۔
نہایت گمبھیر صورتحال ہے اور ایسے میں ہمارے کلاسیکی علوم کس حد تک عہدِ جدیدکے ساتھ متعلق (relevant)ہیں یا ان کا کتنا حصّہ عہدِ جدید کے مسائل کی تفہیم اوران کے حل کی طرف پیش رفت میں ہماری مدد کرتا ہے‘ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر اہل ِعلم کو غور کرنا چاہیے۔اسی ضمن میں قدیم علوم پر کامل دسترس اور عہدِ جدید کی ضروری واقفیت رکھنے والے مذکورہ بالا متکلم کے مختصر کلام کا ترجمہ آگے پیش کیا جا رہا ہے۔
ایک اصولی بات بہرحال سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے کلاسیکی علوم ہماری اسلامی علوم کی روایت میں فرداً فرداً ایک دوسرے سے انقطاع کی حالت میںموجود نہیں تھے ‘خاص طور پر علم العقائد‘ علم التفسیراور علم اصول الفقہ آپس میں ایک اصولی ربط رکھتے ہیں۔ان علوم کے حوالے سے اُمت میں بہت سے منہجی اور فروعی اختلافات پائے جاتے ہیں‘لیکن کچھ بنیادی اصولوں پر اُمّت کا ایک بڑا طبقہ متفق بھی ہے۔ ان اصولوں میںتغیر و تبدل کی کوشش الٰہی متن کے فہم کے اصولوں پر لازماً اثر انداز ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ان حضرات(متجددین) کا منہج داخلی طور پر تضاد سے پاک ہے جو علومِ شرعیہ اور متن(قرآن و سُنّت) میں ایک تغایر کے قائل ہیں‘ علومِ شرعیہ کو ایک وقت و زمانے کی ضرورت قرار دیتے ہیں‘ اور زمانے اور حالات کے بدلنے کے نتیجے میں متن الٰہی (قرآن و سُنّت ) سے نئے اصولوں کے اخذ و استنباط کی بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلامی کلاسیکی علوم کو تاریخی قرار دیتے ہیں اور ان کی تاریخی اور تہذیبی اہمیت کے نہ صرف قائل بلکہ داعی ہیںلیکن دورِ حاضر وموجودمیں ان علوم کو اپنی اصولی حیثیت میں متروک قرار دیتے ہیں۔ ہاں نئے علوم کی تدوین و تشکیل میں ان سے جزوی فوائد ضرور حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ان حضرات کا منہج مکمل طور پر غلط ہو سکتا ہے ‘اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے ‘لیکن یہ منہج داخلی تضادات نہیں رکھتا۔
باقی وہ لوگ جو کہتے تو اپنے آپ کو ’’روایتی‘ ‘ یا’’تراثی‘‘ ہیںلیکن ان کلاسیکی علومِ اسلامیہ کے حوالے سے ایسی رائے ان سے عدمِ واقفیت یا کچھ اور وجوہات کی بنا پر اختیار کرتے ہیںجس کے نتیجے میں وہ علوم اصولی تغیر سے بچ نہیں پاتے اور ان کی تشکیل جدید عہدِحاضر سے اخذ کردہ اصولوں کی روشنی میں ہوتی ہے۔ یہ عمل کچھ لوگوں میں شعوری اور کچھ میں لا شعوری طور پر ہوتا ہے۔ سعید عبد اللطیف فودۃ خاص طور پر علم العقیدہ یا علم الکلام کے حوالے سے اس بات کے قائل ہیں کہ کلاسیکی علم الکلام کے کچھ اصولوں میں تغیرو تبدل کے نتیجے میں جدید دور میں عقائد ’’یقینی ‘‘کے بجائے ’’ ترجیحی ‘‘ قرار پاتے ہیں۔’ ’ایمان‘ ‘ اور’ ’علم‘ ‘ میں نا قابلِ عبور حدِّفاصل قائم ہو جاتی ہے اور ان کا تعلق مضمحل اور مشتبہ ہو جاتا ہے۔ ایمان اور عقیدہ محض ایک ’’موضوعی‘‘‘’ ’فطری‘ ‘ اور subjective بیانیہ بن کے رہ جاتا ہے۔ عقائد ِحقّہ اور عقائد ِباطلہ میں تفریق کچھ قطعی اصولوں کی روشنی میں نہیں ہو پاتی اور ایمانی جست (leap of faith) سے ہی کام چلانا پڑتا ہے۔یہیں سے دورِ حاضر یعنی دورِ شک ‘اضطراب و دجل میں پائے جانے والے تکثیریت (plurality) اورمشمولیت (inclusivity)کے بیانیے کے قبول کر لیے جانے کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ یقیناً اس کا واحد نہیں لیکن ایک بڑا سبب ضرور ہے۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے اور الگ سے کلام کا محتاج ہے۔
ذیل میں تین موضوعات پر مختصر مگر جامع کلام کا ترجمہ کیا گیاہے۔’’البدایۃ‘‘ سعید فودۃ مد ظلہ کی کتاب ’’بحوث فی علم الکلام‘‘ کا ابتدائیہ ہے جو علم توحید و عقیدہ کے کچھ بنیادی مباحث کا احاطہ کرتاہے۔ علم الکلام میں ایک اہم موضوع ’’اوّل واجب علی الانسان‘‘ کا ہے۔ ابتدائیہ کے فوراً بعد شیخ نے اسی موضوع کو چھیڑا ہے۔ اس پر بھی نہایت مختصر مگر جامع کلام ہے۔ تیسرا اقتباس ان کی کتاب’ ’موقف الغزالی من علم الکلام‘‘ کی تمہید سے لیا گیا ہے۔ اس کا عنوان ہے: ھل علم الکلام یحتاج الی التجدید؟ اختصار کے باوجود بہت سی بنیادی اصولی باتیں اس میں نقل کر دی گئی ہیں۔ اس میں بیان کردہ موقف بعینہٖ وہی ہے جو مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ نے تقریباً سو سال پہلے اپنی کتاب ’’الانتباھات المفیدۃ عن الاشتباھات الجدیدۃ‘‘ کے شروع میںاختیار کیا ہے۔[ یہ کتاب حضرتؒ کے اس سفر بنگال (۱۹۰۹ء)کا نتیجہ ہے جس کے راستے میں چھوٹے بھائی سے ملاقات کے لیے علی گڑھ اُترنا ہوا۔ کالج کے کچھ طلبہ کو خبر ہو گئی تووہ حضرت کو لے گئے اور ایک تفصیلی بیان بھی ہوا۔ اگرچہ حضرت کے ذہن میں مسائل و شبہاتِ جدیدہ کے حل و رفع و ازالے کے لیے کچھ تصنیفی و تالیفی کام کرنے کی خواہش پہلے سے تھی لیکن علی گڑھ کے طلبہ سے ملاقات اور ان میں فہم و انصاف کے آثار پانے کے نتیجے میں حضرت کے اس خیال کو مہمیز ملی کہ کچھ قواعد ِاصولیہ فوری منضبط کر دیے جائیں جو حل و دفعِ شبہات کے لیے کافی ہوں۔ ہر شبہ کا الگ الگ جواب ان اصولوں کی روشنی میں بعد میں دیا جاتا رہے گا۔ چنانچہ یہ کتاب سامنے آئی۔ اس زمانے میں علمِ کلام جدید کا غلغلہ بلند ہو چکا تھا اور علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ’’علم الکلام اور الکلام ‘‘کو آئے ہوئے چھ سات برس ہو چکے تھے۔]
چنانچہ ہم یہاں ان کا اقتباس نقل کر دیتے ہیں تاکہ بات کی وضاحت ہو جائے اور جو موافقت ہے وہ سامنے آجائے۔مولانا تھانوی ؒوجہ تالیف ِرسالہ کے ضمن میں لکھتے ہیں:
’’اس زمانہ میں جو بعض مسلمانوں میں اندرونی دینی خرابیاں عقائد کی اور پھر اس سے اعمال کی پیدا ہو گئی ہیں اور ہوتی جا تی ہیں‘ ان کو دیکھ کر اس کی ضرورت اکثر زبانوں پر آرہی ہے کہ علمِ کلام جدید مدوّن ہونا چاہیے ‘گو یہ مقولہ علم کلام مدوّن کے اصول پر نظر کرنے کے اعتبار سے خود متکلم فیہ ہے ‘کیونکہ وہ اصول بالکل کافی وافی ہیں۔ چنانچہ ان کو کام میں لانے کے وقت اہل ِ علم کو اس کا اندازہ اور تجربہ عین الیقین کے درجے میں ہو جاتا ہے‘ لیکن باعتبار تفریع کے اس کی صحت مسلّم ہو سکتی ہے‘ مگر یہ جدید ہونا شبہات کے جدید ہونے سے ہوا ۔اور اس سے علمِ کلام قدیم کی جامعیت نہایت وضوح کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ گو شبہات کیسے ہی اور کسی زمانے میں ہوں مگر ان کے جواب کے لیے بھی وہی علم کلام قدیم کافی ہو جاتا ہے۔ سو ایک اصلاح تو اس مقولہ میں ضروری ہے ۔ دوسری ایک اصلاح اس سے بھی زیادہ اہم ہے‘ وہ یہ کہ مقصود اکثر قائلین کا اس مقولہ سے یہ ہوتا ہے کہ شرعیاتِ علمیہ و عملیہ جو جمہور کے نزدیک متفق علیہ ہیں اور ظواہر نصوص کے مدلول اور سلف سے محفوظ و منقول ہیں‘ تحقیقاتِ جدیدہ سے ان میں ایسے تصرفات کیے جاویں کہ وہ ان تحقیقات پر منطبق ہو جاویں‘گو ان تحقیقات کی صحت پر مشاہدہ یا دلیل عقلی قطعی شہادت نہ دے۔ سو یہ مقصود ظاہر البطلان ہے۔ جن دعووں کا نام تحقیقاتِ جدیدہ رکھا گیا ہے‘ نہ وہ سب تحقیق کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں بلکہ زیادہ حصّہ ان کا تخمینیات و وہمیات ہیں‘ اور نہ ان میں سے اکثر جدید ہیں بلکہ فلاسفہ متقدمین کے کلام میں وہ مذکورہ پائے جاتے ہیںاور ہمارے متکلمین نے ان پر کلام بھی کیا ہے۔چنانچہ کتب ِکلامیہ کے دیکھنے سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ البتہ اس میں شبہ نہیں کہ بعضے شبہات جو السنہ سے مندرس ہو چکے تھے ‘ ان کا اب تازہ تذکرہ ہو گیا ہے‘ اور بعض کا کچھ عنوان جدید ہو گیا ہے اور بعض کے خود مبانی‘ جن کو واقعی تحقیقات جدیدہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے۔ باعتبار معنوں کے بھی جدید پیدا ہو گئی ہیں۔ اس اعتبار سے ان شبہات کے اس مجموعے کو جدید کہنا زیبا اور ان کے دفع اور حل اور جواب کو اس بنا پر بھی کہ جدید شبہات بالمعنی المذکور کے مقابلہ میں ہیںو نیز اس وجہ سے بھی کہ بلحاظ مذاق اہل ِزمانہ کے کچھ طرزِ بیان میں جدّت مفید ثابت ہوئی ہے‘ کلامِ جدید کہنا درست و بجا ہے اور اس تاویل سے یہ مقولہ کہ علمِ کلام جدید کی تدوین ضروری ہے‘ محل ِانکار نہیں۔‘‘
حضرت تھانویؒ کا محولہ بالا اقتباس اپنی جامعیت کے اعتبار سے ایک منفرد شان رکھتا ہے اور اس مسئلے کے حوالے سے تمام اصولی باتیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں ۔ اس کی شرح و وضاحت میں بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے مگر اس وقت مقصد صرف حضرت کے موقف کا بیان اور اس کی موافقت سعید فودۃ صاحب کے بیان کردہ موقف سے دکھانا ہے۔ اسی سبب سے اس اقتباس کی لفظی و معنوی تسہیل ضروری معلوم ہوتی ہے۔اس اقتباس سے ہمیں درج ذیل باتیں واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں:
(۱) اصولِ علمِ کلام قدیم بالکل کافی ہیں۔
(۲) فروع میں تغیر و تبدل‘شبہات اور مسائل جدیدہ کے سبب سے ممکن ہے۔
(۳) فروعات میں تغیر و تبدل انہی مسائل و شبہاتِ جدیدہ پر قدیم علم کلام کے اصولوں کے انطباق کا نتیجہ ہوگا۔
(۴) علم کلام جدید کے غلغلہ سے بعض لوگوں کا مقصد دین کے اجماعی حقائق و مفاہیم کو بدل دینا ہے۔ یہ مقصود تو واضح طور پر باطل ہے۔
(۵) تحقیقاتِ جدیدہ کا اکثر حصّہ تخمینی و و ہمی ہے۔( Philosophy of Scienceکی سمجھ رکھنے والے حضرات اس بات کو بطریق ِ احسن سمجھ سکتے ہیں۔)
(۶) اکثر شبہات اور مسائل ِجدیدہ کی صرف صورت جدید ہے‘ حقیقت نہیں۔ البتہ بعض ایسے بھی ہیں جو صورت و حقیقت دونوں اعتبارات سے جدید ہیں۔
(۷) ان جدید شبہات و مسائل کے جواب دینے کے لیے اور زمانہ کے بدلنے کے نتیجے میں طرزِ بیان میں جو تبدیلی واقع ہوئی ہے اس سبب سے علم کلام جدید کی تدوین کا مقدمہ ثابت ہے۔
اب ذیل میں ترجمہ دیا جاتا ہے:
البدایۃ (بحوث فی علم الکلام)
’’علم ِتوحید اشرف العلوم ہے۔ ایک مکلّف پر جو چیز سب سے پہلے واجب ہوتی ہے وہ توحید ہی ہے۔ توحید کے مفہوم میں اللہ پر ایمان شامل ہے ۔یہ قلوبِ انسانی کے لیے سب سے اہم اور ضروری عقیدہ ہے۔ توحید دین کی اصل ہے ۔اسی لیے علم ِتوحید کو علم اصول الدین بھی کہا جاتا ہے ‘کیونکہ یہ علم ان قواعد ِکلیہ کو شامل ہے جن پر دین کی اساس ہے۔ اس علم کو علم الکلام بھی کہا جاتا ہے ‘کیونکہ توحید کا رسوخِ کامل نفس میں اکثر کلام کے بغیر نہیں ہوتا اور یہ وجہ بھی ہے کہ اس علم کا ایک بڑا مسئلہ کلام ِباری کا ہے۔ قلب سے مراد یہاں وہ ہے جیسا کہ امام غزالی نے کہا ’’ـقلب ایک لطیفہ ربانی ہے جو مخاطب الٰہی ہے اور وہی ہے جو ثواب و عقاب کا حق دار ہے اور اس کا تعلق صنوبری شکل کے لوتھڑے سے ایسا ہے جیسا عرض کا جوہر سے ‘اور اسی کو روح اور نفس بھی کہا جاتا ہے۔‘‘
قلب سے امام صاحب کی مراد روح ہے۔ لطیفہ کا مطلب ایک ایسا امر ہے جس کا ادراک عقول کے لیے مشکل ہے۔ ربانیہ سے مراد ہے کہ اس کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے اور اس کی حقیقت کے علم کو اپنے ساتھ خاص رکھا ہے ‘یعنی وہ عقول سے پردے میں ہے۔ پس جیسے ذاتِ خداوندی کا ادراک مستحیل ہے اسی طرح اس(قلب) کا بھی ادراکِ تام نا ممکن ہے۔ اسی پر ثواب و عقاب کا دار و مدار ہے ‘کیونکہ اصل ادراک تو روح کا فعل ہے ‘جسم بس ایک آلہ ہے۔حواس فی ذاتہٖ مدرک نہیں ہیں بلکہ وسائل ادراک ہیں اور قلب کا تعلق جسم صنوبری کے لوتھڑے سے ارادے اور شوق کے اعتبار سے ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کا اشتیاق ہوتا ہے اور کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ اس اشتیاق کو اپنے (صنوبری) دل میں محسوس کرتے ہیں اور اس اشتیاقِ قلبی سے اس کام کی طرف توجّہ عملی پیدا ہوتی ہے ۔ ارادہ محرکِ اعمال ہے اوراس کا محل قلب ہے۔ یہ تعلق کے بہت سے اندازوں میں سے ایک انداز ہے اور یہ سب سے واضح ہے۔پس روح پر ہی اعتقاد واجب ہے اور اعتقاد وہ ذکر ِنفسی ہے جس کے متعلقات میں ذاکر کے نزدیک نقیض کا احتمال نہیں ہوتا ۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا اور اس سے یہ سمجھا گیا کہ اعتقاد ہی علم ہے‘ لیکن اعتقاد ایک نفسی کیفیت ہے جو نفس میں راسخ ہوتی ہے اور یہ کیفیت نتیجہ ہے اس تعلق جازم کے حصول کا جو نفس کو ایک متعین قضیہ (معتقدات) سے ہوتا ہے۔ یہ تعلق بعض اوقات دلائل سے حاصل شدہ علم کا نتیجہ ہوتا ہے اور بعض اوقات تقلید محض کا نتیجہ ہوتا ہے یا کچھ اور اسباب و بواعث اعتقاد کا۔
جو بات مجھ پر واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اعتقاد علم نہیں ہے‘ اور یہ بات ٹھیک ہے جب ہم کہیں کہ علم کیفیت نفسی نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق نفس کے افعال اور انفعالات سے ہے۔ کیونکہ اگر علم کی بنا اس پر ہو (یعنی مقولہ کیف[ممکن مقولاتِ عشرہ میں منقسم ہوتا ہے‘ نو عرض کے اور ایک جوہر کا۔ عرض کے مقولات میں کم‘ کیف‘ این‘ وضع‘ متی‘ اضافہ‘ ملک‘ فعل اور انفعال شامل ہیں۔ کیف: ھو عرض لا یقتضی القسمۃ ولا نسبۃ لذاتہ۔ کیف اس عرض کو کہتے ہیں جو لذاتہٖ نہ تقسیم کو قبول کرتا ہے اور نہ نسبت کو۔ یہ کبھی تو مادّی اجسام کے ساتھ قائم ہوتا ہے‘ جیسا کہ سواد‘ بیاض ‘ علو وغیرہ اور کبھی مجردات کے ساتھ قائم ہوتا ہے ‘جس طرح علم‘شجاعت‘ قدرت وغیرہ۔ تفصیل کے لیے دیکھیے:تشریحاتِ سواتی علی ایسا غوجی ‘از صوفی عبدالحمید سواتی ۔] سے نہ ہو) تو ممکن ہے کہ ایک انسان کو علم ہو لیکن اس پر اعتقاد نہ ہو یعنی اسے اپنے معلوم سے کوئی ربط و تعلق نہ ہو۔
جیسے یہودی احبار اور عیسائی علماء جن کو علم تھا کہ اللہ کے نبی ﷺ رسولِ بر حق ہیں لیکن ان کا اعتقاد یہ نہیں تھا یعنی وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبیﷺ کے چچا جو جانتے تھے کہ آپؐ نبی ہیں‘ یہ ان کے عقیدے میں نہیں ڈھلا۔ اسی طرح اگر علم باب کیف (مقولہ کیف)سے ہو تب بھی ایمان کو علم نہیں کہا جاسکتا‘ کیونکہ ایسے مؤمن ہوتے ہیں جو اپنے معتقدات کی حقیقت کے عالم نہیں ہوتے(یعنی ایمان بغیر دلیل کے ہوتا ہے)۔ اسی طرح ایسے امور کو ماننے والے بھی پائے جاتے ہیں جو صحیح اور مطابق ِواقعہ نہیں ہوتے۔
میرے نزدیک اصل بات یہ ہے کہ اعتقاد مقولہ کیف سے ہے۔ پس اعتقاد ایک کیفیت ہے جس سے نفس اپنے کسی معیّن فعل ا ختیاری کے نتیجے میں آراستہ ہوتا ہے۔ یہ صرف کوئی فعل یا انفعالی حالت نہیں ہے۔ پس دین کے ماننے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی صفاتِ نفسانیہ اس کیفیت اور ہیئت میں ہوں جس کا دین نے حکم دیا ہے۔ یہ صرف علم سے الگ ایک معاملہ ہے جیسا کہ واضح ہے۔ یہ کیفیاتِ نفسانیہ اس بات کو ضروری ٹھہراتی ہیں کہ نفس جھک جائے اور حقائق ِدینیہ کے سامنے پستی اختیار کرےاور ان پر غالب آنے کی کوشش نہ کرے۔ پس یہ کم از کم تقاضا ہے جس سے ماہیت اعتقاد کا اثبات ہوتا ہے۔ اسی لیے کچھ علماء نے کہا کہ اعتقاد تعلق اور ثبات کا نام ہے۔
کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مقصود یہ ہے کہ معلوم سے اپنا تعلق اور ربط قائم کیا جائے جبکہ ربط و تعلق میں ایک کیفیت کا دوسری کیفیت میں بدل جانا ناگزیر ہے۔ یہی(دوسری صورت) توحید اور عقائد ایمانیہ ہیں۔ اسی لیے ہم اعتقادِ مقلّدپر صحت کا حکم لگا سکتے ہیں ‘کیونکہ ایمان اصل میں ایک خاص کیفیت کا نام ہے اور مقلّد کو وہ حاصل ہوتی ہے۔اس کیفیت کے سبب کی تفتیش نہیں کی جائے گی بلکہ صرف اس کے ہونے یا نہ ہونے کو دیکھا جائے گا۔ پس اعتراض نہیں کیا جائے گا اگر اس کیفیت کی بنا کسی دلیل پر نہ ہو۔ اس وضاحت کی بنیاد پر ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان حامل اخلاقِ قرآنیہ ہو جائے جب تک کہ وہ اصل توحید اور صحیح ایمان کو اپنے دل میں جاگزیں نہ کرے۔
صدق کے بھی مراتب ہیں۔مؤمن بھی سچ بولتا ہے اور کافر بھی ‘لیکن کافر کو اس کے سچ کا ثواب نہیں ملے گا‘ کیونکہ اصل جو کہ اعتقادِ سلیم ہے (جس پر مدارِ ثواب ہے) اس کے پاس موجود اور اس کے اندر جاگزیں نہیں ہے۔یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اخلاق سلیمہ کو حاصل کرے مگر یہ کہ وہ توحید اور صحیح عقیدے کا حامل ہو۔اسی لیے یہ منافی حکمت ہے کہ لوگوں کی تعلیم کا آغاز اخلاق سے اور اس کی ترغیب دلانے سے کیا جائے مگر یہ کہ پہلے عقیدئہ سلیمہ ان کے نفوس میں راسخ ہو چکا ہو۔ اگر وہ اخلاقِ حسنہ سے بظاہر تخلّق اختیار کر بھی لیں تو بھی اس کا اثر سطحی ہو گا‘ کسی حقیقی تبدیلی کا باعث نہیں بنے گااور نہ ہی ان کو اپنے آپ کو بدلنے پر اُبھارے گا ‘کیونکہ اس طرح کے مظاہر کسی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے۔ ایمان کے بغیر کسی انسان کو وعظ مفید نہیں ہوتا۔
عقائد سے مراد وہ قضایا ہیں جن پر عمل کےبغیراصلاً اعتقاد مطلوب ہے ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقائد سے اعمال ظاہر نہیں ہوتے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ صحیح عمل صحیح عقیدے ہی سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان قضایا ہی کو عقائد کہا جاتا ہے ‘چاہے ان پر کسی عمل کی بنا نہ ہو۔ اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عمل انسان کو ایمان سے خارج نہیں کرتا۔ یہی مذہب ِاہل ِسُنّت ہے اور حق ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک انسان کا عقیدہ سلیم ہو اور اس کے اعمال باطل ہوں ‘جیسا کہ ایک فاسق انسان ہوتا ہے۔ یہیں سے کفر اور تکفیر کے مابین تمیز بھی واجب ہوتی ہے۔ پس کفر نہیں ہے مگر یہ کہ آپ کچھ صحیح معتقدات کی مخالفت کریں ‘صرف عمل کی نہیں‘جبکہ تکفیر میں امکان ہے کہ وہ کچھ اعمال کی بنیاد پر بھی کر دی جائے۔ عقیدے کی یہ تعریف عقائد فی نفسہٖ کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے اس بات کے ساتھ کہ عقائد ہی وہ اصل ثابت ہیں جن سے صحیح عمل جنم لیتا ہے۔البتہ جب بھی ہم عقائد کو موضوع بنائیں تو یہ ہمار ے لیے جائز نہیں کہ ہم ایسا اس لیے کریںکہ ان پر عمل کا دارومدار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عقائد اپنی ذات میں مطلوب ہیں اور پھر اس پر عمل بھی مرتب ہو جاتا ہے۔ پس اعتقادِ صحیح کے بغیر عمل ِصحیح نہیں ہوتا۔
اوّل واجب علی الانسان (انسان پر سب سے پہلے کیا واجب ہے؟)
’’تمام عقائد مکلّف وجود پر واجب ہیں لیکن شروع میں ان تمام عقائد کا اظہار زبان سے واجب نہیںہے‘ صرف شہادتین کا اظہار زبان سے ضروری ہے۔ بقیہ عقائد کا اظہار زبان سے تب واجب ہوتا ہے جب ضرورت کے وقت مکلّف سے ان کے بارے میں پوچھا جائے ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان سے ان الفاظ کا اظہار کرے جو اس کے اعتقاد پر دلالت کریں۔
جمہور اہل علم کا موقف جن میں امام مالک ؒاور امام اشعریؒ شامل ہیں ‘یہ ہے کہ مکلّف پر پہلا واجب اللہ‘ اُس کے رسولﷺ اور اس کے دین کا علم ہے۔ یہ علم کہ کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کے حق میں واجب ہیں‘ کیا جائز ہیں اور کیا مستحیل ہیں ۔اسی طرح ان چیزوں کا علم جو اس کے رسولﷺ اور دین سے متعلق ہیں۔ وہ واجب جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا اس سے مراد صفاتِ واجبہ ہیں‘ جیسے قدرت اور نسبت واجبہ ہے ‘ایسے ہی اللہ کے لیے صفت ِقدرت کا ثبوت۔
بعض علماء نے کہا کہ مکلف پر پہلا واجب نظر ہے(یعنی غور و فکر‘ عقل نظری کا استعمال ) جبکہ بعض نے کہا کہ واجب صرف نظر کا قصدو ارادہ ہے(یعنی اگر بالفعل بعض موانع کے سبب سے نہ کر سکا تو معذور ہوگا)۔ کچھ علماء نے کہا کہ نظر کا پہلا جزو واجب ہے۔ (اس ظاہری اختلاف سے) یہ گمان نہ کرو کہ علماء کے درمیان یہ کوئی حقیقی اختلاف ہے یہاں تک کہ اس کے بعد تم کہو کہ جب اول واجبات میں اتنا اختلاف ہے تو بقیہ عقائد اور فقہ میں کتنا ہوگا۔ تمہاری یہ سوچ تمہیں علماء کو (علم اور کردار میں)ہلکا سمجھنے پر اُبھارے گی اور یہیں سے گمراہی اور خسران کا دروا ہوگا۔پھر تم اپنی فاسد رائے اور عقلِ قاصر‘ جو اس طرح کے مسائل میں غور و فکر کے قابل نہیں ‘پرجم جائو گے۔ ان تمام اقوال کا (جن میں تمہیں اختلاف محسوس ہو رہا ہے) منبع واحد ہے اور یہ علم توحید کے فہم کو نفوس میں راسخ کرتے ہیں۔ ان کے درمیان اختلاف محض ظاہری ہے۔
جس نے کہا کہ سب سے پہلا واجب زبان سے شہادتین کا اظہار ہے ‘ا س کامقصد یہ ہے کہ کافر کے خون کا حرام ہو جانا۔ اور اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کرنا ممکن نہیں جب تک کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ شہادت ادا نہیں کرتا۔ یہ وہ پہلا معاملہ ہے جس میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے تاکہ اس کی کفر سے براء ت اور اسلام میں داخلے کا اعلان ہو جائے۔ جس نے یہ کہا کہ مکلف پر سب سے پہلا واجب اللہ‘ اُس کے رسول ﷺاور اُس کے دین کا علم ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ زبان سے شہادتین کی ادائیگی بھی تب اللہ کے نزدیک معتبر ہو گی جب اس کو اپنے ذکر کردہ کلمات کا اجمالی علم تو حاصل ہو‘تاکہ زبان سے کلمہ توحید کی اس کے معانی کے ساتھ ادائیگی صحیح و معتبر ٹھہرے۔ اسی طرح اس کا اعتقاد بھی(صحیح و معتبر قرار پائے)۔ جس نے یہ کہا کہ پہلا واجب نظر ہے اس نے یہ اس لیے کہا کہ عام طور پر ایک انسان کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ بغیر غور وفکر کے حق تک پہنچے‘ چاہے وہ غور و فکر اجمالی ہی کیوں نہ ہو۔ پس جب وہ سوچے گا تو علم تک پہنچے گا اور اس کی زبان سے کلمہ توحید ادا ہوگا۔یہ اس لیے بھی کہا کہ حق پر استدلال کے لیے نظر واجب ہے۔
جس نے اس رائے کا اظہار کیا کہ پہلا واجب قصد ِنظر (یعنی نظر کا ارادہ کرنا )ہے‘ اس کی رائے کا سبب یہ ہے کہ انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ بالفعل نظر کرے مگر یہ کہ اس کام کے لیے اس کی نیت اور اس کا عزم ہو۔ پس سبب کو بھی نتیجے کے حکم میں شمار کیا گیا (یعنی اگر نظرواجب ہے اور نظر بغیر ارادے اور نیت کے ممکن نہیںتو ارادہ و نیت بھی واجب ہے۔ایک اصولی قاعدہ ہے : ما لا یتم الواجب الا بہ فھو واجبکہ اگر واجب کی ادائیگی صحت کے ساتھ کسی خاص سبب کے بغیر نہ ہو سکتی ہو تو وہ سبب بھی واجب ٹھہرے گا )۔ جن کی یہ رائے تھی کہ واجب نظر کا پہلا جزو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غور و فکر کا عمل کچھ مرتب اجزاء رکھتا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جزوِ ثانی سے نظر کا آغاز کریں مگر یہ کہ پہلے جزوپر غور و فکر کو مکمل کیا جائے۔
اسی طرح ہم علمائے شریعت کے بہت سے اقوال میں ظاہری تناقض و تضاد دیکھتے ہیں جبکہ حقیقت میں ان میں اتفاق ہوتا ہے اور یہ مختلف آراء ایک دوسرے کی تکمیل کا سامان کرتی ہیں۔ وہ جاہل ِمحض انسان جو علمائے شریعت کے ساتھ سوئے ظن رکھتا ہے‘ ان کے اجتہادات کو اس طرح پیش کرتا ہے جس سے ان علماء کے مراتب کی تنقیص لازم آئے اور یہیں سے وہ ان کے اقوال و مذاہب پر تنقید کرتا ہے ۔پس اصل بات یہ ہے کہ وہ اقوال و اجتہادات کی حقیقت سے ناواقف ِمحض ہے اور نہ ہی وہ ان کا احاطہ کر سکتا ہے‘ بلکہ وہ اس کام میں پڑا ہی اپنے نقص معرفت کی وجہ سے ہے ‘پھر دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اس( ظاہری)اختلاف و تضاد کا سبب فلسفہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ فلسفہ کو بھی نہیں جانتا اور نہ ہی علماء کے اقوال و اجتہادات کی فنی باریکیوں سے واقف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ علمائے شریعت‘ اللہ اُن پر اپنی رحمتیں نازل کرے ‘کے کلام کا حامل بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ‘‘
ھل علم الکلام یحتاج الی التّجدید(کیا علم الکلام کو حاجت ِتجدید ہے؟)
’’یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو میرے غور و فکر کا مستقل موضوع ہے بلکہ میرا سب سے بڑا دینی مسئلہ اور میری کوششوں کا محور یہی ہے۔
بے شک علم الکلام کسی بھی علم ِانسانی کی طرح (زمانے کی مناسبت اور مسائل و حالات میں تبدیلی کی وجہ سے) تبدیلی اور حذف و اضافے کا ہمیشہ محتاج رہے گااور علم الکلام کی تاریخ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے ۔ اس کی وجہ علم الکلام کے موضوع کو جان لینے سے واضح طور پر سامنے آجاتی ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ علم الکلام کے بہت سے مسائل وہ شبہات ہیں جومخالفین اس دین پر وارد کرتے ہیںاور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ یہ شبہات بعض اوقات قدیم ہوتے ہیں‘ بس ظاہری شکل جدید ہوتی ہے جبکہ بعض شبہات مکمل طور پر جدید ہوتے ہیں ۔ دونوں صورتوں میں بحیثیت متکلمین اسلام ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس شبہ کو سمجھیں‘ اس پر غور کریں اور اس کے فساد و بطلان کو ظاہر کریں۔ اگر وہ جدید ہو تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اصولِ کلیہ کلامیہ پر دوبارہ غور کریں تاکہ ایسے قواعد کا استنباط کیا جاسکے جو ان اعتراضات و شبہات کو دور کر سکیں۔
علومِ شرعیہ میں سے کوئی بھی علم جو (اپنی نشوونما اور حوادث کے سبب سے شرعی حکم کے اخذ و استنباط میں) انسانی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ ہو‘اس احتیاج سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ بات صرف علم الکلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہم علمِ فقہ‘ علمِ تفسیر اور بقیہ تمام علوم ِ شرعیہ کوبھی اس کا محتاج سمجھتے ہیں(یعنی زمانے کے بدلنے اور نئے انسانی مسائل کے سامنے آنے سے ان علوم کے قواعد و فروعات کو تبدیلی کے عمل سے گزارنانہ کہ اصولوں کو) لیکن یہ بات کسی صورت جائز نہیں ہو گی کہ قولِ تجدید کا قائل اس احتیاجِ تجدید و اضافے کے دائرے کو اصولِ کلیہ تک پھیلا دے جن پر تمام علمائے اُمّت کا اجماع ہے۔یہ(اصولوں میں تجدید و تبدیلی) اس لیے ناجائز ہے کہ یہ بات سلف پر گمراہی کے الزام کا سبب بنتی ہے اور اس بات تک کہ دین ان پر واضح نہیں تھا(کہ زمان و مکان کی تبدیلی دین کے اصولوں کو بھی بدل سکتی ہے)۔ تحقیق پر مبنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام زمانوں میں اس( دین )کے بیان کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔یہ اس لیے بھی جائز نہیں ہے کہ یہ (تجدید فی الاصول ) عقائد ِقطعیہ میں تغیر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے اس قول سے کہ ہمارے لیے (عہدِ جدید میں ) ضروری ہے کہ ہم اس علم الکلام سے دامن چھڑا لیں یا ہم اس کی ساخت اور مادہ میں بہت بنیادی تبدیلیاں کریں‘ ہم اپنے آپ کو بالکلیہ متفق نہیں پاتے۔ شق ِاوّل کہ علم الکلام کو مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے ‘اس کا بطلان ہم واضح کر آئے ہیں۔ جہاں تک ساخت اور مضمون میں تبدیلی کی بات ہے ‘اگر مضمون میں تبدیلی سے مراد تمام قواعد کا بدل دینا ہے جن سے استدلال مکمل اور ثابت ہوتا ہے تو یہ بات محض باطل ہے۔ ضرورت تو تنقیح قواعد کی ہے اور ان میں زیادتی کی اگر ممکن ہو(قواعد سے مراد اصول نہیں ہیں۔قواعد اصولوں سے اخذ کیے جاتےہیں)مگر نہایت ہی احتیاط کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے۔ اگر ان کی مراد (قواعد میں) نظر ثانی کرتے رہنا اور ان کو بحث کا موضوع بنائے رکھنا ہے تا کہ ان کا ارتقائی عمل جاری رہے اور اس علمی ذخیرے میں جو علمائے متقدمین ہمارے فائدے کے لیے چھوڑ گئے ہیں ‘کچھ ضروری اضافہ کیا جاسکے تو اس بات میں کچھ حرج نہیں۔ البتہ اس کام کے لیے شدید محنت اور پہلے اس (علمی ذخیرے) کے صحیح فہم کی ضرورت ہے جو وہ ہماری تحویل میں دے گئے ہیں۔ یعنی اس کام کے لیے صرف آوازِتجدید بلند کرنا کافی نہیں۔ جو آدمی کسی علم سے جاہل ہو ‘اس میں اضافہ یا کمی صحیح بنیادوں پر کیسے کر سکتا ہے!
حقیقت یہ ہے کہ علماءجو کلامی سرمایہ ہمارے سپرد کر گئے ہیں‘ اگر اس زمانے کے لوگ اس کے فہم و تحقیق کا حق ادا کریں تو وہ یہ بات جان لیں گے کہ ہمارے اسلاف نے اس علم کی تاسیس کی راہ میں بڑی مشقت اٹھائی ہے اور بڑے معرکے سر کیے ہیں ۔ متاخرین کے لیے زیادہ کام نہیں رہ گیا مگرتنقیح ِقواعد اور ان میں اضافہ جو کہ تحولِ زمانہ اور افکارو شبہاتِ جدیدہ کی وجہ سے یا اسلوبِ کلام اور ذرائع مواصلات میں تغیر کے سبب سے ضروری ہو گیا ہے۔‘‘
مندرجہ بالا ترجمہ کردہ تینوں اقتباسات بہت سے ضروری مباحث ِعقیدہ و کلام کا احاطہ کرتے ہیں‘ خاص طور پر علم الکلام کی تجدید کے مفہوم اور اس کی حاجت و اہمیت کی وضاحت کرنے والا آخری اقتباس جس میں بیان کردہ موقف وہی ہے جو ہم اوپر حضرت تھانویؒ کی کتاب ’’الانتباھات المفیدۃ‘‘ کے حوالے سے نقل کر آئے ہیں۔ مگر کیا کیا جائے کہ جس علم کی تاسیس و تشکیل کی راہ میں ہمارے اسلاف نے اس قدر ژرف نگاہی ‘نکتہ سنجی اور دقیقہ رسی سے کام لیا ہے اس کے فہم و تحقیق کا حق ادا کیے بغیر اوریہ جانے بغیر کہ اس کے اصولوں کا تعلق قرآن و سُنّت کی قطعیات سے ہے ‘ہمارے کچھ اہلِ علم اس پورے علمی سرمائے کو بس گزرے ہوئے زمانوں کی کچھ خاص ضروریات کا پورا کرنے والا ‘کچھ قدیم شبہات و مسائل کا جواب دینے والا اور حل کرنے والا سمجھ لیتے ہیں۔ اپنے اس طرزِ عمل میں وہ اصول و فروع میں تفریق کے بھی روادار نہیں ہوتے۔ آپ کے اس علمی سرمائے کے پیچھے اگر طاقت کا عنصر نہ رہا جو علم کو ایک تہذیبی قوت بنا دیتا ہے تو اس کا حل اس علم کو ہی متروک قرار دے دینا نہیں ہے۔ اس کی زد دین کے کن کن اصولوں پر پڑتی ہے ‘اس موقف کے حاملین اکثر اس سے واقف نہیں ہوتے۔ طاقت کی اپنی ایک دنیا ہے اور طاقت کے حصول کے لیے دین کے کچھ اصولوں اور قطعیات پر سمجھوتا کر لینا دین اور مسلمانوں کے علمی ‘ تہذیبی اور سیاسی غلبے کے لیے ایک عجیب متضاد طرزِ عمل ہے۔ کیا اللہ ربّ العزت نے ہم کو اس کا مکلف بھی ٹھہرایا ہے؟ یہ بھی جدیدیت کے پیدا کردہ اثرات میں سے ایک ہے کہ کامیابی اور ناکامی ‘ غلبے اور مغلوبیت کا معیار دنیا ہی کو قرار دیا جائے اور مسلمان قوم کے لیے اسلام کو قربان کر دیا جائے۔***