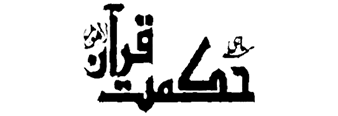(اسلام اور سائنس) سائنسی علوم کی ایک مثالی اسلامی یونیورسٹی کی ضرورت(۳) - ڈاکٹر محمد رفیع الدین
9 /اسلام اور سائنس
سائنسی علوم کی ایک مثالی اسلامی یونیورسٹی کی ضرورت(۳)ڈاکٹر محمد رفیع الدینقرآن کے فلسفہ ٔسائنس کی بنیادیں
ان مفروضات سے ظاہر ہے کہ علم کائنات کے متعلق قرآن کے فلسفہ کی بنیاد یہ ہے کہ مصنوع کاعلم بغیر صانع کے اور صانع کا علم بغیر مصنوع کے ممکن نہیں ۔دونوں ایک دوسرے کے علم کے لیے لازم و ملزوم ہیں‘ کیونکہ مصنوع صانع کے داخلی محاسن اور کمالات کا ایک خارجی مظہر ہوتا ہے‘ لہٰذا صانع کی صفات کا علم مصنوع کے علم کا ایک حصّہ ہوتا ہے۔ کائنات مصنوع اور مخلوق ہے اور خُدا اس کا صانع اور خالق ہے‘ لہٰذا کائنات کا صحیح علم خُدا کے علم کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا۔ اگر ہم خُدا کی معرفت چاہتے ہیں تو ہمیں کائنات پر _جو خُدا نے پیدا کی ہے غور و خوض کرنا پڑے گا‘ یہاں تک کہ ہم اس کے اندر خُدا کی صفاتِ خالقیت وربو بیت کاجلوہ دیکھ لیں۔ اور اگر ہم کائنات کو ٹھیک طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا مشاہدہ اور مطالعہ اس عقیدہ کی روشنی میں کرنا پڑے گا کہ خُدا اس کا خالق اور رب ہے اور اس کی صفات اس میں جلوہ افروز ہیں۔
مظاہر قدرت آیاتُ اللہ کیوں ہیں ؟
شاید یہاں یہ سوال کیا جائے گا کہ اگرمظاہر قدرت خُدا کے عقیدہ کی طرف راہ نمائی نہیں کرتے بلکہ خُدا کا عقیدہ اور مظاہر قدرت دونوں بیک وقت ایک دوسرے کی صحیح حقیقت کی طرف راہ نمائی کرتے ہیں تو پھر وہ آیاتُ اللہ کس طرح سے ہیں؟ لیکن یہ اعتراض قرآن حکیم کے طریق تعلیم کو _جو انسان کی فطرت کے حقائق پر مبنی ہے‘ نظرانداز کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ مظاہر قدرت آیاتُ اللہ اس لیے نہیں ہیں کہ وہ خود بخود کسی منکر ِخُدا کے لیے خُدا کی صفت ِخالقیت اور ربوبیت کا منطقی یا استدلالی ثبوت بہم پہنچاتے ہیں‘ بلکہ وہ آیاتُ اللہ اس لیے ہیں کہ ان کی سچی حقیقت جو علمی اور عقلی طور پر سچی ہو صرف خُدا کی خالقیت اورربوبیت کے عقیدہ سے عقلی اور علمی مطابقت رکھتی ہے۔ لیکن ان کی سچی حقیقت کو جاننے کے لیے بھی حقیقت کائنات کے صحیح تصوّر کی صورت میں ایک صحیح ذہنی پس منظر یا صحیح فلسفہ کی ضرورت ہے ‘کیونکہ اگر یہ پس منظر غلط ہو گا تو وہ ایک حجاب بن جائے گا جو ان کی سچی حقیقت کو نظروں سے اوجھل کر دے گا۔
سائنس کے لیے کسی عقیدہ کا پس منظر ضروری ہے!
حقیقت ِکائنات مادّہ ہے یا خُدا؟ ہم اس سوال کا جواب جو بھی دیں گے ہمارے پیدا کیے ہوئے سائنسی علوم اس نوعیت کے ہوں گے کہ وہ ہمارے اس جواب کے ساتھ مطابقت رکھیں گے۔ ہماری سائنس ہمارے حقیقت کائنات کے تصوّر سے الگ کوئی صورت اختیار نہیں کر سکتی۔ سائنس ہمیشہ حقیقت ِکائنات کے کسی تصوّر کے گہوارہ میں پرورش پاتی ہے اور ظاہر ہے کہ اگر یہ تصوّر صحیح ہو گا تو سائنس کی ترقی یا پرورش اپنے کمال کو پہنچے گی‘ ورنہ رُک جائے گی۔ یہی سبب ہے کہ اب یہ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ سائنس کسی فلسفیانہ پس منظر کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس وقت روس میں‘ جو سائنس کے میدان میں دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے‘ سائنس کا فلسفیانہ پس منظر مارکسزم کا عقیدہ ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کے حامی ممالک میں سائنس کا فلسفیانہ پس منظر یہ عقیدہ ہے کہ اگر خُدا کا عقیدہ سائنس کی بنیاد بنایا جائے تو سائنس کی نشوونما نہیں ہو سکتی ۔اس کے بر عکس قرآن کے نقطۂ نظر سے سائنس کا فلسفیانہ پس منظر یہ عقیدہ ہے کہ جب تک خُدا کے عقیدہ کو سائنس کی بنیاد نہ بنایا جائے‘ سائنس کی نشوونما اپنے کمال کو نہیں پہنچتی۔
قرآن کا طریق تعلیم
قرآن حکیم کا طریق تعلیم فطرت کے مطابق ہے ‘اور وہ یہ نہیں کہ وہ اپنے مخاطب کو قائل کرنے کے لیے صغریٰ اور کبریٰ کے سانچوں میں ڈھلے ہوئے منطقی دلائل دیتا ہے ‘بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے مخاطب کے وجدان کو بیدار کرتا ہے جس سے وہ براہِ راست ایک ایسی حقیقت کا احساس یا مشاہدہ کر لیتا ہے جس کی طلب اس کی فطرت میں پہلے ہی سے موجود ہوتی ہے۔
{بَلْ ہُوَ اٰیٰتٌ م بَیِّنٰتٌ فِیْ صُدُوْرِ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ط} (العنکبوت:۴۹)
’’بلکہ قرآن ایسی واضح آیات پر مشتمل ہے جو دانایانِ راز کے سینوں میں پہلے ہی سے موجود ہیں۔‘‘
جس خُدا نے قرآن نازل کیا ہے اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی محبّت انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے اور اس کی یہی فطری لاشعوری محبّت اسے خُدا کی طرف راہ نمائی کرے گی۔ جب انسان کسی جھوٹے خُدا کو مانتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا وجدان غلطی سے شہادت دیتا ہے کہ وہ سچا خُدا ہے اور وہ اس غلط وجدانی شہادت کو فی الفور قبول کرلیتا ہے تاکہ اپنی فطرت کے ایک زور دار اور ناقابل التوا تقاضا کو پورا کرے۔ عقلی یا منطقی ثبوت کی بنا پر نہ انسان اپنے جھوٹے خُدا کو مانتا ہے اور نہ سچّے خُدا کو۔ لہٰذا قرا ٓنِ حکیم منکر ِخُدا کے لیے خُدا کی ہستی اور صفات کا استدلالی یا منطقی ثبوت نہیں دیتا‘ کیونکہ سننے والے نے ایک جھوٹا خُدا پہلے ہی سے استدلالی یا منطقی ثبوت کے بغیر مان رکھا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم جب انسان کو دعوت دیتا ہے کہ مظاہر قدرت کا مشاہدہ یا مطالعہ آیاتُ اللہ کے طورپر کرو تو اس کا مقصود دراصل یہ ہوتا ہے کہ مظاہر قدرت کامشاہدہ یا مطالعہ کر کے یہ دیکھو کہ آیا یہ مظاہر تمہارے جھوٹے خُدا کی صفات کے ساتھ علمی اور عقلی مناسبت رکھتے ہیں یا اس سچّے خُدا کی صفات کے ساتھ جس کی طرف قرآن تمہیں بلاتا ہے اور جس کی محبّت اور طلب تمہاری فطرت میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر انسان مظاہر قدرت کا مطالعہ آیاتُ اللہ کے طور پر کرے گا تو یہ عمل اس کی جستجو کی منزل کا سراغ اور اس کے فطرتی جذبۂ محبّت کی تشفّی کا سامان بن جائے گا ۔قرآن جب یہ کہتا ہے انسان کا سچا مقصود‘ معبود یا مطلوب خُدا ہے تو وہ کوئی نئی بات نہیں کہتا بلکہ وہی حقیقت بیان کرتا ہے جو انسان کی فطرت میں غفلتوں کے بوجھ سے دبی ہوئی اور تعصبات کے پردوں میں چھپی ہوئی موجود ہے اور جو خود اُبھرنا اور بے نقاب ہونا چاہتی ہے۔ قرآن کائنات کے مشاہدہ اور مطالعہ کی دعوت دے کر اس مخفی اور سوئی ہوئی حقیقت کو آشکار اور بیدار کرتا ہے۔
ایک مثال سے قرآن کے فلسفہ ٔسائنس کی وضاحت
قرآن کا یہ نقطۂ نظر کہ کائنات جو مصنوع اور مخلوق ہے اور خُدا جو اس کا صانع اور خالق ہے ایک دوسرے کی روشنی میں پوری طرح سمجھے جاسکتے ہیں کس قدر معقول ہے ‘اس کا اندازہ ایک مثال سے ہو سکے گا۔
فرض کیجیے کہ کسی اور دنیا کا رہنے والا ایک سائنس دان دن کے وقت زمین پر کسی ایسی جگہ جہاں سورج نصف النہار پر ہے یکایک خلا سے نازل ہو جاتا ہے اور سب سے پہلے اسے دھوپ میں پڑا ہوا ایک برقی لیمپ دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے جس کا نچلا حصّہ لوہے کا بنا ہوا ہے‘ درمیانی حصّہ کی ساخت شیشم کی خوبصورت کامدار لکڑی سے ہے اور اوپر ایک رنگین خوبصورت فانوس کے اندر شیشے کا قمقمہ لگا ہوا ہے۔ وہ اتفاقاً لیمپ کا بٹن دباتا ہے اور لیمپ روشن ہو جاتا ہے۔ سائنس دان برقی رو اور اس کے استعمال سے آشنا نہیں اور جس دنیا سے آیا ہے وہا ں کے حالات یہ ہیں کہ نہ تو وہاں کبھی اندھیرا ہوا ہے کہ کسی لیمپ کی ضرورت ہو‘ نہ وہاں کوئی دھات موجود ہے‘ نہ لکڑی ہے اور نہ شیشہ اور نہ ربڑ اور نہ کوئی اور چیز جو ایک خوبصورت ٹیبل لیمپ کی ساخت میں کام آتی ہے۔ اب سائنس دان لیمپ کو سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے ‘کیسے وجود میں آئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لہٰذا وہ خوب غورو فکر کرکے اس کے متعلق اپنے مشاہدات کے نتائج قلمبند کرتا ہے ۔وہ سمجھتا ہے کہ ایک پتھر اور چٹان کی طرح یہ لیمپ بھی ایک قدرتی چیز ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ یہ اس کی مانندکسی سائنس دان نے کسی خاص مقصد کے لیے بنائی ہے۔ ظاہر ہے کہ سائنس دان کی سابقہ معلومات اس قدر نا کافی ہیں کہ وہ اپنی ذہانت کے باوجود فقط اپنے مشاہدات کی بنا پر لیمپ کے روشن ہونے اور بجھنے کے اسباب اور ذرائع کے متعلق‘ اس کی ساخت کے عمل اور طریق کے متعلق‘ اس کے قدرتی مقاصد اور فوائد کے متعلق اگرچہ اپنی طرف سے نہایت ہی معقول اور مدلل نظریات قائم کرے گا ‘لیکن وہ کرۂ ارض کے رہنے والے ایک تعلیم یافتہ انسان کے نزدیک نہایت ہی مضحکہ خیز ہوں گے۔
فرض کیجیے کہ لیمپ کو شروع سے لے کر آخر تک اپنے استعمال کے لیے ایک ہی شخص نے بنایا ہے اور ان خام اشیاء کی بہم رسائی سے لے کر جو اس کی ساخت میں کام آئی ہیں اس کی آخری حالت تک تخلیق کے تمام مرحلوں سے اسی نے گزار کر اسے مکمل کیا ہے۔ پھر فرض کیجیے کہ ایک فرشتۂ رحمت اس (خلائی سائنس دان )کی پریشانی کو دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کا غذ دے دیتا ہے جس میں لکھا ہے کہ یہ چیز خودبخود بنی ہوئی نہیں بلکہ ایک خاص شخص نے ایک خاص غرض کے لیے بنائی ہے۔ نیز اگرچہ اس کاغذمیں لیمپ کے متعلق براہِ راست کچھ لکھا ہوا نہیں‘کیونکہ لیمپ تو اس خلائی سائنس دان کے سامنے پڑا ہے ‘لیکن لیمپ ساز کی قابلیتوں اور خوبیوں کی ایک مفصل اور مکمل فہرست اس کے اندر موجود ہے اور یہ لکھا ہے کہ اگر تم چاہو تو اس لیمپ کے اندر لیمپ ساز کی ان قابلیتوں اور خوبیوں کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ اس کاغذ کے مطالعہ سے خلائی سائنس دان کے ذہن میں لیمپ ساز کی شخصیت کا اور اس کی صفات اور کمالات کا پورا تصوّر قائم ہو جاتا ہے۔ مثلاً اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ لیمپ بنانے والا علومِ ریاضیات‘ طبیعیات‘ کیمیا‘ زراعت اور فنونِ صنعت سے پوری طرح بہرہ ور ہے اور حسن و زیبائی کا ایک ذوق بھی رکھتا ہے ۔اسے معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ ربڑ کے درخت لگا سکتا ہے جن میں سے ایک خاص قسم کا دودھ نکلتا ہے اور وہ اس دودھ سے ربڑ تیار کر سکتا ہے یا مصنوعی ترکیبی (synthetic) ربڑ بنا سکتا ہے۔ زمین کو کھود کر خام تانبا نکال سکتا ہے‘ اسے صاف کر کے خالص تانبے کا تار بنا سکتا ہے اور اس تار کے گرد ربڑ چڑھا سکتا ہے۔ خام لوہے کو زمین سے نکال کر صاف کرسکتاہے اور اسے پگھلا کرحسب ِضرورت خوبصورت سانچوں میں ڈھال سکتا ہے۔ شیشم کے درخت لگا سکتا ہے۔ ان درختوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے اور ان ٹکڑوں سے ضرورت کی خوبصورت چیزیں بنا سکتا ہے اور ان پر نقش و نگار کھود سکتا ہے ۔مٹی اور ریت سے شیشے کے اجزاء فراہم کر سکتا ہے‘ ان اجزاء کو پگھلا کر شیشے کے برقی قمقموں کی صورت میں ڈھال سکتا ہے۔ ڈائنمو ایسی ایک پیچ دار مشین بنا کر پانی کے بہائو کی قوت سے بجلی کی رو تیار کر سکتا ہے اور وہ اس رو کی خاصیات سے پوری طرح واقف ہے۔ اسے ربڑ میں لپٹے ہو ئے تانبے کے تاروں میں کہیں سے کہیں لے جا سکتا ہے اور اسے اپنے ضبط میں رکھ سکتا ہے اور اس سے حسب ِضرورت مختلف کام لے سکتا ہے جس میں سے ایک برقی قمقمے کو روشن کرنے کا کام بھی ہے۔
ظاہر ہے کہ لیمپ ساز کی ان خوبیوں اور قابلیتوں کے علم سے اس خلائی سائنس دان کے لیے برقی ٹیبل لیمپ کا عقدہ کھل جائے گا اور وہ یہ محسوس کرے گاکہ اس کے لیے نہایت ہی آسان ہو گیا ہے کہ لیمپ کے روشن ہونے اور بجھنے کے ذرائع اور اسباب کے متعلق‘ اس کی ساخت کے عمل اور طریق کے متعلق‘ اس کے مقاصد اور فوائد کے متعلق معقول اور صحیح نظریات قائم کر سکے ۔پھر وہ یہ بھی محسوس کرے گا کہ لیمپ ساز کی صفات اور کمالات کے متعلق جو نظری واقفیت اسے بہم پہنچائی گئی ہے وہ لیمپ کے علم کی روشنی میں بہت واضح ہو گئی ہے اور ایک ٹھوس اور مرئی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اور اس کے علم کے دونوں شعبے لیمپ کا علم اور لیمپ ساز کا علم ایک دوسرے پر روشنی ڈال رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مکمل کر رہے ہیں۔ وہ محسوس کرے گا کہ لیمپ ساز کو جاننے سے خو د لیمپ کے متعلق اس کی سابقہ معلومات میں ایک ایسا اضافہ ہوا ہے جو وافر اور گرانقدر ہے اور جو اسے فقط لیمپ کو دیکھنے سے کبھی حاصل نہ ہوسکتا۔ پھر اسے صاف طور پر نظر آجائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ لیمپ‘ لیمپ ساز کی صفات اورکمالات ہی کا ایک مظہر ہے اور ان کمالات اور صفات کا علم لیمپ ہی کے علم کا ایک حصّہ ہے اور اس سے الگ نہیں۔
لیکن فرض کیا کہ خلائی سائنس دان اس فرشتہ ٔرحمت کے اصرار کے باوجود کاغذکو پڑھنے کے بغیر یہ کہہ کر پھینک دیتا ہے کہ مَیں اپنے مشاہدات میں کسی بیرونی مداخلت کو گوارا نہیں کرتا‘ تو ظاہرہے کہ اس صورت میں وہ برسوں کی ٹھوکروں کے بعد بھی لیمپ کو پوری طرح سے نہ سمجھ سکے گا اور لیمپ کی حقیقت کے متعلق اس کے مشاہدات کے نتائج ہمیشہ مضحکہ خیز رہیں گے۔
عصر ِجدید کے مغربی سائنس دان کی غلطی
یہی حال دور ِحاضر کے مغربی سائنس دان کا ہے کہ وہ کائنات کو اس کے خالق کی صفات کے علم کے بغیر فقط اپنے مشاہدات کے بل بوتے پر سمجھنا چاہتا ہے اور اپنی تحقیقات کے دوران میں اس بات سے قطع نظر کرتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے اور اس کی صفاتِ خالقیت و ربوبیت اس کی اور اس کے اندر کی ہر چیز کی ماہیت کو معیّن کرتی ہیں۔ وہ نہیں سمجھتا خُدا کی صفات کو کائنات سے الگ کرنے کے بعد اس کا سچا سائنسی مشاہدہ اور مطالعہ ممکن ہی نہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ کپڑے کا جو تعلق کپڑے کے تاروپود سے ہے وہی کائنات کا تعلق خُدا کی صفات سے ہے۔ آج بد قسمتی سے اس کا مسلمان نقال بھی ایسا ہی کر رہا ہے۔ اس کو بھی اپنے مغربی استاد کی راہ نمائی میں مظاہر قدرت (جو سائنس دان کے مشاہدہ اور مطالعہ کاموضوع ہیں) کے اندر خُدا کا نشان نہیں ملتا‘ حالانکہ اسے بتایا گیا تھا کہ مظاہر ِقدرت کے اندر خُدا کی صفات ِخالقیت و ربوبیت اور کارسازی ‘ حکمت اور قدرت سموئی ہوئی ہیں۔ اور اگرمظاہر قدرت کی کوئی حیثیت ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ آیاتُ اللہ ہیں۔ ان کی ابتدا اور انتہا خُدا ہے اور ان کا ظاہر اور باطن خُدا ہے۔
{ہُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاہِرُ وَالْبَاطِنُ ج } (الحدید:۳)
’’خُدا ہی اس کائنات کی ابتدا اور انتہا اور ظاہر اور باطن ہے۔‘‘
قدیم سائنس دان کا زاویۂ نگاہ
لیکن ان مسلمان سائنس دانوں کا زاویۂ نگاہ جنہوں نے سائنسی طریق تحقیق ایجاد کیا تھا اور سائنسی علوم کی بنیاد رکھی تھی اور جو آج کے مسلمان سائنس دان کے مغربی استادوںکے بھی استاد تھے‘ آج کے مسلمان سائنس دان سے مختلف تھا۔ وہ خُدا کو جو کائنات کا صانع اور خالق ہے اور کائنات کو جو اس کی مصنوع اور مخلوق ہے ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے تھے۔ ان کے مشاہدہ و مطالعۂ قدرت میں اورسائنسی علوم کی تحقیق اور تدوین میں خُدا کی خالقیت اور ربوبیت کا عقیدہ بطور مدار و محور کے تھا۔ وہ دل سے مسلمان تھے ‘لہٰذا ان کا خیال یہ تھا کہ جس طرح سے خد اروحِ روانِ کائنات ہے اسی طرح سے وہ علم کائنات یا سائنس کی روحِ رواں بھی ہے۔ وہ کائنات کا مطالعہ اس لیے کرتے تھے کہ کائنات میں خُدا کے تخلیقی اعمال کو سمجھ کر خد ا کی صفات کو بہتر طریق سے جانیں اور پہچانیں۔ اور ان کے نزدیک خُدا کا عقیدہ ایک روشنی تھاجس کے بغیر یہ مطالعہ ناممکن بھی تھا اور بے معنی اور بے سود بھی۔ انہوں نے دورِ حاضر کے بعض مسلمان سائنس دانوں کی طرح خُدا کے عقیدہ کو اپنے سائنسی تجزیہ اور تحقیق کے لیے زیر غور رکھا ہوا نہیں تھا کہ جب سائنس اسے قبول کر لے گی تو وہ بھی اسے قبول کر لیں گے‘بلکہ ان کے نزدیک سائنسی تحقیق کے لیے اس عقیدے سے ہٹ کر نہ کوئی راستہ تھا اور نہ منزل۔ ان کے نزدیک خُدا کی وحی کا عطا کیا ہوا علم ان کے حواس کے علم سے کہیں زیادہ بلند اور زیادہ یقینی تھا۔ لہٰذا ان کے دل میں اس بات کا خیال تک بھی نہ آسکتا تھا کہ علم حواس کسی درجہ میں بھی علم وحی کا محک و معیار قرار پا سکتا ہے یا علم وحی کی تشریح اور تفسیر کے علاوہ کسی اور حیثیت سے اپنا کوئی مقام یا وزن رکھ سکتا ہے۔
سارٹن کا عذر
یہی وجہ ہے کہ ’’تاریخ سائنس کا تعارف‘‘(Introduction to the History of Sciecne) کا مغربی مصنف سارٹن (Sarton) اس بات پر مجبور ہوا ہے کہ ہر دور کے مسلمان سائنس دانوں کے سائنسی کارناموں کا ذکر کرتے وقت ان کے مذہبی معتقدات کا ذکر بھی کرے۔ تاریخ سائنس کے مصنف کی حیثیت سے اس کا یہ اقدام علمی لادینیت اور افتراقِ مذہب و سائنس کے اس دور میں یقیناً مشکل سے ہی سمجھ میں آسکتا تھا‘ لہٰذا وہ اپنے قارئین کو مطمئن کرنے کے لیے اس کا عذر پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے:
’’وہ مسلمان بھی جو قرآن کو مخلوق سمجھتے تھے اس بات پر متفق تھے کہ وہ خود خُدا کا کلام ہے‘ لہٰذا ان کا خیال تھا کہ وہ علم جو ہم محض اپنے غلط بین حواس یا اپنی محدود ذہنی قوتوں کے ذریعہ سے حاصل کرتے ہیں لازماً ناقابل اعتماد اور کمزور ہے اور قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ قطعی طور پر صحیح اور یقینی ہے۔ مَیں پھر پوچھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کی سائنس کو اس وقت تک صحیح طور پر کیسے سمجھ سکتے ہیں جب تک ہم اس بات کو پوری طرح سے نہ سمجھ لیں کہ وہ قرآن کے محور کے گرد گھومتی ہے. . .. . . .‘‘
’’قرونِ وسطیٰ میں (جب سائنس کے میدان میں صرف مسلمان ہی پیش پیش تھے) یہ نقطۂ نظر عام تھا کہ مذہب کی عقلی توجیہ نہ صرف سائنس کا مدارومحور ہے بلکہ مذہب کی قوت بھی ہے ‘لہٰذا مذہب اور سائنس ناقابل تفریق تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ایک کو دوسرے کے بغیر سمجھ نہیں سکتے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہماری یہ تحقیق منصفانہ نہیں ہو گی جب تک کہ ہم اس کی بنیاد ’’علم مثبت‘‘ کی اپنی تعریف پر رکھنے کی بجائے خود ان لوگوں کی تعریف پر نہ رکھیں جن کی سائنس کی تاریخ ہم لکھنا چاہتے ہیں۔ اب جیساکہ مَیں پہلے کہہ چکا ہوں ان لوگوں کی نگاہ میں مذہب کی عقلی توجیہ نہ صرف علم مثبت تھا بلکہ علم مثبت سے بھی کوئی بالاتر علم تھا۔ ان لوگوں کے فکر کا مرکز (یعنی خُدا کا عقیدہ) ہمارے مرکز ِفکر سے یکسر مختلف تھا۔‘‘
سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمان ہی سائنسی طریق تحقیق کے موجد تھے اور سائنسی علوم کی بنیاد بھی انہوں نے ہی رکھی تھی تو پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے سائنس کے میدان میں نہ صرف اپنی قائدانہ حیثیت کو کھو دیا بلکہ عیسائی دنیا کے ہم دوش بھی نہ رہے اور آخر کار سائنس ہی میں ان کے نقال اور مقلد بن گئے۔ اور پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ عیسائی دنیا نے خُدا کے عقیدے کو جو مسلمانوں کی قیادتِ سائنس کے زمانے میں سائنسی علوم کا مدارومحور تھا ‘نہ صرف سائنسی علوم سے الگ کر دیا بلکہ اسے سائنس سے منافی خیال کرنے لگے اور آج مسلمان بھی ان کی نقل اور تقلید میں ایسا ہی کر رہے ہیں۔
اصل بات یہ ہے کہ کسی قوم کی علمی ترقیوں کاباعث اس کی پُر امن اور آزادانہ جستجو ئے صداقت ہے۔ ہر قوم علم کے میدان میں صرف اسی وقت تک ترقی کر سکتی ہے جب تک وہ صداقت کی جستجو کے لیے یعنی اس صداقت کی جستجو کے لیے جسے وہ خود صداقت سمجھتی ہے‘ آزاد ہو اور اس کی یہ آزادی امن وامان سے ہمکنار ہو۔ جونہی اس کی یہ آزادی ختم ہو جاتی ہے یا خطرہ میںپڑ جاتی ہے ‘اس کی جستجوئے صداقت اور تحقیق علمی کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں‘ کیونکہ ایسی حالت میں یاتو وہ کسی دوسری قوم کی غلام بن جاتی ہے جس سے اس کی زندگی اس صداقت کی جستجو کے لیے وقف ہوجاتی ہے جسے یہ دوسری قوم صداقت سمجھتی ہے ‘اور یا پھر وہ اپنی آزادی کھو دینے کی فکر میں مبتلا ہوجاتی ہے اور اس کی حفاظت کی تگ و دو میں لگ جاتی ہے۔ غرناطہ اور بغداد کی تباہی نے مسلمانوں کی صدیوں کی علمی تحقیق و تجسّس کی روایات کو ختم کر دیا تھا اور اس کے بعد ان کو پھر پُر امن آزادی کا ایسا طویل دور نصیب نہ ہو سکا جس سے وہ اس قابل ہو جاتے کہ ان روایات کو از سر ِنو اپنی پوری شان وشوکت کے ساتھ زندہ کر سکیں۔
مغرب میں خُدا اور سائنس کے افتراق کا بنیادی سبب عیسائیت کی تعلیم ہے
یورپ میں سائنس اور عقیدۂ خد اکے الگ الگ ہو جانے کی بڑی اور بنیادی وجہ عیسائیت کی تعلیم ہے۔ جب سائنس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر عیسائیوں کے ہاتھوں میں آئی تو کچھ عرصے کے لیے خُدا کا عقیدہ بدستور سائنس کا مرکز بنا رہا ‘لیکن چونکہ دین اور دنیا کا اتحاد سائنس کے دائرہ میں بلکہ انسانی زندگی کے کسی دائرہ میں بھی عیسائیت کی سر شت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا‘ اس لیے ایسا وقت آنا ضروری تھا جب عیسائی دنیا سائنس کو خُدا کے عقیدہ سے اور خُدا کے عقیدہ کو سائنس سے الگ کر دیتی۔ عیسائیت میں دین اور دنیا ایک دوسرے سے الگ تھلگ بلکہ ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ جس طرح سے دینی سعادتیں ترکِ دنیا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتیں اسی طرح دنیوی کامیابیاں بھی مذہب کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ حضرت مسیحؑ نے یہ فرماکر کہ ’’جو کچھ قیصر کا ہے وہ قیصر کو اورجو کچھ خُدا کا ہے وہ خُدا کو دے دو‘‘ نظری طور پر دین کو دنیا سے الگ کر دیا تھا اور حضرت مسیحؑکی ساری عملی زندگی بھی دین اور دنیا کے اس افتراق کی آئینہ دار تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مسیحؑ جو خُدا کے سچّے رسول تھے‘ ایک خاص مقصد کے لیے آئے تھے اور وہ یہ تھا کہ دین موسوی کے خاص خاص پہلوؤں پر زور دیں اور بنی اسرائیل کو ریاکاری سے ‘جو ان کی فطرتِ ثانیہ بن گئی تھی ‘نجات دلاکر اخلاص اور للہیت پر قائم کریں۔اپنی پوری عملی زندگی میں دین اور دنیا کو جمع کر نا ان کا کام نہیں تھا‘کیونکہ یہ عظمت اپنے وقت پر خاتم النّبیینﷺ کے حصّہ میں آنے والی تھی۔
ریورینڈ مارٹن ڈی -آر کی (Rev.Martin D' Arcy) اپنی کتاب’’اشتراکیت اور عیسائیت‘‘ (Communism and Christanity)میں سچ کہتا ہے:
’’لیکن ہم اس بات کو جتنی دفعہ باربارکہیں کم ہے کہ عیسائیت اس لیے وجود میں نہیں آئی تھی کہ کسی قوم یا کسی اعلیٰ قوم کو دنیوی فارغ البالی کا راستہ بتائے۔ یہی بنی اسرائیل کی غلطی تھی اور جب لوگوں نے چاہا کہ حضرت مسیح کو بادشاہ بنا دیں تو وہ ان سے بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔‘‘
عیسائیت میں دین اور دنیا کی علیحدگی ایک اساسی عقیدہ ہے
عیسائیت کی تعلیم یہ ہے کہ انسان اگلی دنیا کی راحتیں اس دنیا کی راحتوں کو ترک کیے بغیر حاصل نہیں کرسکتا۔ مذہب اور سائنس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں‘ کیونکہ مذہب انسان کی دنیوی زندگی سے کوئی سروکار نہیں رکھتا‘ اس کا مقصد انسان کی اُخروی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اس کے بر عکس علم کائنات اور سائنس اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کام آتے ہیں۔ مذہب غیرعقلی اعتقادات کا ایک مجموعہ ہے اور ایک ایسی دنیا کے متعلق رائے زنی کرتا ہے جو ماورائے حواس ہے‘ لیکن سائنس کے نتائج عقل ‘ مشاہدہ اور تجربہ پر مبنی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم خُدا کے عقیدہ کو اپنی علمی بحثوں میں جگہ دیں گے تو ہماری علمی بحثیں عقلیت کے اعتبار سے گر جائیں گی اور مذہب کے دائرہ میں‘ جو تعصّب اور نامعقولیت اور عقل اور علم کی محکومی پر زور دیتا ہے‘ داخل ہو جائیں گے۔ دیکھ لیجیے کہ یہ نقطۂ نظر اسلام کے نقطۂ نظر سے‘ جو کائنات پر غور وفکر کرنے اور اپنے قوائے دید و شنیداور فہم و فراست کو کام میں لانے پر زور دیتا ہے‘ کس قدر مختلف ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ عیسائیت کے بر عکس اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مظاہر قدرت خُدا کی ہستی اور صفات کی نشانیاں ہیں‘ خوب غور سے ان کا مشاہدہ اور مطالعہ کرو۔ جو لوگ آنکھوں سے دیکھتے نہیں‘ کانوں سے سنتے نہیں اور دل سے سوچتے نہیں ان سے باز پرس کی جائے گی اور ان کی سزا دوزخ ہے۔
کلیسا کی سائنس دشمنی اور عیسائیت کی مذہبی عدالتوں کے مظالم
عیسائیت میں اعتقاد‘ مشاہدہ اور مطالعہ ٔ قدرت سے بے تعلق ہے بلکہ اس کا مخالف ہے اور اسلام میں اعتقاد ‘ مشاہدہ اور مطالعہ قدرت کے بغیر ممکن نہیں۔ عیسائیت کی اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ کلیسا نے سائنسی فکر کو جب بھی وہ اُبھرنے لگا بزورِتمام دبا دینے کی کوشش کی۔ عیسائیوں کی مذہبی عدالتوں نے سائنس دانوں پر ایسے ظلم ڈھائے کہ یہ بات مسلّم ہو گئی کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے اور سائنس کو اگر ترقی کرنا ہے تو اسے ہر حالت میں مذہب سے الگ رہنا چاہیے۔ سائنس دانوں کے دلوں میں یہ خوف راسخ ہو گیا کہ اگر انہوں نے خُدا کو سائنس سے اور سائنس کو خُدا سے جوڑنے کی کوشش کی تو وہ پھر مذہبی اداروں اور عدالتوں کے محاسبہ کی زد میں آجائیں گے اور وہ اور اُن کی سائنس دونوں ختم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یورپ میں پے درپے ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے خُدا اور سائنس کے افتراق کو جسے عیسائیت نے جنم دیا تھا‘ اور محکم کر دیا۔ کلیسا اور ریاست کے جھگڑوں نے اتنا طول کھینچا اور اتنی شدّت اختیار کی کہ بالآخر دونوں کو ایک دوسرے سے الگ ہونا پڑا اور عیسائیت کی تعلیم کے عین مطابق یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ مذہب کا سیاست سے کوئی علاقہ نہیں۔ لیکن جب مذہب ایک دفعہ سیاست سے الگ کر دیا جائے تو پھر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ فرد یا جماعت کی زندگی کے کسی اہم شعبہ پر بھی اپنی گرفت قائم رکھ سکے۔ نتیجہ یہ ہو ا کہ نہ صر ف فرد اور جماعت کی سیاسی زندگی مذہب سے الگ ہو گئی بلکہ ان کی قانونی‘ سماجی‘ اقتصادی‘ فوجی اور تعلیمی و علمی زندگی کو بھی مذہب سے کوئی تعلق نہ رہا۔ کیسے ممکن تھا کہ مذہب جو ریاست کے کاروبار سے الگ کر دیا گیا تھا پھر اس کاروبار میں اسکول ‘ کالج اور یونیورسٹی کے چور دروازوں سے داخل کر لیا جاتا۔ سائنس اور علم سے خُدا کے عقیدے کا اخراج جو اس طرح سے عمل میں آیا اگرچہ عیسائیت کے مزاج کاایک تقاضا تھا جو بالآخر ایک سیاسی حادثہ کے نتیجہ کے طور پر رونما ہوا تھا‘ تاہم کچھ عرصہ کے بعد یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ خود سائنس اور علم ہی کا ایک تقاضا ہے۔
اُنیسویں صدی کی طبیعیات کی غلط فہمی
اس غلط فہمی کے ظہور کے لیے عیسائیت کی تعلیم اور کلیسا اور ریاست کی علیحدگی نے حالات پہلے ہی سازگار کررکھے تھے ‘لیکن جن خاص اسباب نے اسے جنم دیا ان میں سے ایک مؤثر سبب اُنیسویں صدی کے ماہرین طبیعیات کا مادّی نظریہ تھا جس کے مطابق یہ سمجھاجاتا تھا کہ مادّہ کائنات کی آخری حقیقت ہے اور کائنات ایک مادّی مشین ہے جو اپنے قوانین سے خود بخود عمل کرتی ہے اور جس کے عمل میں خُدا کا کوئی دخل نہیں۔ لہٰذا اس صدی میں یہ خیال اور راسخ ہو گیا کہ درحقیقت سائنس کا خُدا یا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔
ڈارونزم کا زہر اور اس کی عالمگیر خریداری
لیکن جس شخص نے خُدا اور مذہب کے خلاف عیسائیت کی علمی دنیا کے تعصّب کو آخر کار ایک علمی اور عقلی نظریہ کا مقام اور ایک سائنسی حقیقت کا درجہ دیا وہ ایک ماہر حیاتیات چارلس ڈارون تھا جس نے سبب ارتقا کا ایک نظریہ پیش کیا ہے۔ ڈارون نے انیسویں صدی کی علمی اور عقلی فضا میں پر ورش پائی تھی اور وہ بحیثیت ایک سائنس دان کے اس دور کی جامد اور متحجّر میکانیت اور مادیت کی پیداوار تھا جس میں عیسائیت کے خلاف سائنس دانوں کا ردّ ِعمل اپنی پوری شدّت پر تھا۔ لہٰذا اس نے نوعِ انسانی کے ظہور کا سبب یہ بتایا کہ کائنات میں ایسی قوتیں کام کررہی ہیں جن کا کوئی مقصد یا مدّعا نہیں اور جن کو اپنے عمل کے نتائج اور عواقب سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ان قوتوں کو اس نے کشمکش حیات‘ قدرتی انتخاب اور بقائے اَصلح کے دلفریب نام دیے۔ اس کے نتائج میں سے ایک یہ ہے کہ یہ محض اتفاق ہے کہ انسان عقل و خرد‘ ہوش وتمیز اور ضمیر و تخیل ایسی خصوصیات کا مالک بن گیا ہے اور ان کی وجہ سے مذہب ‘اخلاق اور سیاست اور تعلیم اور قانون اور جستجو ئے علم و فن ایسے مشاغل میں مصروف ہو سکتا ہے۔ آج جو انسان ہے بالکل ممکن تھا کہ وہ انسان نہ ہوتابلکہ گندی نالیوں میں رینگنے والا ایک کریہ المنظر جاندار ہوتا۔ اگرچہ یہ نظریہ بالخصوص حیاتیاتی ارتقا کے اسباب سے تعلق رکھتا تھا ‘تاہم اس کے نتائج تمام مادّی‘ حیاتیاتی اور انسانی علوم پر بھی اثر انداز ہوتے تھے۔ ڈارون نے کہا تھا کہ میرا نظریہ بالقوہ ایک پورا فلسفہ ٔکائنات ہے اور اس کا یہ کہنا صحیح تھا۔ ڈارون کا نظریہ ہر چیز کی تشریح اس طرح سے کر سکتا ہے کہ اگر کوئی روحانی یا آسمانی قوتیں اس کائنات میں کارفرما ہیں تو پھر بھی کائنات کے حقائق کی تشریح کے لیے ان کے ذکر کی کہیں ضرورت پیش نہیں آتی۔ لہٰذا یہ نظریہ انیسویں صدی کی ذہنی اور علمی فضا کے ساتھ‘ جو مادّیت پسندی اور مذہب دشمنی سے معمور تھی‘ خوب ہی مطابقت رکھتا تھا۔ کوئی تعجب نہیں کہ اسے ڈارون کے عہد کی علمی دنیا نے بالعموم قبول کر لیا اور یہ اس کے بعد سے لے کر آج تک بھی تمام سائنسی علوم کی ترقیوں کی نوعیت پر گہرے اثرات پیدا کرتا چلا آرہا ہے۔ یہ اسی نظریہ کی نحوست کا اثر ہے کہ آج یہ سمجھا جا رہاہے کہ ہر مظہر قدرت جو طبیعیاتی یا حیاتیاتی یا انسانی دنیا سے تعلق رکھتا ہے عمل ِارتقا کا ایک اتفاقی نتیجہ یہ ہے اور ہم اس کے ماضی کے قریبی حالات اور واقعات سے اس کی مکمل اور معقول تشریح کر سکتے ہیں۔
کور چشمی کی ایک بیّن مثال
ڈارون ایک پکا عیسائی تھا۔ اس کے باوجود اسے عمل ارتقا کے اندر‘ جو خالق ِکائنات کی ربّ العالمینی کا ایک شاندار اور یقین افروز مظہر ہے‘ خُدا کیوں نظر نہیں آیا اور کیوں اس کی بجائے بے شعور اور بے مقصد مادّی اور میکانکی قوتیں کام کرتی ہوئی نظر آئیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دل خُدا کے عقیدہ کے خلاف ایک علمی قسم کے تعصّب سے معمور تھا اور یہ تعصّب اس اروپائی نظریۂ علم کی پیداوار تھا جو یورپ کے مخصوص حالات و واقعات اور خود تعلیم عیسائیت کے زیر اثر فروغ پاکر انیسویں صدی میں عام ہو چکا تھا کہ خد اکے عقیدہ کو سائنس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈارون کے زمانہ میں عیسائی دنیا کے سائنس دان اس پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے اسے ایک نعمت عظمیٰ سمجھ کر قبول کر لیا۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے اور کتنی بڑی کورچشمی ہے جسے سائنس کے نام پر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کائنا ت میں عمل ارتقا سے انسان جیسی ایک محیر العقول ہستی کا ظہور محض اتفاق ہے اور کسی خالق ِکائنات ربّ کی ربوبیت کی کار فرمائی نہیں! سچ یہ ہے کہ جب دل اندھے ہوں تو محض آنکھوں سے دیکھنے سے کائنات کا علم حاصل نہیں ہوسکتا۔
{فَاِنَّھَا لَاتَعْمَی الْاَبْصَارُ وَ لٰکِنْ تَعْمَی الْقُلُوْبُ الَّتِیْ فِی الصُّدُوْرِ(۴۶)} (الحج)
’’بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں لیکن دل جو سینوں میں ہیں اندھے ہوجاتے ہیں۔‘‘
خد اکے عقیدہ کے خلاف عیسائی مغرب کے سائنس دانوں کا علمی تعصّب لاعلاج ہے
وہ عملی اسباب جنہوں نے یورپ میں سائنسی لادینیت کے نا معقول عقیدہ کو ایک علمی تصوّر کا مقام دیا تھا‘ قریباً ختم ہو چکے ہیں۔ مثلاً اب بعض چوٹی کے ماہرین طبیعیات نے انیسویں صدی کے طبیعیات کو ردّ کرکے یہ بتا یا ہے کہ حقیقت کائنات مادّہ نہیں‘ بلکہ شعور ہے اور ڈارون کے نظریۂ ارتقا کو برگساں (Bergson)اور ڈریش (Driesch) ایسے نامور ماہرین حیاتیات نے محل نظر ٹھہراکر اس کے بالمقابل نہایت ہی معقول اور مدلل نظریات پیش کیے ہیں جن کا ماحصل یہ ہے کہ ارتقا کا باعث کو ئی باشعور قوت ہے جو اپنے مقاصد کے لیے کائنات میں عمل پیرا ہے۔ تاہم خُدا کے عقیدہ کے علمی مقام کے خلاف جس تعصّب کا بیج گزشتہ صدیوں میں یورپ میں بویا گیا تھا اس کی بیخ کنی ابھی تک نہیں ہو سکی ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور عیسائیت کی سرشت میں ہیں جس کا کائناتی نقطۂ نظر اہل یورپ کی زندگی میں سمویا ہو اہے ‘لہٰذا اہل یورپ کا اس سے نجات پانا بہت مشکل ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ شعور کو حقیقت ِکائنات کہنے والے مغربی ماہرین طبیعیات اور ماہرین حیاتیات بھی اس کو خالق ِ کائنات خُدا کہنے سے گریز کرتے ہیں۔ (جاری ہے)
***