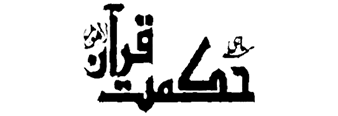(تعلیم و تعلم) مباحث ِعقیدہ(۹) - مؤمن محمود
9 /مباحث ِعقیدہ(۹)
مؤمن محمود
امام بیہقی علیہ الرحمہ کی کتاب ’’الاعتقاد والھدایۃ الٰی سبیل الرشاد‘‘ کامطالعہ اللہ کے فضل سے جاری ہے۔ تیسرا باب جہاں سے امام صاحب نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اَسماء وصفات کے بیان کا آغاز فرمایاوہاں سے ہم نے اس کتاب کی ترتیب کو پیش نظر نہیں رکھا‘بلکہ آگے آنے والے تقریباً پانچ یادس ابواب میں جو اسماء وصفات کے مباحث ہیں ان سب مضامین کو اکٹھا کرلیا ہے۔امام بیہقی ؒ چوتھی صدی کے ہیںاس لیےان کے ہاں وہ ترتیب نہیں ہے جو متاخرین کے ہاں ہے۔متاخرین نے صفات کو چار یاپانچ انواع میں تقسیم کیاہے‘جن کا تذکرہ ہم کرچکے ہیں۔ ہم نے جس ترتیب کواختیار کیاہے یہ امام بیہقی ؒ کی نہیں ہے بلکہ بعد میں آنے والے علماء ِ عقیدہ یا متکلمین کی ہے ۔
صفاتِ معانی
اب ہم صفاتِ معانی کے متعلق بحث کاآغاز کرتے ہیں ۔ان کو صفاتِ معانی اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں کچھ معانی کا ذاتِ خداوندی کے لیے اثبات کیا جاتاہے ۔ پچھلی صفات جن کو ہم نے صفاتِ سلبیہ کہاان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر کسی صفت کا اضافہ مقصود نہیں تھابلکہ نقص کی نفی تھی ۔یعنی جب ہم نے کہا کہ وہ باقی ہے یا قدیم ہے تو قدیم کوئی ایسی صفت نہیں ہے جوذات پر اضافی ہے‘ بلکہ ہماری مراد یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک نقص کی نفی کردی جائے کہ اللہ کی ذات کی ابتدا نہیں ہے ۔قدیم کہنے کا مطلب ہے:لابدایۃلہ۔جب کہ باقی کہنے کا مطلب ہے:لانھایۃلہ۔ مخالفۃ للحوادث کامطلب بھی نفی ہے: لیس کمثلہٖ شیءٌ۔اور صمدیت اور قیام بالنفس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محتاج نہیں ہیں ۔اب ہم جو صفاتِ معانی پڑھنے جارہے ہیں ان کو صفاتِ ذاتیہ اور صفاتِ وجودیہ بھی کہتے ہیں ۔یعنی آپ عقیدے کی کتابوں میں مختلف اصطلاحات دیکھیں گے کہ یہ صفاتِ معانی ‘ صفاتِ ذاتیہ ‘یا صفاتِ وجودیہ ہیں‘ کیونکہ وہ سلبیہ تھیں‘ ان کے برعکس یہ وجودیہ ہیں۔اس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ایک وجودی معنیٰ کا اضافہ کررہے ہیں۔ یعنی اللہ کی ذات ہے اور وہ علیم ہے ‘ اس میں صفت علم ہے ۔اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے اور وہ قدیر ہے‘ اس میں صفت ِقدر ت ہے ۔اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے اور وہ متکلم ہے‘ اس میں صفت کلام ہے ۔اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے اور وہ سمیع ہے ‘ اس میں صفت ِسماعت ہے ۔ اسی طرح اس میں صفت ِبصارت ‘ حیات‘ارادہ اور صفت ِتکوین ہے۔ یہ جوسات یا آٹھ صفات ہیں ان کو صفات ِمعنی کہتے ہیں ۔ اہل سُنّت میں صفت ِتکوین کے متعلق اختلاف ہے ۔اہل ِسُنّت میں احناف کاگروہ جن کو’’ماتریدیہ‘‘ کہتے ہیں‘ان کے نزدیک صفت ِتکوین بھی ایک صفت ہے اور’’اشاعرہ‘‘ جوعموماً شافعی اور مالکی ہوتے ہیںوہ کہتے ہیں کہ صفت ِتکوین کی حاجت نہیں ہے ‘اور جن علماء نے اہل ِسُنّت کے درمیان ان مسائل اختلافیہ پرکتابیں لکھی ہیںان کی رائے ہے کہ یہ مسئلہ یااختلاف لفظی ہے ‘ معنوی اورحقیقی اختلاف نہیں ہے۔یعنی لفظی اختلاف وہ ہوتاہے جس میں اگرلفظ کو چھوڑ کر معنی پرگفتگو کی جائے تواختلاف رفع ہوجاتا ہے ۔اور اختلافِ معنوی وہ ہوتاہے کہ جس میں معنیٰ پر گفتگو کرنے سے بھی اختلاف رفع نہیں ہوتا۔تویہ اختلاف لفظی ہے معنوی نہیں ہے۔
انکارِ صفات(جہمیہ)
جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پرصفات ِمعنویہ ’’اضافی صفات‘‘ ہیں تواس لفظ سے گھبرا کے کچھ فرقوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا۔جن میں سب سے بڑا گروہ جہمیہ کاہے ‘ جس کاوجود تبع تابعین میں ہوا ۔ اس کے بانی کا نام تھا:جہم ابن صفوان‘ جس کی نسبت سے اس گروہ کو جہمیہ کہہ دیا جاتا ہے ۔انہو ں نے کہا کہ اللہ کی ذات توواحد ہے ‘احد ہے ‘اگر تم اس پر کسی صفت کا اضافہ کرو گے تویہ تو’’تعددِ قدماء‘‘ ہوگیا۔یعنی ایک سے زیادہ قدیم ہوگئے ۔اور ایک سے زیادہ قدیم توشرک ہے ۔لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہوسکتیں۔تم نے کہا :اللہ ہے اور صفت ِقدر ت ہے اورصفت ِقدرت ہمیشہ سے ہے ‘تو کیاصفت ِقدرت خدا ہے ؟نہیں !صفت ایک الگ حیثیت رکھتی ہے ۔توصفت ِقدرت خدانہ ہوئی توخدا کا غیرہوئی اور خدا کا غیر ہوئی اور قدیم بھی ہوئی توخدا کے غیر کاقدم لازم آگیا۔لہٰذا ہم صفات کا انکارکرتے ہیں۔ یہ جہمیہ کاعقیدہ تھا۔انہوں نے اسماء کا بھی انکار کیااور صفات کا بھی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ نہ ہم اللہ کوعلیم کہیں گے نہ یہ کہیں گے کہ وہ ذوعلم ہے۔علیم اسم ہے او ر ذوعلم اس کی صفت ہے‘انہوں نے دونوں کا انکا رکردیا۔اس گروہ سے متعلق بہت سے علماءِسلف نے یہ بیان کیا کہ یہ گروہ مسلمان نہیں رہا ۔ان کے کچھ او ربھی بہت غالی قسم کے عقائد تھے جن سے قرآن کی واضح نصوص کا انکا رہو رہاتھا ۔قرآن مجید میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو علیم اورقدیر کہا‘بلکہ واضح طو رپر کہاکہ اَنْزَلَہٗ بِعِلْمِہٖ۔تویہاں صرف علیم نہیں کہا جارہا ہے بلکہ اللہ کے لیے صفت علم کا اثبات ہورہا ہے ۔تو یہ لوگ بہت دور نکل گئے۔ اگرچہ اختلاف رہا ہے لیکن بہت سے علماء نے ان کی تکفیرکی ۔
دوسرا بڑا گروہ معتزلہ کاہے ‘جنہوں نے اسماء کا انکا رنہیں کیااور اسی وجہ سے ان کی تکفیر نہیں ہوئی۔ جہمیہ کی تکفیر اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اسماء اورصفات دونوں کا انکا رکیا۔معتزلہ نے بھی یہی دلیل اختیار کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات ماننے کے نتیجے میں ترکب اور تعددِ قدماء لازم آتا ہے ۔یہ دو اصطلاحات ان کی ہیں ۔تعددِ قدماء کہ ایک سے زیادہ قدیم لازم آتے ہیں ۔ترکب کامطلب ہے کہ اللہ کی ذات تواحد ہے‘اللہ کی ذا ت میں کوئی ترکیب نہیں ہوسکتی کہ مختلف چیزوں سے مل کر بنی ہو۔جب آپ کہتے ہیں صفت اور ہے ذات اور ہے تویہاں توترکب لازم آگیا۔یعنی ایک چیزکوہم تقسیم کرسکتے ہیں اور جو مقسم ہووہ خدا نہیں ہوسکتا ‘وہ توحادث ہے ۔لہٰذا اگر تم صفت مانو گے تواللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حادث ماننا پڑے گا‘کیونکہ وہ مرکب وجو د ہوجائے گااور ساتھ تعددِ قدماء بھی لازم آئے گا۔یہ لوگ قرآن کا صریحاًا نکار نہیں کرتے تھے ۔ معتزلہ اہل سُنّت میں نہیں تھے لیکن ان کی حسنات بھی بہت ہیں۔انہوںنے کہا کہ ہم اسماء کا انکار نہیں کررہے کیونکہ قرآن میں واضح طو رپربہت سے اسماء وارد ہوئے ہیں۔مثلاً عزیز ‘حکیم‘قدیر‘علیم‘سمیع‘بصیر وغیرہ۔ہم اسماء مانتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے :علیم بعلمہ بلکہ علیم بذاتہ‘ قدیربذاتہ۔ہم قدیر کے لفظ کا اثبات کررہے ہیں لیکن ہم کوئی صفت قدرت کا اثبات نہیں کررہے‘ بلکہ اللہ کی ذات ہی کااثبات کرتے ہیں‘اور صفات عین ذات ہیں۔
روایتی کلامی مباحث عبث نہیں تھے
کئی دفعہ اپنی روایت کے متعلق ہمارا طرزِعمل یہ ہوجاتا ہے کہ کچھ مباحث ایسے ہیں جن میں ہمارے علماء یامتکلمین بلاوجہ پڑے رہے جبکہ اس کی ضرورت چنداں نہ تھی۔ اس ضمن میں ہم صفات کی عینیت اورغیریت سے متعلق چند اشعار بھی پڑھ ڈالتے ہیں(ع ’’ہیں صفاتِ ذاتِ حق حق سے جدا یا عین ذات!‘‘)۔جب ہم یہ بات کہتے ہیں توہربڑے آدمی پر یہ اعتراض لازم آتا ہے۔یعنی ہمارے جتنے بھی علماء ہیں ‘اور میں نے اپنے ناقص مطالعے میں کوئی ایسا بڑا عالم اور متکلم نہیں دیکھاجس نے یہ بحث نہ کی ہوکہ صفات عین ذات ہیںیاغیر ذات‘ اور معتزلہ کے موقف کا ردّ نہ کیا ہو‘اور اہل ِسُنّت کا موقف پیش نہ کیا ہوکہ صفت نہ عین ذا ت ہے نہ غیر ذا ت ہے ۔ اس پرلوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ پتا نہیں یہ کس قسم کی بات کردی اور یہ کیسے ہوسکتا کہ ایک شے نہ عین ہو نہ غیر ہو؟حالانکہ وہ یا عین ہوگی یاغیرہوگی۔اس کی وضاحت بھی مَیں مختصراً کردیتا ہوں ۔لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جومعتزلہ کا موقف ہے جس میں صفت عین ذات ہوگئی اور اضافی صفاتِ وجودیہ کاانکار کردیاگیا‘اس کوہمارے علماء اہل ِسُنّت نے تسلیم نہیں کیا۔ انہوںنے کہا کہ اس سے قرآن مجید کی بہت سی نصوص کاانکار ہوتا ہے اگرچہ معتزلہ نے اس کی تاویل کرلی۔لہٰذا کفر کا حکم نہیں لگایاگیا‘لیکن بہرحال یہ موقف بدعتی تھا۔علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے صرف اسم ’’علیم‘‘ کااثبات نہیں کیابلکہ صفت ِعلم کا بھی اثبات کیاہے۔جب فرمادیا کہ {وَلَایُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِہٖ} عِلْمِہٖ مضاف ‘مضاف الیہ ہے اورعلم کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ا پنی ذات مبارکہ کی طرف کی ہے ۔تواللہ کوصرف علیم نہیں کہنابلکہ اللہ علیم ہے اور صفت علم رکھتا ہے‘ اللہ تعالیٰ قدیر ہے اور صفت قدرت رکھتاہے۔اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمیع اور بصیر ہے‘ صفت ِسماعت اور صفت ِبصارت رکھتاہے ۔یہ وہ مبحث ہے جس پر پھر ایک طویل بحث ہوئی اور سمجھا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کے بارے میں صحیح عقیدہ کیاہونا چاہیے ۔
بعد میں ایساہو اکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیاہو کیانہ ہو‘یہ ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا‘کیونکہ دنیا زیادہ اہم ہوگئی ۔پھر یہ کہا جانے لگا کہ مسلمان اس طرح کے مسائل میں اُلجھتے رہ گئے اور ترقی نہ کرسکے۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ عین اور غیر کے مسائل چھوڑ دیتے اور دنیا میں ترقی کر کے دکھاتے۔دنیا تواتنی آگے نکل گئی اور یہ عین اور غیر کے مسائل ہی میں رہ گئے!اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے لیے اللہ کو جاننا دنیا کو جاننے سے زیادہ اہم تھا۔اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچاننا ہے تواللہ کے بارے میں ٹھیک بات بھی جاننی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کن باتوںکا اثبات کیا ہے اورکن باتوں کی نفی کی ہے۔ توخد اکی صحیح معرفت اور خدا سے تعلق کے لیےاورکچھ خارجی وجوہات کی وجہ سے اس بحث کوکرنا ضروری تھا۔لہٰذا ہمارے علماء نے یہ بحث کی اورکسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ فضول بحث ہے ‘اس کی کوئی حاجت نہیں ہے‘اس کو چھوڑ دو۔اب آپ کو سمجھ آرہی ہوگی کہ معتزلہ نے یہ موقف کیوں اختیار کیا کہ ہم نے صفات کو نہیں ماننا کہ اس سے تعددِ قدماء لازم نہ آجائے اوراس سے ‘نعوذباللہ‘ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وجود مرکب ہونا لازم نہ آجائے ‘لہٰذا انہوں نے اضافی صفات کاانکار کردیااور کہہ دیا کہ اللہ علیم اپنی ذات سے ہے نہ کہ اپنے علم سے ۔اہل سُنّت نے کہا کہ ایسا نہیں ہے ۔ اہل سُنّت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمام آیات اور نصوص کو جمع کرتے ہیں اور ان کے ہاں یہ نہیں ہوتاکہ دور دراز کی کوئی تاویل ڈھونڈ کرلائی جائے ۔اہل سُنّت کے سوا جتنے بھی فرق ہیں انہیں اپناموقف ثابت کرنے کے لیے بہت دور دراز کی تاویلیں کرنی پڑتی ہیں ۔چنانچہ معتزلہ نے علم اور قدرت کا انکار کرنے کے لیے تاویلات کا ایک طومار باندھا ہے ۔اہل سُنّت کے ہاں اللہ کے فضل سے ایسا نہیں ہے ۔البتہ اہل سُنّت کے ہاں یہ مسلّم تھاکہ تعددِ قدماء بھی نہیں ہوسکتااور یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مرکب ہو۔یعنی معتزلہ نے صفات کا انکار کرتے ہوئے جو اعتراضات اٹھائے وہ اعتراضات توبرحق تھے‘ اہل سُنّت بھی اس کے قائل تھے ۔اہل سُنّت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کو مرکب نہیں کہتے بلکہ اَحد کہتے ہیں کہ وہاںکسی قسم کی ترکیب نہیں ہے اوراسی طرح ایک سے زیادہ قدیم کے بھی وہ قائل نہیں ہیں‘ لیکن پھر بھی وہ صفا ت کو مانتے ہیں اوران کا انکار نہیں کرتے۔
ضد اور نقیض کافرق
اہل سُنّت نے جوموقف اختیار کیاکچھ لوگوں کااس پراعتراض یہ ہے کہ یہ تونقیضین کو جمع کرنا ہے ۔ دوچیزیں نقیض ہوتی ہیں ‘مثلاً ایک شے اورساتھ ہی اس کی نفی ‘دونوں بیک وقت جمع نہیں ہوسکتیں ۔یعنی یالکڑی ہوگی یالکڑی کا غیر ہوگا۔یہ تونہیں ہوسکتا کہ نہ لکڑی ہواور نہ لکڑی کا غیر ہو۔یہ انسان ہے یاغیرانسان ہے ‘بس دوہی احتمالات ہیں۔ یہ ضد کی بات نہیں ہورہی ۔ضد اور شے ہوتی ہے‘ نقیض اور شے ہوتی ہے ۔نقیض میں اسی شے کی نفی ہوتی ہے۔یعنی سیاہ اور سفیدباہم نقیض نہیںہیں ‘یہ ضد ہیں۔سیاہ کی نقیض ہوگی غیر سیاہ ۔سفید ا س کی ضد ہے ۔نقیض ایک ساتھ نہ توجمع ہوسکتی ہیں ‘یعنی یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ ایک شے ایک وقت میں سیاہ بھی ہواور غیرسیاہ بھی ہو‘او ر نہ یہ دونوں بیک وقت اُٹھ سکتی ہیں۔ یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہ سیاہ ہے نہ غیر سیاہ ہے ۔اَضداد جمع تونہیں ہوسکتیں مگر اُٹھ سکتی ہیں ۔ بیک وقت سیاہ اور سفید جمع تونہیں ہوسکتے‘لیکن یہ ہوسکتا ہے کہ یہ نہ سیاہ ہونہ سفید ہو‘کچھ او ر ہو۔نقیض نہ جمع ہوسکتیں ہیں اور نہ اُٹھ سکتی ہیں ۔ عین اورغیر نقیض ہیں ۔یعنی جب کہیں عین ذات اور پھر غیر ذات میں اسی کی نفی کردی تویہ نقیض ہوگئی۔ معترضین کہہ رہے ہیں کہ اہل ِسُنّت نے نقیضین کا اثبات کس طرح کرلیا؟ ’’نہ عین ذات اور نہ غیر ذات ‘‘یہ تونقیضین کا اثبات ہوگیااور منطق کا یہ قاعدہ سب کو معلوم ہے کہ ’’النقیضان لایجتمعان ولایرتفعان‘‘۔اس پر اہل سُنّت کا جواب یہ ہے کہ ’’ نقیضین‘‘ اس وقت نقیض بنتی ہے جب ایک جہت سے ‘ایک اعتبار سے‘اور ایک حیثیت سے ہو۔یعنی ایک شے جس حیثیت سے عین ذات ہے اسی حیثیت سے کہہ دیا جائے کہ وہ غیر ذات ہے تونقیض ہوجائے گی ۔ لیکن اگر ایک حیثیت سے عین ذات ہے اورکسی اور حیثیت سے غیرذات ہے توپھر نقیض نہیں ہوگی ۔تونقیضین بننے کے لیے دونوں جہات کا ایک ہونا ضروری ہے ۔ہم کہہ رہے ہیں کہ عین ذات ایک اعتبار سے ہے ‘غیرذات اسی اعتبار سے نہیں بلکہ ایک اور اعتبار سے ہے ۔لہٰذایہ نقیضین نہیں ہیں اور ان دونوں کا اجتماع ممکن ہے ۔
صفات کی ذات سے عینیت حقیقی ہے او رغیریت اعتباری
اب اہل سُنّت نے صفاتِ معانی کو کس طریقے پر سمجھا کہ یہ عین ذات اور غیر ذات ہیں ؟کس طریقے پر اس سے تعددِقدماءاور ترکیب لازم نہیں آتی؟ان کا کہنا ہے کہ اـصل میں جب تم صفت پر غور کرتے ہوتوکیایہ نہیں پاتے کہ صفت ِعلم صفت ِقدرت کی غیر ہوتی ہے ‘اور کیایہ نہیں پاتے کہ صفت ِقدرت صفت ِعلم کی غیر ہے؟یعنی ذہنی طور پر اوراعتباری طور پر یہ صفات الگ الگ سمجھی جاسکتی ہیں یانہیں سمجھی جاسکتیں؟ اور کیایہ نہیں ہوسکتا کہ کوئی ذات ہو جس میں صفت ِقدرت توپائی جاتی ہولیکن مثلاً صفت ِسماعت نہ ہو؟تویہ صفات ان معنی میں کہ ذہنی طور پر اور اعتباری طور پر ایک دوسرے کی غیر ہیں‘ذات کی بھی غیر ہیں اور ہر صفت ایک دوسرے کی بھی غیر ہے ۔لیکن یہ صرف اعتبار اور ذہن ہے۔ توجب ہم کہتے ہیں کہ عین ذات نہیں ہے تواس وقت ہم اعتبار ‘فہم اورعلم مراد لے رہے ہوتے ہیں ۔اور جب ہم کہتے ہیں کہ عین ذات ہے تواب خارج مراد لیتے ہیں۔خارج میں بس ایک ذات ہی ہے جوصفات سے متصف ہے ‘وہاں کوئی ترکیب نہیں ہے ۔یہ ترکیب جو لازم آرہی ہے یہ ذہنی ہے‘ اعتباری ہے ‘ فہمی ہے ‘علمی ہے‘ تقدیری ہے۔یعنی سمجھنے کے لیےہے ۔توخارج میں کوئی ترکب نہیںہے‘ بس ایک ذات ہے جومتصف بالصفات ہے ۔اور یہ صفات اس طرح کی کوئی شے نہیںہے جس کو آپ دکھا سکیں کہ یہ ایک شخصیت ہے‘ نعوذ باللہ‘ اور یہ اس کی صفت ہے۔ صفت الگ خارج میں کوئی وجود نہیں رکھتی۔خارج میں وہ عین ذات ہوتی ہے لیکن فہم اور علم کے اعتبار سے ‘ سمجھنے اور تغایرذہنی کے اعتبار سے یہ الگ الگ ہیں ۔خارج میں بس ایک ذات ہے۔یہ باتیں انسان پر بھی ایک اعتبار سے صادق آسکتی ہیں ‘لیکن انسان کا وجود مرکب ہے‘ جیسے اُس کے ہاتھ پائوں بھی کچھ صفات شمار ہوتے ہیں ‘جبکہ اللہ کے بارے میں ہم نے جان لیا کہ وہ جسمانیت سے ماوراء ہےاور وجودِ مرکب نہیںہے ۔
صفت ِید صفت ِعین نہیں ہے
اہل ِسُنّت نے کہا کہ اللہ کے لیے جب ’’ید‘‘ آتا ہے تویدکوصفت عین ماننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔یعنی جب ہم اپنے لیے ید بولتے ہیں تویہ صفت نہیں ہوتی بلکہ جز وہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اجزاء سے ماورا ء ہیں ۔اہل سُنّت کی کتابوں میں بھی صفت ید کا اثبات ہوتا ہے ۔مجسمہ ‘جو اللہ کوجسم مانتے ہیں‘ وہ بھی اس کا اثبات کرتے ہیں ۔فرق یہ ہوتاہے کہ اہل سُنّت اس کوصفت معنی مان کر اثبات کرتے ہیں ‘جبکہ وہ صفت ِعین مان کر کرتے ہیں ۔صفت معنیٰ کامطلب ہے کہ جس طرح علم ‘قدرت‘سماعت اور بصارت ایسی صفات ہیں جوخارج میں مرکب نہیں ہوتیں اسی طرح یہ بھی کوئی ایسی ہی صفت ہے ۔لیکن جب آپ اس کوصفت عین کہتے ہیں تواس کامطلب ہوتاہے ایسی صفت جس کی طرف اشارہ کرناکسی دوسری صفت کی طرف اشارہ کرنے کے مترادف نہ ہو۔یعنی اگر آپ کہیں گے کہ یہ میرا ید ہے توآپ ید کی طرف اشار ہ کریں گے کہ یہ میرا عین ہے‘عین جزو کو کہہ رہے ہیں۔ مجسمہ ‘ صفاتِ ید‘ قدم‘ ساق اور ا س طرح کی صفات کو صفات عین مانتے ہیں اوراہل ِسُنّت صفات ِمعنیٰ ‘اگر اثبات کرنا ہے اور تاویل نہیں کرنی۔اگر ہم تقریب اِلی الذہن کے لیے ایک مثال لے لیں توانسان خارج میں ایک وجود ہے‘ اس میں آپ الگ سے کوئی علم اورقدرت نہیں دکھا سکتے ‘ کہ اِدھر علم ہے اور اُدھر قدرت ہے ‘اور اِدھر ارادہ ہے اور اُدھر سماعت یابصارت ہے‘ بلکہ ایک وجودہے ۔وہاں ان صفات کے اعتبار سے ترکیب نہیں ہے تو{وَلِلہِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی} اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تو بلند مثال ہے ۔صفات کی عینیت اور غیریت کے مسئلے کا قریب الفہم بیان یہ ہے کہ ایک اعتبار سے عین ذات ہیں او ردوسرے اعتبار سے غیرذات ‘لہٰذا ہم نے ان دونوں کو جمع کرکے کہہ دیاکہ نہ عین ذات ہیں اور نہ غیرذات ہیں ۔
یہ صفاتِ معانی کے حوالے سے اہل سُنّت کا مسلک ہے ‘لیکن صفات کااثبات ضروری ہے۔ اور صفت عین ہے یاغیراس میں اختلاف عقیدے کے اصولی مسئلے میں اختلاف شمار نہیں ہوتایعنی اس سے انسان اہل سُنّت سے خارج نہیں ہوتا۔آپ کہیں گے کہ معتزلہ کوکیوں خارج کردیا ؟اس لیے کہ انہوں نے صفات کا انکار کردیاتھا۔اگر آپ کہیں اللہ کی صفت علم ہے ‘اللہ کی صفت قدرت ہے۔ اس کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آتاکہ عین اور غیرذات کے مسائل کیاہوتے ہیں توٹھیک ہے نہ سمجھ آئے ‘لیکن آپ نے اللہ کی صفت کاانکار نہیں کرنا۔مجھے ایک صاحب نے کہا آپ خلاصہ بتادیں کہ کیامانناضروری ہے؟ عین اور غیر کی بحث فروعی مسائل میں سے ہے‘مگر یہ ماننا ضروری ہے کہ ا للہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے ۔ وہ صفات ہیں : علم ‘قدرت ‘ارادہ ‘سماعت ‘بصارت ‘کلام ‘حیات اور صفت تکوین ۔ یہ آٹھ صفات ہیں ۔سات (صفات ِسبعہ )پر اتفاق ہے‘صفت ِثمانیہ پراختلاف ہے ۔باقی یہ بحث آپ کو معلوم ہویانہ معلوم ہوتواہم بات نہیںہے‘ لیکن اتنا ضرور جان لیں کہ علماء نے بحث کی ہے توکچھ ضرورت کے تحت کی ہے ۔ایسے ہی ان کے ذہن میں نہیں آگیا کہ غور کرتے ہیں کہ صفات عین ِذات ہیں یا غیر ذات ہیں۔ظاہر ہے کچھ ضرورت تھی ‘کچھ باطل فرقوں کا انکار مقصود تھا‘وغیرہ۔یہ بحث متعلق (revelant) ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی غیر متعلق (irrelevant) قسم کی بحث ہو۔اب تک کی بحث سے صفاتِ معانی کامطلب آپ کو سمجھ آگیا کہ ایک صفت وجودی ہے جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارکہ کے لیے اثبات ہورہا ہے۔
ماخذ ِصفات ِسبعہ
اب سوال یہ پیداہوتا ہے کہ ہم نے توقرآن وحدیث میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت سی صفات پڑھی ہیں ‘ یہ سات صفات کامعاملہ کہاں سے آگیا؟یہ ایک بڑا عتراض ہے جو اہل سُنّت پرہوتا رہتا ہے کہ ان کے ہاں صفات سبعہ ہیں اور قرآن میں توصفات کی کوئی انتہا نہیںہے ۔اللہ کے ننانوے اَسماء ہیں اور بہت سے اَسماء ایسے بھی ہیں کہ جو ہمیں معلوم نہیں۔ یہ صفات ِسبعہ کی تعیین کہاں سے ہوئی‘ کیا اہل سُنّت نے باقی صفات کا انکار کیا ؟اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ انہوں نے باقی صفات کاانکار کیا ہےلہٰذا یہ اہل سُنّت سے نکل گئے ہیں اور اصل میں یہ معطلہ ہیں‘ کیونکہ یہ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے ۔اہل سُنّت نے کہا :تم ہمارا موقف سمجھ لو‘کیونکہ کئی دفعہ بغیر سمجھے تنقید ہوتی ہے ۔اور علم کی دنیا میں بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ نے کسی شے پر حکم لگانا ہے توپہلے اس کو سمجھیں ۔آپ منطق کاقاعدہ پڑھتے ہیں :’’الحکم علی الشیئ فرع عن تصورہ‘‘کہ کسی شے پر حکم لگانا اس کے تصوّر کی فرع ہوتی ہے۔ توپہلے بات کوسمجھ لیجیے ‘پھرحکم لگائیے۔جب ہم نے صفاتِ سبعہ یاثمانیہ کہا توہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہی صفاتِ سبعہ اور ثمانیہ ہیں ‘بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صفاتِ سبعہ اور ثمانیہ ایسی بنیادی صفات ہیں کہ جن کی طرف باقی صفات کو لوٹایا جاسکتا ہے۔ یعنی ان صفات میں سے کسی ایک صفت کی طرف آپ تمام صفات کو لوٹاسکتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ خالق‘رازق ‘محیی اور ممیت نہیں ہے ۔یہ تمام صفاتِ فعلیہ ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں‘ لیکن ہم یہ بتارہے ہیںکہ کس طرح ان سب صفات کوصفت ِقدرت کی طرف لوٹایاجاسکتا ہے ۔ یہ سب صفات مانواورصفت ِقدرت نہ مانو توکچھ نہیں مانا۔اور اگر تم نے یہ بنیادی سات صفات مان لیں تواس کے ذیل میں تم نے گویا تمام صفات کا اقرار کرلیا۔مثال کے طور پر آج جوہم پہلی صفت پڑھنے جارہے ہیں وہ صفت ِقدرت ہے۔اب جتنی بھی صفاتِ فعلیہ ہیں وہ صفت ِقدرت کے تحت ہیں۔ صفات ِفعلیہ سے مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہوتے ہیں ۔مثلاًخلق ‘رزق ‘تدبیر‘ احیاء ‘اماتہ ‘ اعزاز وغیرہ۔ارشاد ہوتاہے :
{وَاَنَّـہٗ ہُوَ اَضْحَکَ وَاَبْکٰی(۴۳)}(النجم)’’اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔‘‘
اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے :
{کُلَّ یَوْمٍ ھُوَفِیْ شَاْنٍ (۲۹)} (الرحمٰن)’’ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔‘‘
ہرآن اُس کی ایک شان ہے ۔یہ سب اللہ کی صفاتِ فعلیہ ہیں جن کا کائنات میں ظہور ہورہا ہے ۔یہ سب صفت قدرت کے تحت ہیں۔ یعنی احیاء ہے ‘کسی کو حیات دینے کی قدرت رکھنا۔اماتہ ہے کسی کو موت دینے کی قدرت رکھنا۔ رزّاق ہونے کامطلب ہے کسی کو رزق پہنچانے کی قدرت کا ہونا۔اسی طریقے پر باقی صفاتِ فعلیہ ہیں۔ توقدرت ا ور ارادے کی طرف تمام صفات ِفعلیہ پلٹ جاتی ہیں۔ اصل میں بنیادی صفت کہ جس کا اقرار مقصود ہے وہ صفت ِقدرت اور صفت ِارادہ ہے ۔باقی جتنی صفاتِ افعال ہیں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدر ت کے تحت بیان کی جاسکتی ہیں ۔ کسی نے انکار نہیں کیا کہ اللہ خالق ہے ۔خالق ہونے کا کیسے انکار کرسکتے ہیں؟ یااللہ رازق ہے‘ یااللہ مدبر ہے‘یااللہ سبحانہ وتعالیٰ حکیم ہے‘بس صفت حکمت کو علم کی طرف لوٹایا۔یہ بات سمجھ لیجیے کہ جوصفاتِ سبعہ ہم پڑھنے جارہے ہیں اس کامطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی صفاتِ سبعہ ہیں بلکہ صفاتِ سبعہ بنیادی ہیں جن کی طرف باقی صفات کو ہم لوٹا سکتے ہیں اور ساری صفات انہی کی طرف پلٹتی ہیں ۔
صفت ِقدرت
ہم صفت ِقدرت سے آغاز کریں گے ‘اگرچہ صفات میں ترتیب ضروری نہیںہے ۔بعض نے صفت ِحیات سے شروع کیا ہے کہ حیات ہوگی توساری صفات ہوں گی ‘لیکن اکثر عقیدے کی کتابوںمیں صفت ِقدرت سے آغاز کیا گیاہے۔ امام ابراہیم القانی کی جوھرۃ التوحید ایک منظوم متن ہے‘جس کی بہت سی شروحات کی گئیں ہیں۔ مصر کے بہت بڑے علامہ ‘جامعہ ازہر کے شیخ‘چار پانچ سوسال پرانے علامہ البیجوری کی اس پر ایک شرح ہے : شرح البیجوری علٰی جوھرۃ التوحید۔یہ بہت مشہور ہے اور ابھی تک ازہر میں عقیدہ کے باب میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں وہ صفت قدرت کی تعریف فرماتے ہیں : القدرۃ صفۃ وجودیۃ یعنی قدرت صفت وجودی ہے سلبی نہیں ہے ۔قدیمۃ:ہمیشہ سے ہے ۔اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں ۔یہ ہم کئی دفعہ پڑھ بھی چکے ہیں او ر سمجھ بھی چکے ہیں کہ اللہ کی کسی صفت میں اضافہ نہیں ہوتا۔اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں ‘کامل ہیں ‘ ان میں کوئی استکمال یا تکمیل نہیں ہوتی۔ اگر اس میں مزید بڑھنے کی گنجائش ہوتوبڑھنے سے ماقبل حالت نقص کی ہوجائے گی ۔اور نعوذباللہ ‘اللہ تعالیٰ میں نقص لازم آجائے گا۔اسی لیے ہم کہیں گے صفت ِقدرت قدیم ہے چاہے مقدور ہویانہ ہو۔یعنی جس پر قدرت ہے اس کاوجود ہی نہ ہو۔جیسے ہم نے امام طحاوی کی عبارت پڑھی تھی :لہ معنی الربوبیۃ ولامربوب۔اس کے لیے ربوبیت ثابت ہے مربوب چاہے کوئی نہ ہو۔ لہ معنی الخالقیۃ ولامخلوقاس کے لیے خالقیت کامعنیٰ ثابت ہے چاہےمخلوق کوئی نہ ہو۔اسی طرح اس کے لیے قدرت ثابت ہے چاہےمقدور موجود نہ ہو۔ چاہے مقدور جس پرقدرت ہے ‘اللہ نے اسے وجود نہ دیا ہو۔ پھر فرمایا: ثابتۃ لذات اللہ سبحانہ وتعالٰـی:ثابتہ سے مرادہے صفت کاپایا جانا۔صرف اعتباری نہیںہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں صفت قدرت حقیقتاًپائی جاتی ہے۔ اعتباری غیر ہونے کے اعتبار سے ہے مگر وہ صفت تواللہ کے لیے ثابت ہے۔یعنی اللہ کی ذات جو خارج (تسامحاً)میں ہے وہ صفت قدرت سے یقیناً متصف ہے ۔
قدرت صرف ممکنات سے متعلق ہوتی ہے
پھرفرمایا:تتعلق بالممکنات: ممکنات سے متعلق ہوتی ہے ۔ہم نے پہلے تقسیم کی تھی کہ ایک واجب الوجود ہوتا ہے‘ ایک ممکن الوجود ہوتاہے اور ایک ممتنع الوجود ہوتا ہے ۔واجب الوجود اللہ کی ذا ت کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کیاقدرت اللہ کی ذات سے متعلق ہے؟اللہ کی ذات سے قدرت متعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قدرت ذات میں کمی یانقص کرے گی ۔وہ توخدا ہو ہی نہیں سکتاجس میں کمی بیشی ہوجائے ۔توقدرت واجب الوجود سے متعلق نہیں ہوتی ۔جوممتنع الوجود ہے‘ جوا صلاً ہے ہی نہیں‘اس سے بھی قدرت متعلق نہیں ہوسکتی۔اس کی میں وضاحت کروں گا‘ کیونکہ صفت قدر ت کے حوالے سے اعتراضات ہوتے ہیں کہ اللہ یہ کرسکتا ہےیا نہیں؟ وہ کرسکتا ہے یانہیں؟نعوذباللہ! اور یہ ہم صرف تدریس کی ضرورت کے تحت بیان کررہے ہیں ‘مثلاًاللہ ایسی چٹان بناسکتا ہے جوخود نہ اٹھاسکے؟ نعوذباللہ!اس پرہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ممتنع ہے کہ جس کانہ ہونا واجب ہے۔ یعنی ممتنع الوجود واجب العدم ہوتا ہے۔ تیسری شےرہ جاتی ہے :ممکن الوجودکہ جس کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے قدرت درکار ہوتی ہے۔ توقدرت ان تین وجودوں میںسے صرف ممکن الوجود سے متعلق ہوگی ۔تتعلق بالممکنات کا مطلب ہے کہ صفت قدرت کے متعلقات ممکنات الوجود ہوں گے اور صفت قدر ت کےتعلق کامطلب ہے کہ صفت ِقدر ت کے تعلق کے نتیجے میں مقدور وجود میں آئے گا۔جو صفت ِقدرت کا متعلق ہے وہ مقدور ہے ۔یعنی تعلق کو سمجھنا ہے تویوں سمجھیں کہ اللہ نے کائنا ت پیدا کی تواللہ کی مقدور تھی ‘اس سے ماقبل وہ ممکن تھی‘ یعنی اللہ کائنات پیدا کرسکتا تھا۔توصفت قدرت کے تعلق کےنتیجے میں کائنات پیدا ہوئی ۔متعلق اس صفت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شے کو کہتے ہیں ۔
اب صفت قدرت سے جو متعلق پیدا ہوگاوہ واجب الوجود ہوگا‘یاممکن الوجود ہوگا‘یاممتنع الوجود ہوگا؟علماء کلام نے کہا ممکن الوجود ہوگا۔یہ مطلب ہے تتعلق بالممکناتکایعنی صرف ممکنات سے یہ صفت متعلق ہوتی ہے ۔کس حیثیت سے متعلق ہوتی ہے ؟کہتے ہیں :صفۃ وجودیۃقدیمۃ ثابتۃلذات اللہ سبحانہ وتعالٰی تتعلق بالممکنات ایجادًا اعدامًا وتکیّفًا۔ایجادًا واعدامًاسے مراد ہے کہ قدرت ممکن کویاوجود دے گی یاعدم بعداز وجود دے گی ۔یعنی یاوجود میں لائے گی یاعدم کے پردے میں واپس لے جائے گی۔ اور تیسری شے تکیّفًاسے مراد ہے کہ وجود دینے کے بعد ا س وجود کی جتنی بھی صورتیں بنیں گی‘ جوبھی کیفیات ہوں گی وہ سب کی سب بھی صفت ِقدر ت سے ہوں گی۔ تووجوداوروجود کے بعد اس کے بقاء میں جتنی بھی ممکنات
(possibilities)ہوسکتی ہیں ‘ان میں سے لمحہ موجودایک امکان کو منصہ شہود پرلانا صفت قدرت کا نتیجہ ہے۔یعنی میری شکل کی انتہائی possibilitiesہوسکتی ہیںلیکن قدرت نے ایک possibilityکومعین کردیا ہے تویہ تکیف ہے۔ لیکن اسی کوکیوں معین کیاہے ‘یہ نتیجہ ہے صفت ارادہ کا۔ جب ہم صفت ارادہ پڑھیں گے تواس کی تفصیل ہوگی ۔ان شاء اللہ!بہت سے ممکنات دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن اللہ ان کووجود دے سکتا تھا ‘پھر اسی کو کیوں دیا؟مجھے دیا اور اس کونہیں دیا جوابھی عدم میں ہے یاہمیشہ عدم میں رہے گا‘اس کی وجہ صفت ارادہ ہے۔اہل ِ سُنّت کے دوبنیادی اصول ہیں :صفت قدرت اور ارادہ۔
تعریفاتِ صفات مناطقہ کی حد نہیں ہیں
دوبارہ قدرت کی تعریف دیکھ لیں کہ یہ صفت وجودی ہے ‘ثابت ہے ‘اللہ کی ذات ِعالیہ کے لیے اور قدیم ہے۔ ممکنات سے متعلق ہوتی ہےاس طرح کہ ایجاد کرتی ہے ‘اعدام کرتی ہے اور اس کی کیفیت او رصورت متعین کرتی ہے ۔یہ صفت قدرت کی تعریف ہے ‘لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ تعریف منطق کی رو سے حد نہیں ہے ۔حد سے مرادہے کہ ہم اس میں صفت قدرت کی ماہیت اور حقیقت کونہیں بیان کررہے ہیں ‘کیونکہ وہ توہم پہلے ہی اقرا ر کرچکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور صفت دونوں کی ماہیت ‘کنہ‘ حقیقت اوراس کا اصل جوہر ہمارے ادراک سے ماوراء ہے ۔ہم صرف یہ بات بیان کررہے ہیں کہ صفت قدر ت سے کیاہوتاہے ۔صفت قدرت سے کیسے ہوتا ہے ‘عدم سے وجود کیسے آرہا ہوتا ہے ‘یہ ہمیں پتانہیں ہے۔یہ توہم صفت ِقدرت کی حقیقت جان سکیں توپتا چلے گا۔لہٰذا ابھی بھی بہت سے لوگ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ عدم سے کوئی شے کیسے وجود میں آتی ہے ۔اسے صفت قدرت وجود میں لے آکر آتی ہے۔صفت ِقدرت کیسے عدم سے وجود میںلے کر آتی ہے یہ نامعلوم ہے ۔
عدم سے وجود کی حقیقت ماورائے عقل ہے
یہاں ہمیں اپنے عجز اور اپنی جہالت کا عتراف کرنا پڑے گاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کی حقیقت بیان نہیں کررہے ‘لیکن ہمیں اتنا ضرور پتا ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پید اکی ہے ۔کیسے پیدا ہوئی ‘عدم کاپردہ کیسے چاک ہوااور کس طریقے پرکائنات برآمد ہوئی ؟اس کو ہمارا ذہن سمجھ نہیں سکتاکہ کوئی شے نہ ہواور ہوجائے۔ یہ صفت قدرت کی حقیقت جاننے پرمنحصر ہےاوراس کی حقیقت ہمارے حواس وعقل وتخیل سے ماوراء ہے۔ اگرچہ بہت سے مختلف فلسفے اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے ہیں جس کو ’ربط الحادث بالقدیم‘ کامسئلہ کہتے ہیں کہ کیسے قدیم سے حادث وجود میں آگیا ۔ہمارے ہاں جووحدت الوجود کاایک فلسفہ ہے وہ بھی اصلاًاس کی توجیہہ کرنے کے لیے ہے کہ کس طرح عدم سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ لیکن ہمارے علماء ِ عقیدہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی انسانی عقل کی حدود سے ماوراء ہے ‘کیونکہ اس کاانحصار ہے اللہ کی صفت قدرت کی حقیقت جاننے پر۔اوراللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت قدرت کی حقیقت جان لینا انسانی فہم کے لیے ممتنع ہے یعنی ناممکن ہے‘لہٰذا ہم نہیں جان سکتے۔ ہاں فلسفے وغیرہ بناتے رہیں لیکن بالآخر وہ سب ظنی ہوں گے۔ پتا نہیں چلے گا کہ اللہ نے کیسے یہ کائنات پیدا کی ہے ۔اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریاؑسے فرمایا:{وَقَدْ خَلَقْتُکَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَکُ شَیْئًا(۹)}(مریم)’’اورتمہیں بھی تو مَیں نے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔‘‘تمہیں ایسے پیدا کیا کہ تم پہلے کچھ بھی نہ تھے ‘تمہارا وجود ہی نہیں تھا۔
{ھَلْ اَتٰی عَلَی الْاِنْسَانِ حِیْنٌ مِّنَ الدَّھْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئًا مَّذْکُوْرًا(۱)} (الدھر)
’’کیا انسان پر اس زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟‘‘
کوئی قابل ذکر شے نہ تھا وہ اورپھر اس کو پید اکردیا ۔اس لیے کہ اللہ کی صفت ’’بَدِیْعُ‘‘ہے :
{ بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِط} (البقرۃ:۱۱۷)
’’وہ نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔‘‘
اسی طرح اللہ کی صفت ہے ’’بَارِیٔ‘‘۔ بَارِیٔاور بدیعکے اندر مفہوم ہے بغیر کسی شے کے پیدا کردینا۔تویہ اللہ ہی کرسکتا ہے ۔ہماری عقل کہہ رہی ہے کہ اللہ کر سکتا ہے ‘لیکن یہ کیسے ہوتا ہے اس کا فہم ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ایک شے وہ ہے جس کوہماری عقل بتارہی ہوکہ یہ خلافِ عقل ہے اور ایک شے وہ ہوتی ہے جوماورائے عقل ہے کہ ہماری عقل کہہ رہی ہے ہوناتوایسے ہی چاہیے اگر خداہے تو‘لیکن کیسے ہورہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا چلتا۔تویہ مافوق العقل تو ہے خلافِ عقل نہیں ہے ۔
اب اس صفت کا اثبات ہے ۔اس حوالے سے امام بیہقی علیہ الرحمہ نے اس صفت کے اثبات میں حدیث استخارہ اور کچھ آیات نقل کی ہیں ۔وہ آیات یہ ہیں:
{وَکَانَ اللہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ مُّقْتَدِرًا(۴۵)}(الکھف)
’’اوراللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔‘‘
{اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ(۲۰)}(البقرۃ)
’’یقیناًاللہ ہر چیز پر قادر ہے۔‘‘
{ بَلٰی قٰدِرِیْنَ عَلٰی اَنْ نُّسَوِّیَ بَنَانَہٗ (۴)} (القیامۃ)
’’کیوں نہیں! ہم تو پوری طرح قادر ہیںاس پر بھی کہ ہم اس کی ایک ایک پور درست کر دیں۔‘‘
{قُلْ ھُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓی اَنْ یَّبْعَثَ عَلَیْکُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِکُمْ} (الانعام:۶۵)
’’کہہ دیجیے کہ وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے‘‘
{اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِیْ جَنّٰتٍ وَّنَھَرٍ (۵۴) فِیْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِیْکٍ مُّقْتَدِرٍ(۵۵)} (القمر)
’’یقیناً متقین باغات اور نہروں (کے ماحول) میں ہوں گے۔بہت اعلیٰ راستی کے مقام میں اُس بادشاہ کے پاس جو اقتدارِ مطلق کا مالک ہے۔‘‘
تو’’مقتدر‘‘ بھی صاحب ِقدرت ہے’’قادر‘‘ بھی صاحب ِقدرت ہے ۔’’قادر‘‘ سے زیادہ ’’قدیر ‘‘بلیغ ہے ‘کیونکہ صفت مشبہ ہے فعیل کے وزن پر‘اس لیے ا س کے اندر معنی کا دوام زیادہ ہوتاہے ۔
الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پردال ہے
بعض نے کہا کہ جو لفظ ’’مقتدر‘‘ ہے اس کے اندر مزید معنیٰ کی زیادتی ہے ‘کیونکہ عربی زبان کاقاعدہ یہ ہے کہ زیادۃ المبنیٰ تدل علی زیادۃ المعنییعنی حروف زیادہ ہوں گے تومعنیٰ میں بھی کچھ اضافہ ضرور ہوگا۔یعنی ’’قدیر‘‘ کے حروف چار اور’’مقتدر‘‘ کے حروف پانچ ہیں۔اگر آپ کہیں کہ ’’مقتدر‘‘ کے اندر’’قدیر‘‘ کے لفظ سے کم معنیٰ ہے توسوال پیدا ہوگا کہ حروف زیادہ ہیں تومعنی کم کیسے ہے؟عربی کا عمومی قاعدہ جانے بغیرآپ صرف حروف کی کثرت اور قلت سے بھی یہ جان سکتے ہیں کہ جس اسم میں حروف کی کثرت ہے تویقیناً اس میں کچھ معنی کی بھی کثرت ہے۔اس کو کہتے ہیں: زیادۃ المبنیٰیعنی اس کی اینٹیں زیادہ ہیں۔اینٹیں زیادہ ہیں توعمارت بھی وسیع ہونی چاہیے ۔امام بیہقی فرماتے ہیں کہ قادر ہے ‘قدیر ہے اور پھر مقتدر ہے ۔یعنی جس کی قدرت سے اور جس کے اقتدار سے اور جس کی مملکت سے اور جس کی بادشاہی سے کوئی شے خارج نہیں ہے۔ پھر انہوں نے حدیث نقل کی۔مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ﷺنے دعائے استخارہ کوقرآن کی طرح سکھایاہے۔
((اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُکَ بِعِلْمِکِ وَاَسْتَقْدِرُکَ بِقُدْرَتِکَ . . .فَاِنَّکَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ. . .))
’’اے اللہ! بے شک مَیں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں . . . . . کیونکہ تُو قدرت رکھتا ہے اور مَیں قدرت نہیں رکھتا‘ تُو جانتا ہے اور مَیں نہیں جانتا . . . .‘‘
یہاں صفت قدرت کا اثبات ہورہا ہے ۔پھر اسی طرح اما م بیہقی ؒنے ایک اور حدیث نقل کی کہ ایک صحابی نے جسم میں درد کی شکایت کی تواللہ کے نبی ﷺ نے انہیں ایک نسخہ بیان فرمایاکہ تم تین دفعہ بسم اللہ پڑھواور سات دفعہ یہ الفاظ کہو:((اَعُوْذُ بِعِزَّۃِ اللہِ وَقُدْرَتِہٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ))یعنی مَیں اللہ کی عزّت او ر قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اُس شر سے جو مَیں اس وقت اپنے جسم میں پارہا ہوں اور جس کا مجھے خوف ہے ۔یہ صحیح روایت ہے۔جومسنون دم ہیں ان میں سے ایک دم یہ ہے کہ جہاں آپ کو درد ہورہا ہے وہاں آپ دایاںہاتھ رکھیں اور تین دفعہ بسم اللہ پڑھیں اور سات دفعہ یہ الفاظ پڑھیں۔’’ اَجِدُ ‘‘میں وہ شرہے جو اس وقت واقع ہوچکا ہے او ر ’’اُحَاذِرُ‘‘میں مستقبل کا شر ہے ۔توجو میں پاتا ہوں او رجس کا مجھے خوف ہے دونوں شرور سے میں تیری عزّت اور قدرت کی پناہ میں آتا ہوں ۔اس کے علاوہ اور بھی روایات نقل کی ہیں ۔بس یہ کافی ہیں‘ جن سے معلوم ہوگیا کہ اللہ کے نبیﷺ نے بھی اللہ کوصرف قدیر نہیں کہابلکہ قدرت کا اثبات کیا۔
ہرصفت ایک تقاضائے عبودیت رکھتی ہے
’’فَاِنَّکَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ‘‘ میں اللہ کے نبی ﷺنے یہ بھی بتادیاہے کہ اس صفت قدرت کے مقابلے میں تمہاری عبودیت کیا ہے ۔یعنی ہرصفت اور ہر اسم جواللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے وہ ہم سے بھی توایک عبودیت کا مطالبہ کررہا ہے ۔اگر اللہ رحیم ہے توہم سے بھی رحم کا مطالبہ ہے ‘لیکن اللہ قدیر ہے توہم سے مطالبہ یہ نہیں کہ ہم بھی صاحب ِقدر ت ہوجائیں ‘بلکہ ہم اپنے عجز ‘اپنے احتیاج اور فقرکا اثبات کریںگے ۔ اور ہماری عبودیت کیا ہے؟ وَلَا اَقْدِرُ’’اور مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں ہے‘‘۔ یعنی انسان کااس صفت کے مقابلے میں اپنے آپ کو بالکل قدرت سے عاری‘ مجبور‘لاچار‘فقیراورمحتاج محسوس کرنا۔صفت قدرت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اوراُس کے سوا کسی کو حاصل نہیں ۔یعنی اصلاًاُس کی صفت قدرت کے مقابلے میں کسی کی صفت قدرت نہیں ہے۔ تواس سے توکّل بھی پیدا ہوا۔قرآن مجید کاایک بنیادی مضمون ہے کہ اس کائنات میں نفع اور ضرر کاا ختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ باربار اس حقیقت کوبیان کیاگیا ہے کہ اس کواپنے شعور اور اپنے وجود میں اتار لوکہ کائنات میں نفع اور ضرر کسی کے پاس نہیں ہے ۔وہ قدرت رکھتا ہے‘اُس کے سوا کسی کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے ۔تویہ ایمانی حقیقت ہے‘ محض کوئی کلامی بحث نہیں ہے کہ صفت ِقدرت کا اثبات کرنا ہے یا نہیں کرنا؟بلکہ اس صفت قدرت کے اثبات پر عبودیت کے بہت سے احوال منحصر ہیں ۔
ایک مہمل(absurd)سوال
جیساکہ ہم نے واضح کیاکہ قدرت صرف ممکنا ت سے متعلق ہوتی ہے‘ واجبات وممتنعات سے نہیں‘توبعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سےتواللہ کی صفت قدرت کی محدودیت لازم آتی ہے ۔یعنی مثلاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا شریک بناسکتا ہے ؟نعوذ باللہ! یہ گستاخی کی باتیںہیں۔ اگر یہ موقع نہ ہوتویہ باتیں بھی نہیں کرنی چاہئیں‘ لیکن بہرحال صرف سمجھانے کے لیے ہم بیان کررہے ہیں۔ اگر تم کہو بناسکتا ہے توپھر اللہ کاشریک ثابت ہوگیا اور توحید باطل ہوگئی۔ اگر کہیںکہ نہیں بناسکتاتوپھر اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ شَیْ ٍٔ قَدِیْرٌ کاانکار لازم آگیا۔دونوں صورتوں میں مفر کوئی نہیں ۔یاپھر اس طرح کے اور الٹے سیدھے سوالات کا درسی جواب یہی ہے کہ جوبتا دیاکہ اللہ کی قدرت ممکنات سے متعلق ہوتی ہےاو ر جوشے ممتنع الوجود ہوتی ہے ‘جس کاعدم ہی واجب ہوتا ہے ‘ وہ ایک مہمل خیال (absurd idea) ہے‘وہ شے نہیں ہے۔لہٰذا جب آپ کہتے ہیں : اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ شَیْ ٍٔ قَدِیْرٌ توشے سے مراد ممکن الوجود ہے‘ شے سے مراد ممتنع الوجود نہیںہے ۔اس پر شے کے لفظ کااطلاق تسامحاً اور مجازاً ہوتا ہے ‘وگرنہ وہ شے ہی نہیں ہے ۔لہٰذا مثال کے طور پر کہ ’’اللہ تعالیٰ اپنا شریک بنانے پر قادر نہیں ہے ‘‘۔اگر اس کو ہم تحلیل کریں گے تومطلب یہ بنے گاکہ کیااللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ خدا نہ ہو؟کیونکہ شریک ہوگیاتووہ خدا نہ رہا‘ایک سے زیادہ ہوگئے تووہ واجب الوجود ہی نہیں ہے ‘وہ خدا ہی نہیں ہے ‘لہٰذا وہ شے ہی نہیں ہے ۔یعنی مثلاً آپ یہ کہیں کہ کیااللہ تعالیٰ اس بات پرقادر ہے کہ وہ مخلوق بن جائے؟ توخدا by definitionہی یہ ہے کہ وہ خدا ہوتا ہے‘ اس کا شریک نہیں ہوسکتا‘لہٰذا یہ بات ہی مہمل(absurd)ہے ۔اسی طریقے پر جب آپ کہتے ہیں کہ کیا اللہ ایک ایسی چٹان بناسکتا ہے کہ جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے توگویا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو عاجز کرسکتا ہے ۔لہٰذا یہ ایک مہمل بات ہے‘ خدا کے تصور کے خلاف ہے۔
خدا کاشریک ممتنع الوجود ہے ‘لہٰذا اس کوشے کہنا تسامحاً ہو تاہے ‘وگرنہ وہ چیز ہی بالکل بے معنیٰ ہے ‘اس کاکوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جس کا کوئی مطلب نہیں ہے ‘ جوبے معنیٰ ہے ‘وہ ممتنع الوجود ہے ‘اس سے قدرت متعلق نہیں ہورہی ہوتی۔قدرت ممکنات سے متعلق ہوتی ہے ۔ {اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ} میں کُلِّ شَیْءٍ سے مراد ممکن الوجود ہے ‘ممتنع الوجود اورواجب الوجودنہیں ہے۔ واجب الوجود ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے۔اگرہم یہ کہیںکہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ پرایسے تصرف پرقادر ہے جس کے نتیجے میں وہ خدا نہ رہے تو یہ سوال اصلاًبے معنیٰ ہے ‘مہمل ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت میں اس سے کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہیں ہورہا۔ اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلَّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ اپنے اطلاق کی شان کے ساتھ محفوظ ہے ۔بعض نے کہا : اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ خاص ہوگیا ممکنات سے اور بعض نے کہا خاص نہیں ہوا عام ہے ‘کیونکہ شے کا اطلاق ہی ممکنات پرہوتاہے ۔پھر ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ آیت خاص ہوگئی‘ بلکہ عام ہے اور شے سے مرادعلماء بتارہے ہیں ۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں !شے کا اطلاق واجب الوجود پربھی ہوجاتا ہے ۔جیسے قرآن میں آیا:
{قُلْ اَیُّ شَیْ ءٍ اَکْبَرُ شَہَادَۃً ط قُلِ اللّٰہُ قف } (الانعام:۱۹)
’’(اے نبیﷺ !ان سے) کہیے کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہے؟(پھر خود ہی ) کہیے کہ اللہ (کی گواہی سب سے بڑی ہے) !وہ میرے اور تمہارے مابین گواہ ہے۔‘‘
امام بیہقی ؒنے شَیْء کے لفظ کوبھی خدا کے اسماء میں شامل کیاہے ۔اگر آپ یوں کہیں کہ شے کے لفظ کااطلاق ہوسکتا ہے واجب الوجود پرتوپھر ہم کہیں گے کہ یہ آیت خاص ہے ۔یہاں اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ سے مراد ممکن الوجودہے۔دونوں صورتوں میں بات ایک ہی رہے گی ‘بس تھوڑا سا اختلا ف ہوگا کہ آیت خاص ہے یااپنے عموم پرباقی ہے!***