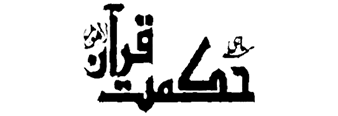(تذکر و تدبر) مِلاکُ التأویل(۳۷) - ابو جعفر احمد بن ابراہیم الغرناطی
9 /مِلاکُ التأوِیل (۳۷)تالیف : ابوجعفر احمد بن ابراہیم بن الزبیرالغرناطی
تلخیص و ترجمانی : ڈاکٹر صہیب بن عبدالغفار حسنسُورۃُ طٰہٰ(۲۴۱) سورئہ طٰہٰ‘ سورۃ النمل اور سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ بیان ہوا ہے جس میں وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ صحرائے سینا میں سفر کر رہے تھے۔ اس قصے کی حکایت جن الفاظ میں کی گئی ہے ان میں الفاظ اور معانی کا کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور اسی کا سمجھنا مقصود ہے۔ پہلے ان آیات کا متن اور ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے:
{وَہَلْ اَتٰىکَ حَدِیْثُ مُوْسٰی(۹) اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَہْلِہِ امْکُثُوْٓا اِنِّیْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّیْٓ اٰتِیْکُمْ مِّنْہَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَی النَّارِ ہُدًی(۱۰) فَلَمَّآ اَتٰىہَا نُوْدِیَ یٰمُوْسٰی(۱۱) اِنِّیْٓ اَنَا رَبُّکَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ ج اِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًی(۱۲) وَاَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوْحٰی(۱۳) اِنَّنِیْٓ اَنَا اللہُ لَآ اِلٰــہَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِیْ لا وَاَقِمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکْرِیْ(۱۴) اِنَّ السَّاعَۃَ اٰتِیَۃٌ اَکَادُ اُخْفِیْھَا لِتُجْزٰی کُلُّ نَفْسٍم بِمَا تَسْعٰی(۱۵) فَلَا یَصُدَّنَّکَ عَنْھَا مَنْ لَّا یُؤْمِنُ بِھَا وَاتَّبَعَ ھَوٰىہُ فَتَرْدٰی(۱۶) وَمَا تِلْکَ بِیَمِیْنِکَ یٰمُوْسٰی(۱۷) قَالَ ہِیَ عَصَایَ ج اَتَوَکَّؤُا عَلَیْہَا......} (طٰہٰ)
’’کیا تمہیں موسیٰ ( علیہ السلام )کے قصّے کی خبر ملی ہے؟جب اُس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے ‘ تم ذرا ٹھہرو‘(میں جاتا ہوں اور) شاید میں اس کا ایک انگارا تمہارے لیے لیتا آئوں یا آگ کے آس پاس ( لوگوں سے) راستے کے بارے میں ہدایت پائوں ۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی: اے موسیٰ! یقیناً میں ہی تیرا ربّ ہوں تو تُو اپنی جوتیاں اُتار دے‘ کیونکہ تُو طویٰ کی مقدس وادی میں ہے ۔اور میں نے تجھے چُن لیا ہے تو جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن لے! بے شک میں ہی اللہ ہوں‘ اور میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں‘ پس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرتے رہو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے اُس کی سعی کا۔ تو پھر تمہیں اس پر یقین رکھنے کے لیے کوئی بھی شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا‘ روک نہ دے ‘ایسا شخص جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہو ‘(تم اگر ایسا کرو گے) تو ہلاک ہو جائو گے! اور اے موسیٰ! تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا: یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں ......‘‘
سورۃ النمل میں ارشاد فرمایا:
{اِذْ قَالَ مُوْسٰی لِاَہْلِہٖٓ اِنِّیْٓ اٰنَسْتُ نَارًاط سَاٰتِیْکُمْ مِّنْہَا بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِیْکُمْ بِشِہَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّکُمْ تَصْطَلُوْنَ(۷) فَلَمَّا جَآئَ ہَا نُوْدِیَ اَنْ بُوْرِکَ مَنْ فِی النَّارِ وَمَنْ حَوْلَہَاط وَسُبْحٰنَ اللہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ(۸) یٰمُوْسٰٓی اِنَّہٗٓ اَنَا اللہُ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ(۹) وَاَلْقِ عَصَاکَ ط }
’’یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے‘ میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا انگارا تاکہ تم لوگ تاپ سکو۔ تو جب وہ اس (آگ) کے پاس آیا تو اس کو آواز آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہیں‘ او رپاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے موسیٰ! یہ تو میں ہوں‘ اللہ جو عزیز و حکیم ہے‘ تم اپنا عصا ڈال دو!‘‘
اور سورۃ القصص میں ارشاد فرمایا:
{فَلَمَّا قَضٰی مُوْسَی الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَہْلِہٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًاج قَالَ لِاَہْلِہِ امْکُثُوْٓا اِنِّیْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّیْٓ اٰتِیْکُمْ مِّنْہَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَۃٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّکُمْ تَصْطَلُوْنَ(۲۹) فَلَمَّآ اَتٰىہَا نُوْدِیَ مِنْ شَاطِیِٔ الْوَادِ الْاَیْمَنِ فِی الْبُقْعَۃِ الْمُبٰرَکَۃِ مِنَ الشَّجَرَۃِ اَنْ یّٰمُوْسٰٓی اِنِّیْٓ اَنَا اللہُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ(۳۰) وَاَنْ اَلْقِ عَصَاکَ ط}
’’تو جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ روانہ ہوا تو اُس نے طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی‘ تو اُس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے آگ نظر آئی ہے ‘ تم لوگ ٹھہرو کہ میں وہاں سے کوئی خبر یا آگ کا کوئی انگارا لائوں تاکہ تم لوگ تاپ سکو۔ تو جب وہ اس کے پاس آیا تو خطہ مبارک میں‘ وادیٔ ایمن کے کنارے سے‘ ایک درخت سے اُسے آواز آئی: اے موسیٰ! مَیں ہوں اللہ‘ تمام جہانوں کا پروردگار‘ اور (پھر کہا) : اپنا عصا ڈال دو!‘‘
ان آیات میں اشکال اس وجہ سے پیدا ہوا کہ ان تینوں سورتوں میں ایک ہی قصہ بیان ہوا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کی داستان ہے جو انہوں نے اپنے سفر رسالت میں طے کیا تھا۔صحرائے سینا کا سفر‘ آگ کا دیکھنا‘ پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی۔ اب اس واحد سفر کے بیان میں جو حکایت کی گئی ہے‘ اس میں خاص طور پر الفاظ کے چنائو میں اختلاف کیوں واقع ہوا ہے؟
الفاظ میں اختلاف کا ہونا مندرجہ ذیل جدول سے واضح ہے :
سورئہ طٰہ
سورۃ النمل
سورۃ القصص
(۱)
امْکُثُوْٓا اِنِّیْٓ اٰنَسْتُ نَارًا
’’امْکُثُوْٓا‘‘کا لفظ نہیں ہے
امْکُثُوْٓا اِنِّیْٓ اٰنَسْتُ نَارًا
(۲)
لَعَلِّیْٓ اٰتِیْکُمْ مِّنْہَا
سَاٰتِیْکُمْ مِّنْہَا ( لَعَلِّیْٓ کی جگہ)
لَعَلِّیْٓ اٰتِیْکُمْ مِّنْہَا
(۳)
بِقَبَسٍ
بِخَبَرٍ اَوْ اٰتِیْکُمْ بِشِہَابٍ قَبَسٍ
بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَۃٍ مِّنَ النَّارِ
( قَبَسٍ کا ذکر پہلے ہے)
(قَبَسٍ کا ذکر بعد میںہے)
(جَذْوَۃٍ بمعنی قَبَسَ بعد میں ہے)
(شِہَابٍ قَبَسٍ کا ذکر ہے)
(قَبَسَ کی جگہ جَذْوَۃٍ کا ذکر ہے)
(۴)
اٰتِیْکُمْ ایک دفعہ ذکر کیا گیا
’’اٰتِیْکُمْ‘‘کا لفظ مکرر ہے
اٰتِیْکُمْ ایک دفعہ ذکر کیا گیا
(۵)
آگ تاپنے (اصطلاء) کا ذکر نہیں ہے
’’لَعَلَّکُمْ تَصْطَلُوْنَ‘‘ارشاد فرمایا
’’ لَعَلَّکُمْ تَصْطَلُوْنَ‘‘ ارشاد فرمایا
(۶)
خبر لانے کے بجائے کہا: اَوْ اَجِدُ عَلَی النَّارِ ہُدًی
صرف خبرلانے کا ذکر ہے
صرف خبرلانے کا ذکر ہے
یہ وہ الفاظ ہیں جن میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ ان اختلافات کی نوعیت زیادتی و کمی اور تقدیم یا تاخیر کی ہے‘ اور چونکہ یہ ایک واقعہ کا بیان ہے کہ جس میں نسخ واقع نہیں ہو سکتا‘اور نہ ہی اس میں مذکورہ قسم کا اختلاف ہونا چاہیے‘ تو یہاں دو سوال اٹھتے ہیں:
(ا) وجہ اختلاف کیا ہے؟
(ب) اور جس جس سورت میں یہ اختلافی الفاظ واقع ہوئے ہیں تو اس خاص سورت میں ان کا وارد ہونا کیا معنی رکھتاہے؟
میں اللہ سے مدد چاہتے ہوئے اور اس کی توفیق اور ہدایت کا طلب گار ہوتے ہوئے عرض کرتاہوں کہ انسان کے ذہن میں جو معقول قسم کے معانی قائم ہوتے ہیں‘ ان کو سوائے الفاظ کے اور کس طرح دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ جو الفاظ معانی کے لیے اصطلاح کا کام دیتے ہیں‘ ان کے اظہار کے لیے الفاظ کا ہی سہارا لیا جاتا ہے۔اور اس بات کو ذہن نشین کرنے کے بعد یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معانی کا بعض اوقات متعدد الفاظ سے اظہار کیا جاتا ہے۔ الفاظ و معانی کے اس تعلق کی چار اقسام ہی ہو سکتی ہیں:
(۱) لفظ اور معنیٰ دونوں متحد ہوں (یعنی ایک ہی ہوں)
(۲) لفظ اور معنی میں اختلاف ہو۔
(۳) الفاظ ایک جیسے ہوں لیکن معنی مختلف ہو
(۴) الفاظ مختلف ہوں لیکن معنی ایک ہی ہو۔
عقلی اعتبار سے یہی چار قسمیں ہو سکتی ہیں‘ ان سے زائد نہیں اور انہی کے مطابق ار بابِ عقل و خرد ایک دوسرے سے خطاب کرتے ہیں۔
پہلی قسم میں نوع اور جنس سے متعلق الفاظ آجاتے ہیں‘ جیسے انسان کے تحت بشریت کے اعتبار سے متعدد اشخاص کا تصوّر کیا جاسکتا ہے ‘اور جنس کے تحت اگر لفظ حیوان لیا جائے تو اس سے انسان‘ جانور اور پرندہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔ دوسری قسم میں وہ الفاظ آ جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف معنی رکھتے ہیں جیسے کالا اور سفید‘ یا قدرت اور عجز۔ تیسری قسم میں وہ الفاظ آجاتے ہیں جن کے معانی میں اشتراک ہو سکتا ہے جیسے لفظ ’’عَیْن‘‘ سے آنکھ بھی مراد لی جا سکتی ہےاور پانی کا چشمہ بھی۔ یعنی لفظ تو ایک ہی ہے لیکن معنی مختلف ہے۔چوتھی قسم میں مترادف الفاظ آجاتے ہیں جیسے شیر کے لیے اَسَد یا لَیْث کوئی بھی لفظ استعمال کیا جاسکتا ہے۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ مشترک ہو لیکن اس کے تحت جو معانی ہوں‘ وہ اپنی قوت کے اعتبار سے متفاوت ہوں۔ اور تفاوت سے یہ مقصود ہے کہ ایک لفظ اپنے معنی کے اظہار میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہ ہو اور اس لحاظ سے وہ پہلی قسم میں شمار ہو گا‘ یا وہ اپنے اظہار کے لیے دوسری چیز کا محتاج ہو تو وہ تشکیک کے زمرے میں شمار ہو گا۔ جیسے کوئی ایسا اسم جو جوہر (مستقل بذاتہٖ) یا عرض (محتاج لغیرہٖ) دونوں کو شامل ہو‘ تو کہا جائے گا کہ اس کے معانی میں تفاوت پایا جاتا ہے۔ اگر جوہر ہو تو وہ پہلی قسم (لفظ اور معانی کا متحد ہونا) میں شمار ہو گا اور اگر عرض ہو تو وہ مُشکّک کہلائے گا۔
بعض الفاظ کے مجازی معنی لیے جاتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں خاص طو رپر اپنے مُسَمّی کے لیے وضع نہیں کیا گیا لیکن وہ اس معنی سے مناسبت رکھتے ہیں جن کے لیے وہ وضع کیے گئے ہیں۔ ایک اور بات کا بھی خیال رکھا جائے جو کسی جملے کی ترکیب میں واقع ہو سکتی ہے‘ اور جسے ’’لحن الخطاب‘‘ کا نام دیا گیا ہے‘ یعنی بعض دفعہ ایک کلمہ مقصود ہوتا ہے لیکن اسے حذف کر دیا جاتا ہے ‘کیونکہ سیاق و سباق کے اعتبارسے وہ کلمہ قابلِ فہم ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد :
{اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاکَ الْبَحْرَط فَانْفَلَقَ......} (الشعراء:۶۳)
’’(اے موسیٰ علیہ السلام !) اپنے عصا کو سمندر پر مارو ‘تو وہ پھٹ گیا......‘‘
اور یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ’’فَانْفَلَقَ‘‘ سے پہلے لفظ ’’ضَرَبَ‘‘ محذوف ہے‘ یعنی ’’تو اس نے مارا اور سمندر پھٹ گیا‘‘۔ اس قسم کی کئی اور مثالیں دی جا سکتی ہیں جس کے سوائے امام کرخی (محمد بن ابراہیم) کے تمام جمہور علماء قائل ہیں‘ جیسے قولِ باری تعالیٰ:
{ فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَّرِیْضًا اَوْ عَلٰی سَفَرٍ فَعِدَّۃٌ مِّنْ اَیَّامٍ اُخَرَط} (البقرۃ:۱۸۴)
’’تو جو تم میں سے بیمار ہو اور سفر پر ہو تو وہ دوسرےدنوں میں گنتی پوری کرے۔‘‘
یعنی جو شخص بیمار ہو اور سفر پر ہو ’’اور پھر افطار کر لے‘‘ تو پھر اس کی قضا کرے۔تو یہ حذف ’’لحن الخطاب‘‘ کہلاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایک چیزکہی جاتی ہے (منطوق بہٖ) لیکن وہ ایک دوسری چیز جس کا بیان نہیں ہوا (سکوت عنہ) پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے ارشاد فرمایا:
{ فَلَا تَقُلْ لَّھُمَا اُفٍّ} (الاسراء:۲۳) ’’اور تم اپنے والدین کو اُف تک نہ کہو۔‘‘
تو یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب اُف تک کہنا منع ہے تو جو چیز اس سے زیادہ ہو یعنی گالم گلوچ یا مارپیٹ تو وہ کیوں نہ منع ہو گی۔اسے ’’مفہوم‘‘ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے ‘اور جو لوگ قیاس کے منکر ہیں وہ بھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔
یہ چند باتیں اس لیے ذکر کر دیں تاکہ آگے کے مباحث کو سمجھا جاسکے۔ ان کا تعلق کسی ایک سورت کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایک خاص مقام سے۔ اور یہ بات بھی سب کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو اسی زبان کے ساتھ بھیجا ہے جو کہ اس کی قوم کی زبان تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی زبان عبرانی تھی اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے عبرانی زبان ہی میں کلام کیا تھا۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے تو وہ حرف‘ آواز اور جملوں کی قید سے ماوراء ہیں۔ اس لیے جو کچھ ہماری کتاب میں وارد ہوا ہے وہ ان معانی کی حکایت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں اور جو موسیٰ علیہ السلام کا موضوع خطاب رہیں۔ عبرانی زبان عربی سے قریب ترین زبانوں میں سے ہے تو پھر اس بات میں کیا مانع ہے کہ عبرانی زبان میں بھی وہ اقسام کیوں نہ پائی جائیں جو کہ عربی زبان میں پائی جاتی ہیں۔ اب اس تمہید کی روشنی میں ہم ان اعتراضات کا جواب دیتے ہیں جو پہلے بیان ہوئے ہیں:
(۱) موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے آگ کی طرف جاتے ہوئے کہا تھا : ’’امْکُثُوا‘‘(یہاں ٹھہرو!) جو کہ سورۃ النمل میں ذکر نہیں کیا گیا۔ اب اس میں دونوں باتوں کا احتمال ہے کہ یا تو انہوں نے زبان سے یہ
کلمہ اداکیاتھا‘ یا اشارتاً کہا تھا‘ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر والوں نے قرائن حال سے اس بات کو سمجھ لیا ہو۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی عبارت میں کہیں ان کے زبانی قول کی حکایت کی گئی ہے اور کہیں ان کے حکم کی ترجمانی کی گئی ہے جو ان کے گھر والوں نے ان کے طرزِعمل سے سمجھا۔ اس لیے اس اعتراض میں کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔
(۲) جہاں تک ان کا یہ کہنا: ’’لَعَلِّیْٓ اٰتِیْکُمْ‘‘ دو سورتوں میں اور ’’سَاٰتِیْکُمْ‘‘سورۃ النمل میں آیا ہے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ حرفِ تسویف (سَ یا سَوْفَ بمعنی عنقریب) سے مستقبل میں فعل کا حاصل ہونا سمجھا جاتا ہے اور ’’لَعَلَّ‘‘ حرف ِترجی (بمعنی اُمید) میں مستقبل کے معنی کے ساتھ اُمید اور لالچ کا مفہوم بھی ہے‘اور عین ممکن ہے کہ ان کی زبان میں ان دونوں معانی کو بیان کرنے کے لیے صرف ایک ہی لفظ کافی رہا ہو‘ اور چونکہ عربی زبان میں ایسا نہ تھا اس لیے دونوں معانی کا احاطہ کرنے کے لیے دو علیحدہ علیحدہ حروف لائے گئے تاکہ جو کچھ ان کی زبان میں کہا گیا اس کی مکمل ترجمانی ہو سکے۔
(۳) سورئہ طٰہ میں قَبَس (انگارے) کا ذکر پہلے ہے اور خبر لانے کا بعد میں اور باقی دونوں سورتوں میں اس کا الٹ ہے ‘تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اس قصہ کی حکایت میں معانی کا خیال رکھا گیا ہے‘ اور یہاں تقدیم اور تاخیر کا لحاظ رکھنا ضروری نہ تھا ۔
(۴) ان آیات میں آگ کے انگارے کو تین الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے :
قَبَس : آگ کا وہ شعلہ جو ایک بڑی آگ سے لیا جاتا ہے۔
جَذْوَۃ : آگ کا وہ انگارا جس میں آگ سلگ رہی ہوتی ہے۔
شِھَاب : آگ کا وہ انگارا جو بھڑک اٹھا ہو۔
عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک ہی چیز کو ذرا سے فرق کی بنا پر مختلف نام دے دیے جاتے ہیں جیسے تلوار کے لیے سیف‘ صارم اور مُہنّد کے الفاظ آئے ہیں‘ اور کھجور کے تو بہت سے نام دیے گئے ہیں جیسے : طلع‘ ضحک‘ اغریض‘ بسر‘ زھو‘ رطب‘ تمر‘ بلح‘ سیاب۔ یہ کوئی دس نام ہیں جو کھجور کی مختلف حالتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے بتائے گئے ہیں۔ عربوں کا یہ قاعدہ بھی تھا کہ اگر کوئی چیز انتہائی قابل قدر ہوتی یا ان کے کلام میں کثرت سے بیان ہوتی تو وہ اس کے متعدد نام رکھ دیتے‘ بعض چیزوں کے تو سوکے قریب نام بھی رکھے گئے۔ اس کی ضرورت اشعار میں قافیہ کی پابندی کی بنا پر پیش آئی۔ اگر عربی زبان میں یہ وسعت نہ ہوتی تو ان کا قافیہ تنگ ہو جاتا اور نظم و نثر میں گرہ لگ جاتی۔
اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیلیوں کی زبان میں تو ایک معنی کو بیان کرنے کے لیے غالباً ایک ہی لفظ بولا گیا ہو لیکن ہماری زبان میں اس عبرانی لفظ کی تعبیر کے لیے ایک سے زائد اسماء ہوں تو وہ سارے کے سارے اسماء عربی زبان میں لائے گئے ۔ اب چاہے اسے مترادف اسماء مراد لے لیا جائے یا یہ کہا جائے کہ ہر ایک اسم سے عبرانی لفظ کی تعبیر کی گئی ہے۔
(۵) اب رہا سورۃ النمل میں ’’اَوْ اٰتِیْکُمْ‘‘ کی تکرار تو یہاں ایک واقعہ کی تاکیدکی گئی ہے۔ یہاں معاملہ کسی امر یا نہی کا نہیں ہے‘ صرف ایک خبر کو مؤکد بنانا ہے کہ جس سے اس خبر کی سچائی کو ظاہر کیا گیاہے۔
اب چونکہ یہاں ایک واقعہ کی حکایت حال مقصود ہے تو ا س سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک جگہ کسی لفظ کی تکرار ہو اور دوسری جگہ تکرار نہ ہو‘ اصل مقصود یعنی واقعہ کی سچائی کو ظاہر کرنا ہے اور عربی زبان کے اسلوب کے مطابق اس قسم کی تکرار میں کوئی حرج نہیں ہے۔
(۶) جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آخری دو سورتو ں میں لفظ ’’اصطلاء‘‘ لایا گیا جس سے مقصود آگ تاپنے کی ضرورت کا بیان تھا اور سورئہ طٰہ میں اس حاجت کا بیان نہیں کیا گیا تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک امر زائد تھا جو ان دوسورتوں میں بیان ہوا لیکن وہ سورئہ طٰہ کے بیان سے متعارض نہیں تھا۔ یہ قرآن کا ایک عام اسلوب ہے کہ ایک جگہ ایک واقعہ اختصار کے ساتھ بیان ہوتا ہے اور دوسری جگہ اسے تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے‘ یعنی دونوں بیانات کی روشنی میں پوری بات سمجھ میں آجاتی ہے۔
(۷) سورئہ طٰہ میں آگ کی طرف جانے کا سبب یہ بتایا گیا: {اَوْ اَجِدُ عَلَی النَّارِ ہُدًی} ’’یا میں آگ کے آس پاس لوگوں سے ہدایت کا راستہ پائوں۔‘‘یہاں وہ بات وضاحت سے بیان کی گئی ہے کہ جس کی طرف سورۃ النمل اور سورۃ القصص میں یہ کہہ کر اشارہ کیا گیا تھا کہ ’’میں تمہارے لیے ایک خبر لے کرآتا ہوں‘‘ وہ اس لیے کہ انہیں اور ان کی اہلیہ کو سوائے آگ تاپنے اور راستہ معلوم کرنے کے اور کسی چیز کی حاجت نہ تھی‘ اس لیے سورئہ طٰہ میں تو اس کا کھل کر بیان ہو گیا اور باقی دونوں سورتوں میں اس کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اور ایک قصے کی حکایت کرتے وقت اس قسم کا اختلاف کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے‘ تو اسے تعارض نہ سمجھا جائے۔
یہاں تک تو پہلے سوال کی مختلف شقوں کا جواب تھا‘اب دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ہر سورت میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ اسی سورت میں آنے کے لائق تھا۔
اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو الفاظ جس سورت میں آئے ہیں وہ اس کے فواصل اور مقاطع (ہر آیت کے آخری الفاظ اور حروف) کے مطابق وارد ہوئے ہیں۔ سورئہ طٰہ کے مقطع میں الف مقصورہ کثرت سے آیا ہے جیسے طٰہٰ‘ لِتَشْقٰی‘ تَخْشٰی اور سورت کے آخر تک یہ مقطع چلا جاتا ہے (آخری آیت میں ہے: اھْتَدیٰ) اور سورۃ النمل اور سورۃ القصص کا مقطع ہے : یاء نون (جیسے مُبِیْن‘ مُؤْمِنِیْن) یا وائو نون (جیسے یُوْقِنُوْنَ‘ یَعْمَھُوْنَ) ‘ یاء ہو تو اس سے قبل کسرہ ہوگا اور اگر وائو ہو تو ا س سے پہلے ضمہ ہو گا۔
اور اگریہ کہا جائے کہ دونوں سورتیں تقریباً برابر ہیں (سورۃ النمل کی ۹۳ آیات ہیں اور سورۃ القصص کی ۸۸) تو پھر دونوں کی عبارات میں فرق کیوں واقع ہوا ہے ؟ جواب یہ ہے کہ دونوں میں اختصار کا اور طوالت کا فرق ہے۔ سورۃ النمل کی صرف آٹھ آیات میں یہ قصہ بیان ہوا ہے اور سورۃ القصص کا تو بڑا حصہ (تقریباً پچاس آیات) اسی قصے پر مشتمل ہے۔ اور یہ قاعدہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ جہاں ایجاز اور اختصار ہو وہاں الفاظ کے چنائو میں وہ طوالت نہیں ہوتی جو کہ ایک تفصیلی مکالمے میں ہو سکتی ہے۔
سورئہ طٰہ کے ابتدائی کلمات ہی کو دیکھ لیں ‘ وہاں خطاب ہمارے نبیﷺ سے ہے:
{مَـآ اَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓی(۲) }
’’ہم نے قرآن آپؐ پر اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپؐ مشقت کا شکار ہو جائیں۔‘‘
گویا نبیﷺ سے انسیت کا اظہار ہو رہا ہے اور پھر اسے موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے جوڑ دیا گیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں صحراء میں راستہ پانے کے اسباب مہیا کر دیے تاکہ وہ آسانی سے اپنی منزلِ مقصود تک پہنچ سکیں۔
اسی طرح باقی دونوں سورتوں میں بھی سورتوں کے مجموعی نظام سے ان آیات کا تناسب اور ملائمت ظاہر ہوجاتی ہے۔ یعنی ہر سہ سورت میں جو آیات وارد ہوئی ہیں وہ وہیں مناسبت رکھتی ہیں اور اگر انہیں دوسری جگہ رکھا جاتا تووہ مناسبت نہ پیدا ہوتی۔ واللہ اعلم!
(۲۴۲) آیت ۱۵
{اِنَّ السَّاعَۃَ اٰتِیَۃٌ اَکَادُ اُخْفِیْھَا}
’’بے شک قیامت آنے والی ہے جسے میں قریب قریب پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں‘‘
اور سورئہ غافر(المؤمن) میں ارشاد فرمایا:
{اِنَّ السَّاعَۃَ لَاٰتِیَۃٌ لَّا رَیْبَ فِیْھَا} (آیت۵۹)
’’بے شک قیامت آنےوالی ہے ‘ اس میں کوئی شک نہیں‘‘
سوال کرنےوالا یہ سوال کر سکتا ہے کہ دونوں سورتوں میں قیامت کے آنے کا وصف بیان ہوا ہے لیکن دونوں میں اختلاف ہے‘ ایک میں ہے : {اَکَادُ اُخْفِیْھَا} اور دوسرے میں ہے : {لَا رَیْبَ فِیْھَا}اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سورئہ غافر کی آیت میں حرفِ لام ’’اٰتِیَۃٌ‘‘ پر اضافہ کیا گیا ہے؟
پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ سورئہ طٰہ کی ابتدا ہی اس بات سے ہو رہی ہے کہ نبیﷺ کو کفار کے کفر اور عناد کے مقابلے میں تسلی دی جائے‘چنانچہ شروع ہی میں ارشاد فرما دیا:
{مَـآ اَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓی(۲)}
’’ہم نے آپؐ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپؐ مشقت میں پڑ جائیں۔‘‘
اس کے بعد پھر کتاب کی عظمت کا تذکرہ ہے اور پھر کتاب کے نازل کرنے والے کی تعظیم اور تکبیر ہے۔ وہ اللہ ہے‘ آسمان اور زمین کا خالق ہے‘ عرش پر مستوی ہے‘ زمین وآسمان میں جو کچھ بھی ہے‘ سب اُسی کا ہے‘ وہی عبادت کے لائق ہے اور تمام اسمائے حسنیٰ اسی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد نبیﷺ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائے سفر کے واقعات سنائے گئے اور پھر کہا کہ گو قیامت یقیناً آنے والی ہے لیکن میں خود اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں اور اس حد تک کہ مخلوق کے کان میں ا س کے آنے کی بھنک تک نہ پڑ سکے۔ یعنی وہ ان غیبی امور میں سے ہے جن کا آنا یقینی ہے اور جن پر ایمان لانا ضروری ہے‘ اور چونکہ یہ بات نبیﷺ کے گوش گزار کی جا رہی ہے جن کا قیامت پر ایمان اتنا پختہ ہے کہ یہاں اس کے بارے میں کسی شک و شبہ کی نفی کرنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی ‘کیونکہ نبی اس قوتِ ایمانی کا مالک ہوتا ہے کہ جہاں شک و شبہ کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہوتی‘ ا س لیے یہاں اس کی نفی کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔
جہاں تک سورئہ غافر کی آیت کا تعلق ہے تو شروع سورت سے اس آیت تک قریش مکہ اور تمام کفارِ عرب سے خطاب ہے جو قیامت کے بارے میں غافل تھے بلکہ اس کے واقع ہونے کے بارے میں جھگڑا کیا کرتے تھے۔ وہی تھےجنہوں نے یہ کہا:
{اِنْ ہِیَ اِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوْتُ وَنَحْیَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِیْنَ(۳۷)} (المؤمنون)
’’یہاں تو صرف ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے کہ جہاں ہم جیتے مرتے ہیں اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔‘‘
اور پھر مذکورہ آیت سے قبل اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ان الفاظ میں کیا گیا:
{ لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَکْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ} (غافر:۵۷)
’’یقیناً آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے بڑا کام ہے۔‘‘
اس طرح انہیں یاد دلایا گیا کہ تم اللہ کی عظمت کے سامنے عاجز اور مقہور مخلوق ہو‘ اور پھر جس چیز کا وہ انکار کر رہے تھے‘ اس کی آمد کے بارے میں بطور تاکید ’’ لَاٰتِیَۃٌ‘‘ کا لفظ لایا گیا ہے جس کے شروع میں لام تاکید کا اضافہ کیا گیا تاکہ اس کے آنے کے بارے میں ان کے شک و شبہ کا ازالہ کیا جا سکے۔
یوں ظاہر ہو گیا کہ ہر آیت اپنی اپنی جگہ بہترین مناسبت رکھتی ہے ‘ اور سورئہ طٰہ کی آیت سورئہ غافر میں‘ یا غافر کی آیت طٰہ میں کوئی جوڑ یا مناسبت نہ رکھتی تھی‘ واللہ اعلم!
(۲۴۳) آیات ۲۴ تا۳۶
{اِذْہَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّہٗ طَغٰی(۲۴) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ(۲۵) وَیَسِّرْ لِیْٓ اَمْرِیْ(۲۶) وَاحْلُلْ عُقْدَۃً مِّنْ لِّسَانِیْ(۲۷) یَفْقَہُوْا قَوْلِیْ(۲۸) وَاجْعَلْ لِّیْ وَزِیْرًا مِّنْ اَہْلِیْ(۲۹) ہٰرُوْنَ اَخِی(۳۰) اشْدُدْ بِہٖٓ اَزْرِیْ(۳۱) وَاَشْرِکْہُ فِیْٓ اَمْرِیْ (۳۲) کَیْ نُسَبِّحَکَ کَثِیْرًا(۳۳) وَّنَذْکُرَکَ کَثِیْرًا(۳۴) اِنَّکَ کُنْتَ بِنَا بَصِیْرًا(۳۵) قَالَ قَدْ اُوْتِیْتَ سُؤْلَکَ یٰمُوْسٰی(۳۶) }
’’اب تُو فرعون کی طرف جا‘ اُس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ موسیٰؑ نے کہا: اے میرے رب! میرے سینے کو کھول دے ‘اور میرا کام آسان کر دے ‘اور میری زبان کی گرہ کھول دے ‘تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اور میرے گھر والوںمیں سے میرا ایک وزیر بنا دے‘ ہارون میرے بھائی کو۔ اور میری کمر اس سے کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے‘ تاکہ ہم بکثرت تیری تسبیح کر سکیں‘ اور بکثرت تجھے یاد کرتے رہیں‘ بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:اے موسیٰ! جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ سب تمہیں دیا جاتا ہے۔‘‘
اور سورۃ الشعراء کی آیات میں ارشاد فرمایا:
{وَاِذْ نَادٰی رَبُّکَ مُوْسٰٓی اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ(۱۰) قَوْمَ فِرْعَوْنَ ط اَلَا یَتَّقُوْنَ(۱۱) قَالَ رَبِّ اِنِّیْٓ اَخَافُ اَنْ یُّکَذِّبُوْنِ(۱۲) وَیَضِیْقُ صَدْرِیْ وَلَا یَنْطَلِقُ لِسَانِیْ فَاَرْسِلْ اِلٰی ہٰرُوْنَ(۱۳) وَلَہُمْ عَلَیَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ یَّقْتُلُوْنِ(۱۴) }
’’اور جب تیرے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ تم ظالم قوم کے پاس جائو‘ قوم فرعون کے پاس‘ اور (انہیں بتا) کہ وہ کیوں نہیں (اللہ سے) ڈرتے! موسیٰ نے کہا: مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے‘ میری زبان کھل نہیں رہی‘ تو ہارون کی طرف بھی (وحی) بھیج! اور میں نے ان کی جانب ایک قصور کیا ہے اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔‘‘
اور سورۃ القصص کی آیات میں ارشاد فرمایا:
{اُسْلُکْ یَدَکَ فِیْ جَیْبِکَ تَخْرُجْ بَیْضَآئَ مِنْ غَیْرِ سُوْٓئٍ ز وَّاضْمُمْ اِلَیْکَ جَنَاحَکَ مِنَ الرَّہْبِ فَذٰنِکَ بُرْہَانٰنِ مِنْ رَّبِّکَ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَمَلَائِ ہٖ ط اِنَّہُمْ کَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِیْنَ(۳۲) قَالَ رَبِّ اِنِّیْ قَتَلْتُ مِنْہُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ فَاَخَافُ اَنْ یَّقْتُلُوْنِ(۳۳) ۔۔۔۔ الی قولہ ۔۔۔۔۔ ۔۔ اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَکُمَا الْغٰلِبُوْنَ(۳۵) }
’’اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال‘ وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا نکلے گا بالکل سفید اور اپنا خوف (زائل کرنے کے لیے) اپنے بازو کو اپنے پہلو سے ملا لے‘ تو یہ دونوں تیرے رب کی طرف سے دو معجزے ہیں فرعون اور اس کے حاشیہ برداروں (کو دکھانے) کے لیے۔ بے شک وہ ایک بدکار قوم ہیں۔ موسیٰ نے کہا: میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا‘ اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے....... پھر آیت۳۵ کے آخر تک جہاں فرمایا: ’’تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔‘‘
سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہےکہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ مبعوث ہونے کے بعد کن کن مراحل سے گزرتے ہوئے فرعون کے پاس پہنچے تھے اور پھر فرعون کے سامنے کیا کیا واقعات پیش آئے۔ یہ قصہ ان تینوں سورتوں میں بیان ہوا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ہر سورت میں کچھ ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں جو دوسری دو سورتوں میں بیان نہیں ہوئیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہر ایک سورت میں بیان ہوا ہے اس کی سورت کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟
پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ زبان کے اختلاف کی بناپر یہ ساری حکایت معنوی طور پر بیان ہو رہی ہے ‘یعنی جو الفاظ اس زمانہ میںادا کیے گئے ان کے معانی کو عربی زبان میں ادا کیا جا رہا ہے اس لیے الفاظ کی ادائیگی میں اختلاف کا واقع ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ ایک مضمون کو پورے کمال سے ادا کرنے کے لیے کبھی ایک تعبیر اختیار کی جاتی ہے اور کبھی دوسری‘ اور خاص طو رپر اس لیے بھی کہ عربی زبان میں کسی مفہوم کی ادائیگی کے لیے مختلف اسالیب کو اختیار کیا جا تا ہے‘ جیسے مشترک الفاظ کا اختیار کرنا‘ عموم وخصوص‘ مطلق اور مقید‘ حقیقت و مجاز اور کئی دوسرے اندازِ بیان کی صورتوں کا اعتبار کرنا شامل ہے‘ اس لیے یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ہی قصے کو مختلف عبارات میں کیوں بیان کیا گیا ہے۔
ہم تو یہ کہیں گے کہ اگر کوئی شخص کسی عربی عبارت کو معنی کا لحاظ کرتے ہوئے بیان کرے تو اس کی حکایت میں اختلاف نظر آئے گا ‘اور اگر یہ بات ایک ہی زبان کے قول میں واقع ہو سکتی ہے تو پھر ایک زبان سے دوسری زبان میں کسی بات کو نقل کیا جائے تو ایسا فرق کیوں نہیں واقع ہو سکتا۔
ان تینوں سورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے مراحل زندگی کے یہ واقعات بیان ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو کھول دے‘ ان کے فرضِ منصبی کی ادائیگی کو آسان کر دے‘ ان کی زبان کی گرہ کوکھول دے‘ تاکہ لوگ ان کی بات کو سمجھ سکیں‘ ان کے بھائی ہارون کو ان کا معاون بنا دے‘ اپنے اس خوف کا اظہار کہ لوگ انہیں جھٹلائیں گے اور ان کے ہاتھ سے ایک قبطی کے قتل کی بنا پر انہیں موردِ الزام ٹھہرائیں گے‘ اور فرعون کے سامنے ظاہر ہونے والے معجزات بیان ہوئے۔
یہی وہ سات واقعات ہیں جو ان سورتوں میں اختلافِ الفاظ کے ساتھ بیا ن ہوئے ہیں‘ اور کسی میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے تو کسی میں دوسرا‘لیکن ایسا نہیں ہے کہ واقعات کے بیان میں تعارض یا اختلاف ہو۔
اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ سورئہ طٰہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے نبی کریمﷺ کے لیے بشارت‘ تسلی اور اطمینان کا اظہار ہو۔اس کی ابتدا ’’رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ‘‘ سے ہوتی ہے کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا بیان ہوا ہے۔ شروع سورت میں {مَـآ اَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓی(۲)} کہہ کر نبیﷺ کو تسلی دی گئی تھی اور پھر آخر سورت میں نبیﷺ کی دلجوئی پر یہ سورت ختم ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمایا: {لَا نَسْئَلُکَ رِزْقًاط نَحْنُ نَرْزُقُکَ ط } (آیت ۱۳۲)’’ہم تم سے رزق نہیں مانگتے‘ یہ تو ہم ہیں جو تمہیں رزق بہم پہنچاتے ہیں۔‘‘اور پھر آخر میں دشمنانِ رسول کو یوں دھمکی دی گئی:{قُلْ کُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوْاج} (آیت ۱۳۵)’’آپؐ کہہ دیجیے‘ ہر ایک اپنےانجام کا منتظر ہے تو تم بھی انتظار کرو!‘‘تو یہ وہ وجہ ہو گئی کہ مذکورہ آیات سورئہ طٰہ ہی سے مناسبت رکھتی ہیں۔
جہاں تک سورۃ الشعراء اور سورۃ القصص کا تعلق ہے تو دونوں سورتیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعاتِ زندگی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔اب ملاحظہ ہو کہ سورۃ الشعراء میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں:موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی طرف بھیجا جانا اور اسے رب کی طرف دعوت دینا‘فرعون کا ان کے ساتھ کج بحثی کرنا‘ فرعون کا بنی اسرائیل میں سے لڑکوں کا ذبح کرنا اور لڑکیوں کو خدمت کرنے اور ذلت کی زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دینا‘ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو اس ذلت کی زندگی سے نجات دلوانا۔ اس قصے کے بیان میں موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی‘ مصر سے بھاگ کر مدین جانا‘ شعیب علیہ السلام سے ملاقات اور فرعون کی طرف آنا۔ پھر فرعون کا قومِ موسیٰ کا پیچھا کرنا اور بالآخر ڈوب کر ہلاکت کی موت مرنا‘ یہ سب واقعات بیان ہوئے ہیں۔
سورۃ الشعراء میں چونکہ کئی رسولوں کا بیان ہوا ہے اور اس بات پر خاص طور پر زو ر دیا گیا ہے کہ جن قوموں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا‘ تو پھر ان کا انجام کیا ہوا‘ اور اسی لحاظ سے قومِ فرعون کے اپنے بدانجام کو پہنچنا اس سورت کے مرکزی مضمون سے مناسبت رکھتا ہے۔
جہاں تک سورۃ القصص کا تعلق ہے تو اس میں بھی نبیﷺ کی تسلی اور دلجوئی ملحوظ رکھی گئی ہے۔ شروع ہی میں فرما دیا تھا:{نَتْلُوْا عَلَیْکَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰی وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ} (آیت ۳) ’’ہم آپؐ کو سناتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا صحیح صحیح واقعہ!‘‘اور ان واقعات کے سنانے سے مقصود کیا ہے‘ اسے سورئہ ہود میں یوں بیان کیا:{وَکُلًّا نَّقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ اَنْبَآئِ الرُّسُلِ مَا نُثَـبِّتُ بِہٖ فُؤَادَکَ ج } (آیت۱۲۰) ’’رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔‘‘ اور سورت کے آخر میں آپﷺ کو اس بات کی تسلی دی گئی کہ جس مکہ سے وہ اپنی قوم کی بنا پر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے‘ بالآخر ایک دن وہاں واپس آئیں گے۔ فرمایا:{اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّکَ اِلٰی مَعَادٍط}(القصص:۸۵)’’ جس نے آپؐ پر قرآن (کی دعوت و تبلیغ) فرض کی تھی وہ آپؐ کو دوبارہ اپنی جگہ لانے والا ہے۔‘‘ یہاں مناسبت ہے موسیٰ علیہ السلام کے اپنے مولد مصر سے نکالے جانے اور پھر مدین ہو کر واپس لوٹائے جانے سے! اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر سورت میں جو آیات آئی ہیں وہ اسی سورت سے پوری مناسبت رکھتی ہیں‘ واللہ اعلم!
(۲۴۴) آیت ۴۷
{فَاْتِیٰـہُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّکَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِیْٓ اِسْرَآئِ یْلَ ۵}
’’تم دونوں اس کے پاس جائو اور کہو کہ ہم دونوں تیرے رب کے پیغامبر ہیں تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو۔‘‘
اور سورۃ الشعراء میں ارشاد فرمایا:
{فَاْتِیَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ(۱۶) اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِیْٓ اِسْرَآئِ یْلَ(۱۷)}
’’تو پھر فرعون کے پاس جائو اور (اس سے) کہو کہ ہم جہانوں کے رب کے پیغامبر ہیں‘ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو!‘‘
یہاں دونوں آیتوں کی عبارت میں ذرا سا اختلاف ہے‘ ملاحظہ ہو:
سورئہ طٰہٰ
سورۃ الشعراء
(۱)
فَاْتِیٰـہُ(ضمیر سے فرعون مراد ہے)
فَاْتِیَا فِرْعَوْنَ (فرعون کا نام کے ساتھ ذکر ہے)
(۲)
اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّکَ (رسولًا: تثنیہ ہے اور اس کے بعد ’’رَبِّکَ‘‘ یعنی ضمیر خطاب ہے)
اِنَّا رَسُوْلُ (رسول مفرد ہے)
رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (صراحت کے ساتھ کہا گیا)
موسیٰ علیہ السلام کی حکایت کے دو مرحلے ہیں۔ پہلے جب کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مدین سے صحرائے سینا میں سفر کر رہے تھے۔ یہاں صرف انہی سے خطاب کیا گیا ہے اور فرعون کے پاس جانے کی ہدایت کی گئی ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی طلب کا ذکر کیا گیا ہے۔اور دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں ان کی طلب پوری کر دی گئی ہے اور پھر موسیٰ اور ہارون علیہما السلام دونوں سے خطاب ہے۔ یہ وہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں عبارت کا اختلاف پیدا ہوا ہے تو اس کی وضاحت مطلوب ہے۔
جواباً ارشاد ہے کہ ایک تو وہی بات جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ یہاں زبان کے اختلاف کی بنا پر لفظ بلفظ حکایت نہیں کی جا رہی ہے بلکہ اس کے مضمون اور مقصود کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کی بنا پر الفاظ میں اختلاف کا ہونا ایک طبعی امر ہے۔ رہی دوسری بات کہ سورئہ طٰہ میں بجائے فرعون کے نام کے اس کی ضمیر لائی گئی ہے تو وہ اس لیے کہ سورئہ طٰہ میں مذکورہ آیت سے چند آیات قبل فرعون کا صریحاً ذکر آ چکا ہے‘ جہاں ارشاد ہوا تھا:
{اِذْہَبَآ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّہٗ طَغٰی(۴۳) فَقُوْلَا لَہٗ قَوْلًا لَّیِّنًا} (آیت۴۴)
’’تم دونوں فرعون کے پاس جائو‘ وہ سرکشی کر رہا ہے‘ تو تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا!‘‘
تو اس کے معاً بعد آیت ۴۷ میں دوبارہ اس کا نام لانے کی ضرورت نہ تھی‘ اس لیے ضمیر لائی گئی اور کہا گیا : ’’فَاْتِیٰہُ‘‘ اور جہاں تک سورۃالشعراء کی آیت کا تعلق ہے تو وہاں پہلے آیت ۱۰ میں کہا گیا تھا :
{وَاِذْ نَادٰی رَبُّکَ مُوْسٰٓی اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِیْنَ(۱۰) قَوْمَ فِرْعَوْنَ ط }
’’اور جب تیرے ربّ نے موسیٰ کو آواز دی کہ تم ظالم قوم‘ قومِ فرعون کے پاس جائو۔‘‘
اس کے بعد چار اور آیات ہیں جن میں موسیٰ علیہ السلام اور اللہ ربّ العالمین کے درمیان بات چیت کا ذکر ہے اور پھر دوبارہ کہا گیا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جائو۔ تو یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ’’ فَاْتِھِمْ‘‘ (تو ا ن کے پاس جائو) لیکن ان دونوں آیات میں فصل پیدا ہو چکا ہے‘ اس لیے بجائے ضمیر کے فرعون کا نام کے ساتھ ذکر ضروری تھا‘ اور چونکہ فرعون کے نام کے ساتھ اس کی قوم کا ذکر ذہن میں خود بخود آجاتا ہے اس لیے صرف فرعون کہہ دینا بھی کافی تھا۔
دوسری بات یہ کہ سورئہ طٰہ میں رَسُوْلَا (تثنیہ)ہے اور سورۃ الشعراء میں (رَسُوْلُ) مفرد ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ عام قاعدے کے اعتبار سے اگر دو آدمی ہوں تو ان کے لیے تثنیہ کا لفظ لانا معروف ہے‘ لیکن لفظ رَسُوْل اہل عرب کے نزدیک مفرد‘ تثنیہ اور جمع بلکہ مذکر اور مؤنث سب کے لیے آ سکتا ہے۔جیسے کہ ذئویب ھُذَلی کے اس شعر میں استعمال ہوا ہے۔ ؎
ألکنی الیھا وخیرُ الرسُولِ
اَعْلَمُھُمْ بِنَواحیِ الخَبَر
’’ مجھے اس کی طرف بھیجو اور بہترین پیغامبر وہ ہیں جو خبر کا پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہوں۔‘‘
تووہ ایک جگہ معروف و مشہور لغت کے اعتبار سے آیا ہے اور دوسری جگہ ایک دوسری قدرے غیر معروف لغت کے اعتبار سے آیا ہے‘ اور جو لفظ جہاں آیا ہے سیا ق و سباق کے اعتبار سے اس کا وہاں آنا ہی مناسب تھا۔
اب رہی دوسری بات کہ فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے وہ دونوں کہتے ہیں:’’اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّکَ‘‘ ہم دونوں تیرے ربّ کے پیغامبر ہیں۔ یعنی ربّ کی طرف نسبت کے ساتھ اپنا تعارف کر ارہے ہیں تو خیال رہے کہ سورئہ طٰہ میں نبیﷺ کی دلجوئی اور تسلی مطلوب ہے اور اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ایسے اسلوب کو اپنایا گیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے باعث ِشفقت اور اُنس تھا۔ جیسے ارشاد ہوا:
{وَاَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوْحٰی(۱۳)} (طٰہٰ)
’’اور میں نے تمہیں چن لیا ہے تو پھر کان لگا کر سنو کہ کیا وحی کی جا رہی ہے۔‘‘
اور پھر ان کے سوال کے جواب میں یہ بشارت دی جاتی ہے:
{قَدْ اُوْتِیْتَ سُؤْلَکَ یٰمُوْسٰی(۳۶) } (طٰہٰ)
’’اے موسیٰ ! تمہیں تمہارے تمام مطالب عطا کر دیے گئے۔‘‘
اور پھر موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو فرعون کے پاس جانے اور نرمی سے خطاب کرنے کی تلقین کی گئی:
{فَقُوْلَا لَہٗ قَوْلًا لَّیِّنًا} (طٰہٰ:۴۴)’’تو پھر تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا۔‘‘
اور یہی انداز سورۃ النازعات کی آیات میں بھی جھلک رہا ہے:
{فَقُلْ ہَلْ لَّکَ اِلٰٓی اَنْ تَزَکّٰی(۱۸) وَاَہْدِیَکَ اِلٰی رَبِّکَ فَتَخْشٰی(۱۹)}
’’تو اس سے کہنا کہ آیا تم پاک ہونا چاہتے ہو؟ اورمَیں تمہیں تمہارے ربّ کی طرف جانے کا راستہ سجھائوں تو پھر تم میں کچھ ڈر پیدا ہو گا!‘‘
اور اسی اسلوب کو اس قول میں بھی اپنایا گیا ہے :’’اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّکَ‘‘ کہ ہم دونوں تیرے ربّ کے پیغامبر ہیں۔
اب آیئے سورۃ الشعراء کی طرف جہاں سختی کا اسلوب ہے‘ فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو کر ہلاک کیے جانے کا ذکر ہے‘ وہاں بجائے ’’رَبِّکَ‘‘ (یعنی تیرے ربّ کی طرف نسبت) ربّ العالمین کہا گیا:
{فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ(۱۶) }
’’تو پھر تم دونوں کہنا کہ ہم تمام جہانوں کے ربّ کے پیغامبر ہیں۔‘‘
یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اُس ربّ کے پیغامبر ہیں جو ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز اور ہر شخص اُس کے قبضہ ٔ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہاں ضمیر خطاب نہیں لائی گئی کہ یہاں دلجوئی اور تسلی مقصود نہیں ہے۔
اس سے ملتا جلتا اسلوب سورۃ الانعام کی ان دو آیات میں ملاحظہ ہو:
{وَلَوْ شَآئَ رَبُّکَ مَا فَعَلُوْہُ} (الانعام:۱۱۲)’’اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے‘‘
یہاںنبیﷺ کی دلجوئی مقصود ہے‘ اور پھر ایک طویل بیانیہ ہے جس میں مشرکین کے گھنائونے کاموں کو گنوایا گیا ہے اور اس کے آخر میں ارشاد فرمایا:
{وَلَوْ شَآئَ اللہُ مَا فَعَلُوْہُ} (الانعام:۱۳۷)’’اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا کچھ نہ کرتے۔‘‘
یعنی جو آیت جہاں آئی ہے وہاں بہترین مناسبت رکھتی ہے ‘اور اگر اس کا اُلٹ کیا جاتا تو قطعاً مناسب نہ ہوتا۔ واللہ سبحانہ اعلم!