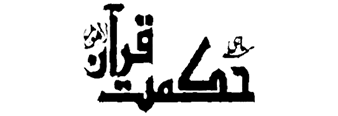(فکر و نظر) ہمارے عقائد پر جدید تعلیم کے اثرات - ڈاکٹر محمد رشید ارشد
9 /ہمارے عقائد پر جدید تعلیم کے اثراتپروفیسر ڈاکٹر رشید ارشد
اس موضوع کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ’’ہمارا تعارف کیا ہے اور ہمارا تصورِ علم کیا ہے؟‘‘ دوسرا حصہ ’’جدید تصورِ علم اور ہمارے عقائد پر اس کے اثرات۔‘‘
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا بنیادی تعارف ’’عبداللہ‘‘ کا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہی ہمارا جوہر اور ہماری اصل ہے۔ ایک عرصے سے ہمارے ہاں فیشن سا بن گیا ہے اور یہ بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے کہ ہمارا اوّلین تعارف انسان ہونا ہے جبکہ مسلمان‘ عیسائی‘ ہندو‘ سکھ اور پارسی ہونا بعد کا ایک تعین ہے۔اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسانیت کو ہم اپنے’’جوہر‘‘کے طور پر دیکھتے ہیں‘حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہمارا جوہر حقیقت میں انسان ہونا نہیں بلکہ’’عبد‘‘ یعنی بندہ ہونا ہے۔ فلسفے اور منطق میں وجود کے متعلق دو اصطلاحات ’’واجب الوجود‘‘ اور ’’ممکن الوجود‘‘ استعمال ہوتی ہیں۔ واجب الوجود کا ہونا لازمی ہے اور نہ ہونا ناممکن ہے۔ یہ وہ وجود ہے جو اپنی بنیاد پر خود سے قائم ہے۔ فلسفے میں اس کو necessary being کہا جاتا ہے۔ ایک ہے ممکن الوجود جس کو contingent being کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاں عدم اور وجود برابر ہو‘ یعنی جو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہوسکتا۔ جو نہیں تھا‘ پھر ہوا‘ پھر نہیں ہوگا ‘یہ ممکن الوجود ہے۔ لہٰذا جس طرح اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اور مخلوق ممکن الوجود ہے‘ اسی طرح اللہ اور ما سوا اللہ میں ایک ہی نسبت ہے کہ وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں۔ یہی نسبت یہاں اس طرح سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے ‘باقی سب عبد ہیں۔
ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اس بات کو دیکھنا ہے کہ اس وجود یعنی ہستی کے تصوّر کا میری بندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اگر میں بنیادی طور پر ایک مذہبی وجود ہوں تو اب مجھے ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھنا ہے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ میں اختیار کر رہا ہوں‘چاہے وہ کوئی چیز ہو یا کوئی تصوّر‘ یہ میرے مذہبی وجود کو یامیری بندگی کے وجود کو کہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا‘ اس کو متاثر تو نہیں کر رہا۔ یہ گویا میرا سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے۔ اصولِ فقہ میں مقاصد ِ شریعت بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حفظِ دین یا حفظِ ایمان ہے‘ پھر حفظِ نفس یا حفظِ جان‘ اس کے بعد حفظِ نسل‘ حفظِ مال اورحفظِ آبرو ہیں۔ یہ درجہ بندی اس اعتبار سے ہے کہ شریعت کے سارے احکام ان پانچ میں سے کسی نہ کسی درجے کے تحت آئیں گے۔لہٰذا یہاں یہ دیکھنا اہم ہے کہ سب سے بڑا فرض ایمان بچانا ہے۔ یہاں تک تو ہماراتعارف تھا کہ ہم ’’اللہ کے بندے‘‘ ہیں۔ اب ہم تصوّرِ علم کی طرف آتے ہیں۔تعلیم کے اندر غیر معمولی تاثیر ہوتی ہے ‘یعنی اس کا پورا عمل انسان کی تشکیل کرتا ہے۔انسان کاظاہری وجود اس کے ماں باپ کا پروردہ ہوتا ہے‘ اور باطنی وجود کی پرورش معلم کرتا ہے۔بقول علامہ اقبال:
شیخِ مکتب ہے اک عمارت گر
جس کی صنعت ہے روحِ انسانی
اور تعلیم کی تاثیرپرعلامہ اقبال کا شعر دیکھیے:
تعلیم کے تیزاب ميں ڈال اس کی خودی کو
ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے‘ اسے پھیر
تاثیر ميں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب
سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے اک ڈھیریہاں علامہ اقبال جس تعلیم پر گفتگو کر رہے ہیں اس کی تاثیر منفی ہے‘یعنی یہ تعلیم سونے کے پہاڑ کو مٹی بنا دیتی ہے ‘اور اس کا برعکس بھی ٹھیک ہے کہ مٹی کا ایک ڈھیر ہو اس کو تعلیم دے دیں‘ شعور دے دیں تو وہ سونے کا ہمالہ بن سکتا ہے۔ ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں:
اور یہ اہلِ کلیسا کا نظامِ تعلیم
ایک سازش ہے فقط دین و مروّت کے خلافیہاں کلیسا سے مراد چرچ نہیں بلکہ جدید مغرب ہے۔
شعور اور و جود کی ایک پرانی تقسیم ہے‘ یعنی انسان کی شخصیت میں ایک وجود ہے اور ایک شعور ہے‘ ایک علم ہے اور ایک اخلاق ہے۔ یہ تقسیم دنیا کی ہر روایت میں ملے گی۔ قرآنِ مجیدمیں جگہ جگہ ایمان اور عملِ صالح کا ایک جوڑا نظرآتا ہے۔ ایمان کا تعلق فکر‘ شعوراور تصور سے ہے جبکہ عمل صالح کا تعلق وجود‘ اخلاق اور عمل سے ہے۔ علامہ اقبال کے خطبات The Reconstruction of Religious Thought in Islam کے ابتدائیہ کا پہلا جملہ ہی یہی ہے کہ:
The Islam is a religion which emphasizes ‘deed’ rather than ‘idea’.
اسلام کا تصوّرِ علم
اسلام میں علم سے مراد ہے کہ انسان یہ جان لے کہ وہ مخلوق ہے‘ وہ فانی ہے‘ اور یہ بھی جان لے کہ کائنات مخلوق ہے اور فانی ہے۔ مرنے کے بعد ایک عالم برپا ہوگا اور وہاں پر ایمان اور عملِ صالح کی بنیاد پر احتساب ہوگا۔ پھر یا تو ابدی راحتیں ہیں یا ابدی سزا ہے۔ قرآن مجید جس کو ’’العلم‘‘ کہتا ہے اس سے مراد یہ علم ہے۔ وہ صرف ونحو‘ منطق اور فقہ کا علم بھی نہیں ہے‘ اور نہ ہی وہ قرآن اور حدیث کا ٹیکنیکل معنوں میں یعنی تفسیر اور علم ِ حدیث کا علم ہے۔ امام بخاریؒ نے ’’الجامع الصحیح‘‘ میں ایک ترجمۃ الباب قائم کیا ہے: العِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ‘ کہ کچھ کہنے اور کرنے سے پہلے ایک علم ہے۔ اس کے شروع میں وہ سورۂ محمد کی آیت لے کرآئے ہیں: {فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ} (آیت۱۹)’’جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے‘‘۔ اسی طرح ہمارا تصورِ علم تو یہ ہے:{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ط}(الزمر:۹) ’’کہو کہ: کیا وہ جو جانتے ہیں اور جونہیں جانتے سب برابر ہیں؟‘‘ یہاں جاننے والے اور نہ جاننے والے سے مراد فزکس‘ کیمسٹری‘ بیالوجی‘ جیالوجی اور اسٹرانومی جاننے والے یا نہ جاننے والے نہیں ہیں۔ یہاں مبحث وہی ہے جو قرآنِ مجید دوسری جگہ کہتا ہے:{وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ(۷)} ’’لیکن یہ منافق لوگ نہیں سمجھتے‘‘ اور {وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ(۸)}(المنافقون)’’لیکن یہ منافق لوگ نہیں جانتے۔‘‘ تو وہ کون سا تفقہ ہےجس کی بات قرآن کر رہا ہے؟ دُنیاوی معاملات میں تو وہ لوگ بہت سمجھ دار تھے‘ چال بازیاں آتی تھیں‘ لہٰذا کیا چیز ان کے پلے نہیں پڑ رہی: {يُخٰدِعُوْنَ اللهَ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ(۱۲)} (البقرۃ) ’’وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو (واقعی) ایمان لاچکے ہیں دھوکا دیتے ہیں اور (حقیقت تو یہ ہے کہ) وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکا نہیں دے رہے لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔‘‘ہماراکل تصوّرِ علم یہ ہے۔
بطورِ مثال ایک واقعہ ملاحظہ ہو۔کسی نے امام حسن بصریؒ سے کہا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں اور فلاں فقیہہ یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا:
ثَكِلَتْك أُمُّك، وَهَلْ رَأَيْت فَقِيهًا بِعَيْنِك؟ إنَّمَا الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ، الْبَصِيرُ بِدِينِهِ الْمُدَاوِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ، الْوَرِعُ الْكَافُّ عَنْ أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ، الْعَفِيفُ عَنْ أَمْوَالِهِمْ النَّاصِحُ لِجَمَاعَتِهِمْ.(رد المحتار على الدر المختار،ج:۱، ص:۳۷)
’’تمہاری ماں تمہیں روئے‘ تم نے کبھی زندگی میں فقیہہ دیکھا بھی ہے یا بس صرف فقاہت کا نام ہی سن لیا ہے؟ فقیہ تو وہ ہے جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے‘ آخرت کی طرف رغبت کرتاہے‘ اپنے دین کی بصیرت رکھتا ہے‘ اپنے رب کی بندگی پر مداومت کرتا ہے‘ صاحبِ ورع ہے یعنی شبہات سے بچتا ہے‘ مسلمانوں کی عزتوں کو بے آبرو کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے‘ ان کے اموال کے بارے میں عفت مآب ہے اور ان کی جماعت کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہے۔‘‘
ماقبل کی گفتگو میں ’’العلم‘ ‘کی تعریف سامنے آئی‘ لیکن اس کے علاوہ اور بھی علوم ہیں۔ اگر آپ اس کی درجہ بندی اور مراتب سمجھنا چاہیں تو امام غزالی کی کتاب ’’إحیاء علوم الدین‘‘ کے پہلے باب ’’کتاب العلم‘‘ کو تفصیل سے پڑھ لیں۔ اگر اختصار مطلوب ہو تو امام غزالی کی علمی سوانح ’’المنقذ من الضلال‘‘ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو انگریزی میں Deliverance from Error کے نام سے چھپا ہے۔ اردو میں بھی اس کے کئی تراجم موجود ہیں۔ اس میں امام غزالی نے علوم کی اقسام بتائی ہیں‘ اس کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے اس میں فلسفے اور اس کی اقسام مثلاً‘ الدهریون‘ طبیون‘ الٰهیون وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب بڑے فاضل آدمی تھے۔ انہوں نے ایک اصطلاح متعارف کروائی’ ’علم بالوحی‘ ‘۔یہ متن یعنی قرآن وسُنّت کا علم ہے۔ ایک علم ہے’ ’انسانی استعداد کا زائیدہ علم‘‘ یعنی وہ علم جو انسانی استعداد سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک Revealed Knowledge ہے اور ایک Acquired Knowledge ہے۔ Revealed کے مقابلے میں تسلیم سے بات شروع ہوگی۔ تسلیم‘ تفہیم‘ تعمیل اور ایک اور لفظ ہمارے استاذ کہتے تھے تحویل‘ کہ سب سے پہلے آپ مان لیں‘ پھر سمجھیں‘ پھر اس پر عمل کریں اور پھر تحویل کو وہ حال کے معنیٰ میں بیان کرتے ہیں‘ حالانکہ یہ معروف استعمال نہیں ہے۔ تحویل کا مطلب تو مڑنے کا ہوتا ہے ‘جیسے تحویلِ قبلہ وغیرہ۔ چنانچہ تحویل اس معنوں میں کہ جیسے اس کو اپنا حال بنالیں۔
اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ ہمارے علوم کی نوعیت کیا ہے تو ایمان یعنی ہمیں کچھ ماننا ہے‘ اسلام کا مطلب ہمیں کچھ کرنا ہے اور احسان کے معنی ہیں کہ ہمیں کچھ بننا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ: إنَّ الصِّدْقَ یُنْجِی والْکَذِبَ یُهْلِکُ ’’سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔‘‘ یہ گویا ایمان کی سطح پرہے۔ پھر آپ کو سچ بولنا ہے اور جھوٹ سے بچنا ہے ۔یہ ایک عمل ہے ۔پھر آپ کو سچا بننا ہے۔ سچ بولنا اور سچا بننا ایک نہیں ہے‘ یہ وہی وصف ہے کہ جس کے بارے میں ترمذی شریف میں اللہ کے نبیﷺ کے الفاظ نقل ہوئے ہیں کہ ایک انسان سچ بولتا ہے اور بولتا رہتاہے ‘ سچ کا اہتمام کرتا ہے یہاں تک کہ: ((یُکْتَب عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّیقًا))’’اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے۔‘‘یہ جو بننے کا عمل ہے‘ ہونے کا عمل ہے‘ یہ ہمارے ہاں علم کا آخری درجہ ہے کہ وہ علم ہم نے قبول کیا‘ اس کے بعد اس پر عمل کیا اور پھر اس کو اپنا حال بنایا۔ لہٰذا یہ ہمارے ہاں علم کا تصوّر ہے۔ جو دوسرے علوم ہیں ہم ان کو بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ انہیں بھی حاصل کرنا چاہیے‘ لیکن جب ہم ’’العلم‘‘ بولتے ہیں یا ہماری روایات میں آتا ہے اس سے قال الله اور قال الرسول مراد ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دنیا کے باقی علوم حاصل کریں۔
مثال کے طور پر ارسطو کو اگر آپ پڑھیں تو وہ سب سے پہلے علم کے مقاصد پر بات کرتا ہے کہ مقاصدِ علم کیا ہیں۔ ارسطو نے سب سے بنیادی مقصد ’’سعادت‘‘ قرار دیا ہے۔ عام طور پر اس کا ترجمہ happiness کیا جاتا ہے ‘جو درست نہیں ہے۔ اصل میں سعادت Contemplation of the reality سے حاصل ہوتی ہے‘ جس کا مطلب ہے حقیقت ِکبریٰ پر غور کرنا۔ یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہTo live a moral and ethical life۔وہاں سے جو معرفت حاصل ہوئی اس کے مطابق ایک اخلاقی زندگی بسر کریں۔ ارسطو نے ’’ٹیکنے‘‘ کو تیسرا درجہ قرار دیا ہے جس کو ہمارے ہاں ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے‘ یعنی طاقت۔ اس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں تو جو ضرورتیں آپ سے وابستہ ہیں آپ ان سے اس دنیا کو تلاش کریں گے۔ آگ کی ضرورت پڑگئی تو آپ نے دو پتھر رگڑے اور اس سے آگ نکل آئی۔ اسی طرح اپنی ضرورت کے لیے آپ نے پہیہ ایجاد کر لیا۔ یہ سارے معاملات آپ اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے‘ اپنے نفس کی بقاکے لیے کرتے ہیں۔
اس وقت مغرب کا جوتصوّرِ علم ہے اس میں پہلی دو چیزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس وقت علم کا مقصود طاقت ہے‘ یعنی پیش گوئی کے ذریعے کنٹرول۔ یہ سائنس ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ فزکس اور کیمسٹری کے علم میں طے شدہ نتائج ہیں‘ بنے بنائے سانچے ہیں۔ آپ پیش گوئی کرسکتے ہیں تو اختیار بھی حاصل کرسکتے ہیں۔ آج جو مولوی لوگ ہیں ان کے پاس کون سا علم ہے؟ یہ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ یہ کرلو گے تو ایسا ہوجائے گا؟ ہمارے ہاں یہ بھی ایک تصور ہے کہ یہ بھی عروج وزوال کا ایک الٰہی قانون ہوتا ہے کہ یہ چار مراحل طے کرلیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ میں اس کو مغالطہ سمجھتا ہوں۔ عروج وزوال کے متعلق ہمارے ہاں بہت خلط ِ مبحث پیدا ہوا ہے۔دنیا میں قوموں اور قیادتوں کا بھی ایک قانونِ فطرت ہے اور وہ کوئی بھی قوم اختیار کرلے گی تو وہ عروج پر آجائے گی۔ میں اس بات کو بہت بڑا مغالطہ سمجھتا ہوں۔ جب سے ہم استعمار کا نشانہ بنے یہ بیانیہ شروع ہوا۔
مغرب کا تصوّرِ علم
یہ جو روشن خیالی ہے‘ اس کے حوالے سے ایک انسائیکلوپیڈیا چھپا تھا جو فرانسیسی فلاسفہ نے تیارکیا تھا‘ انقلابِ فرانس میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ ان فلاسفہ میں والٹیئر بھی شامل ہے۔ اس انسائیکلوپیڈیا کا چیف ایڈیٹر Denis Diderot تھا جو ایک بڑا نام ہے۔ میں اس کا ایک اقتباس یہاں نقل کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ اٹھارہویں صدی کے اختتام میں مغرب میں تصورِ علم کیا تھا۔ ۱۵۰۰ء تک جو مسلمانوں کا تصوّرِ علم میں نے ذکر کیا ہے پوری دنیا کا تصوّرِ علم تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ وہی تھا۔ عیسائیوں اور ہندوؤں کا بھی وہی تھا جو مسلمانوں کا تھا۔ اس کے جوہر میں کوئی فرق نہیں تھا۔ Denis Diderot نے اب آ کر کہا ہے:
" There are three principal means of acquiring knowledge … observation of nature, reflection, and experimentation. Observation collects facts; reflection combines them; experimentation verifies the result of that combination." (Diderot, 1784)
’’علم حاصل کرنے کے تین بنیادی ذرائع ہیں: فطرت کا مشاہدہ‘ عکاسی‘ اور تجربہ۔ مشاہدہ حقائق کو جمع کرتاہے‘ عکاسی انہیں یکجا کرنے کا کردار اداکرتی ہے‘ جبکہ تجربہ یکجا ہونے کے بعد اس کے نتیجے کی تصدیق کرتا ہے۔‘‘
سائنسی طریقۂ کار کو انہوں نے تین جملوں میں بالکل سادگی سے بیان کیا‘ جیسے دوسری تیسری کلاس کے بچے کو سمجھاتے ہیں۔ اگلا جملہ جان لاک کا ہے جو بڑے فلسفی ہیں‘ کہتے ہیں:
" No man's knowledge can go beyond his experience."
’’کسی انسان کا علم اس کے تجربے سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔‘‘
یعنی جو حسیات اور جو تجربے ہیں کوئی آدمی اس سے ماورا نہیں جا سکتا۔علامہ اقبال نے اس تھیسز کو اپنے خطبات میں قبول کر لیا اور پھر بتایا کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ علم کا تجربی ہونا ضروری ہے۔ کانٹ نے اپنے تئیں جس طریقے سے آ کر خدا کے وجود کے دلائل کو اڑا کر رکھ دیا‘ علامہ اقبال نے اس کو own کیا کہ علم وجودی‘ Ontological Cosmological and Teleological دلائل نہیں چلیں گے۔ علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے علم تجربے سے ہوگا‘ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تجربہ ہوتا ہے فزیکل سینس کے ذریعے اور ایک تجربہ ہوتا ہے روحانی یا مذہبی۔ یہاں سے ان کا تھیسز شروع ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ جب اخلاقیات(Ethos) وہی ہے تو مجھے بھی اسی پر کسی طریقے سے اپنی روایت کھڑی کرنی چاہیے تاکہ بچت ہو جائے ورنہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ جان لاک کے بعد کانٹ آتے ہیں:
" All our knowledge begins with the senses, proceeds then to the understanding, and ends with reason. There is nothing higher than reason. "
’’ہمارا تمام علم حواس سے شروع ہوتا ہے‘ پھر ادراک کی طرف بڑھتا ہے‘ اور عقل پر ختم ہوتا ہے۔ لہٰذا عقل سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔‘‘
ان کے جدید تہذیب کے پیغمبر یہ باتیں کر رہے ہیں۔یہ ہلکے لوگ نہیں ہیں۔ فلسفہ ڈیپارٹمنٹ میں یا پولیٹیکل سائنس میں جان لاک کا بہت بلند درجہ ہے ۔ اسی طرح فلسفے میں کانٹ کا ایک اعلیٰ مقامہے۔ تو کانٹ نے بڑی صفائی سے کہا کہ علم کا آغاز حواس سے ہوتا ہے اور اس کی انتہا اور تکمیل میرے ذہن میں ہوتی ہے۔ اس کے بہت عرصے بعد ایک فرانسیسی فلسفی لیوتار آیا‘ جس نے ۱۹۷۹ء میں ایک کتاب لکھی۔ لیوتار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا early theorist ہے۔ اس کی کتاب ہے:
The Postmodern Condition: A Report on Knowledge
اگرچہ مابعد جدیدیت کی تعریف بہت مشکل ہے‘ یعنی وہ اپنی جوہر میں ایسا ہے کہ ڈیفائن نہیں ہونا چاہتا‘ مگر لیوتار نے اپنی اس کتاب میں عام طور پر مابعد جدیدیت کی جو تعریف جگہ جگہ کی ہے وہ بہت مشہور ہے۔ وہ تعریف یہ ہے کہ Incredulity Towards Metanarrativesیعنی ہر طرح کے مہا اور کبیری بیانیوں سے بداعتمادی۔ اس کتاب میں انہوں نے چند باتیں کہیں۔ ایک اس نے کہا کہ اب علم میں سب سے اہم چیز performativity ہے۔یعنی یہ جو تصور تھا کہ ایک Correspondence Theory of Truth ہوتی ہے اور ایک Coherence Theory ہوتی ہے‘ اب اس کی جگہ Pragmatic Theory یعنی بس واقعاتی علم ہوتا ہے۔ ایک Formativity Criteria ہے۔ان کا کہنا ہے کہ اب Mercantilization of Knowledge ہوگا‘ یعنی علم کاروبار بن جائے گا۔ علم ایک قابل فروخت جنس بن جائے گا۔
پھر آگے کہتا ہے کہ کمپیوٹرائزیشن کا جو دور آرہاہے‘ واضح رہے کہ یہ ستر کی دہائی میں اس وقت کہا گیا تھا جب سائبر دور کا آغاز ہو رہا تھا‘ کہ اس کے بعد اب علم میں Legitimation Crisis پیدا ہو جائے گا۔ پچاس سال میں اب وہ بات مکمل ہو گئی کہ آج آدمی کے بجائے روبوٹ یا مشین ہے۔ ہم نے وہ ساری صلاحیتیں ادھر منتقل کر دیں۔ اسی طرح اس نے کہا تھا کہ اب دنیا میں جو جنگیں ہوں گی وہ ڈیٹا پر ہوں گی۔ یہ بات ۱۹۷۰ء میں کہہ دی گئی تھی کہ اب سب سے بڑا ریسورس ڈیٹا ہوگا۔ آج پروفیسر Yuval Noah Harari ڈیٹا ازم کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ آنے والے مذہب کا نام ڈیٹا ازم ہے۔چنانچہ اب اس علم کی یہ گَت بن رہی ہے جو مغرب میں وجود میں آیا ۔ اس علم میں سے انسان منہا ہو رہا ہے۔ Renaissance اور Enlightenment کا سارا آئیڈیا ہیومن ازم تھا اور وہ ہیومن ہی غائب ہوگیا۔ یعنی آپ نے معاذ اللہ‘ خدا سے غداری کی ہے تو پھر انسانیت نام کا جانور زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتا۔ The Death of God Becomes the death of Man۔ ایک صدی لگی ہے جب اس نے Death of God کا اعلان کیا تھا‘ معاذ اللہ! اب انسان کا قصہ ختم ہوگیا۔ اب ہر سال یومِ فلسفہ منایاجاتا ہے ‘ غالباًنومبر یا اکتوبر کی تیسری جمعرات کو۔ اس میں ایک تھیم دیتے ہیں۔دو سال پہلے یہ تھیم تھی:’’فورتھ کمنگ ہیومن‘‘یعنی نیا آنے والا انسان۔ اب معلوم نہیں وہ کیا ہوگا۔ ان کے نزدیک آج کا جو انسان ہے یہ بچ نہیں سکتا۔یہ sustainable نہیں ہے۔ اب یا ٹرانس ہیومنسٹ ہے یا اینٹی ہیومنسٹ ہے ۔یا تو کہتے ہیں کہ ماڈل یہ ہے کہ Cyborgs وغیرہ جیسے مشین بن جاؤجبکہ ایک ماڈل یہ ہے کہ جانور بن جاؤ۔ یعنی تم نے اپنے آپ کو اس کائنات کا جو دولہا بنا لیا تھا اس نے مسائل پیدا کیے۔ تم اپنے آپ کو مچھر‘ مکھی اور گھاس کے تنکے کے برابر لے آؤ تو اس سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال ابھی تک میں نے یہ بتایا ہے کہ ان کا تصورِ علم کیا ہے اور ہمارا کیا ہے۔
تعلیم کیا ہے؟
اب تعلیم کیا ہوتی ہے؟ تعلیم وہ عمل ہے کہ اپنے وِرثہ اور ترکہ کو‘ جو کچھ اپنے بڑوں سے ہمیں ملا ہےاسے اپنی اگلی نسلوں تک پہنچانا۔اس عمل کو عام طور پہ تعلیم کہا جاتا ہے۔ یہ استناد کے ساتھ چلتا ہے۔ یعنی اپنے بڑوں سے سیکھا ‘ پھر آگے سکھایا‘ پھر آگے سکھایا‘ اس میں کچھ اضافے بھی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تعلیم کا تصور یہ ہے کہ یہ ایک اخلاقی اور بہت بڑا عمل ہے۔ انسان کی تشکیل میں اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے ۔ جیسے حسن بصریؒ نے کہا کہ: لَوْلَا الْعُلَمَاءُ لَصَارَ النَّاسُ مِثْلَ الْبَهَائِمِ ’’ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کی طرح ہوتے‘‘۔ وہی کہتے ہیں: الدُّنْیَا کُلُّهَا ظُلْماً إلّا مَجَالِسَ الْعُلَمَاء ’’ دنیا تو ساری کی ساری اندھیر ہےسوائے علماء کی مجالس کے‘‘۔ وہاں علم ہے ‘جبکہ اقبال نے کہا تھا :؎
گمان آبادِ ہستی میں یقیں مردِ مسلماں کا
بیاباں کی شبِ تاریک میں قِندیلِ رہبانی
(طلوعِ اسلام)یہ قندیل علماء نے ہی تو جلائی ہوئی ہے۔ علماء کون ہیں؟ ’’ اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاءِ ‘‘ جو پیغمبر کے وارث ہیں‘ جو علم کے وارث ہیں۔ علم کا جو ترکہ ان کے پاس ہے وہ آگے لے کر چل رہے ہیں۔
ہمارے ہاں تعلیم ایک اخلاقی عمل ہے کیونکہ ہمارے ہاں ہر عمل ایک اخلاقی عمل ہوتا ہے ۔ یہ صرف ہمارے ہاں نہیں بلکہ پندرہویں ‘ سولہویں صدی عیسوی تک پوری دنیا کاethos یہی تھا کہ ہر چیز اخلاقی ہے ۔افلاطون (Plato ) کی ’’ریپبلک‘‘ ان کتابوں میں سے ہے جو طبع زاد ہے‘ جس میں اس نے بتایا ہے کہ ایک ریپبلک کیسی ہونی چاہیے۔اس کتاب کا اسّی فیصد حصہ اخلاق پر مبنی ہے اور باقی تھوڑا سا حصہ سیاسیات پر مبنی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر کام اخلاقی ہوتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہـ:
Everything is moral, and education is basically a moral, ethical activity
اب ماڈرن تصوّر یہ ہے کہ: Everything is political ۔پولیٹیکل جدید معنی میں۔ پہلے تو سیاست اخلاق کا ایک جزو تھا۔ اگر تہذیب الاخلاق پر ابنِ حزم کی کتاب پڑھیں‘ ابن مسکویہ کی کتاب پڑھیں یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ تک سب سے پہلے نفس‘پھر تدبیرِ منزل‘ پھر سماج اور اس کے بعد سیاست ِ مدن۔ یعنی تہذیب الاخلاق کا ایک ہی محل ہے جس سے ہوتے ہوتے آپ ادھر تک پہنچ گئے۔
ہر چیز پہلے اخلاقی تھی‘ اب سیاسی ہے اور سیاسی بھی جدید معنوں میں۔ سقراط‘ سینٹ آگسٹائن‘امام الغزالی کے معنوں میں سیاسی نہیں بلکہ مکیا ویلی کے معنوں میں۔مکیاویلی نے کہا کہ The politics is basically amoral مطلب یہ ہوا کہ اس پر اخلاقیات کی کیٹگری عائد نہیں ہوتی ۔لیڈرز کہتے ہیں کہ یہ کرناہے‘ یہ کرنا ہے‘یہ کرنا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیوں نہیں کیا‘ آپ نے جھوٹ بولا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں‘ بھئی اس چیز پر جھوٹ سچ کا اطلاق نہیں ہوتا‘ وہ ایک سیاسی بیان تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ amoralہے یعنی وہاں پر اخلاقیات کا اطلاق نہیں ہوتا۔
روایتی تعلیم ایک اخلاقی عمل تھا ‘جدید تعلیم ایک سیاسی فیصلہ ہے۔اگر ایک بائنری بنائے تو روایتی تعلیم اور علم اقداری تھاجبکہ جدید علم و تعلیم اقتداری ہے۔ یعنی وہاں اخلاقی تھا اور اب طاقت کی بنیاد پر ہے۔ ہمارے علم اور تعلیم کا مقصود بندگی تھا ‘بندگی کے لیے آسانی فراہم(fecilitate) کرنا تھا ۔اگر کسی کو جوتا گانٹھنے یا کپڑے بُننے کا علم سکھایا جا رہا ہے تووہ بھی بندگی کے پیراڈائم میں ہے۔ ہم صرف قرآن و حدیث کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہر چیز۔ ہمارے استاذ ایک جملہ کہا کرتے ہیں‘ شاعر جسے ابنِ عربی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ’’ہمارے علوم متعدد ہیں اور ہمارا معلوم واحد ہے۔‘‘یعنی ہم تفسیر پڑھیں‘ حدیث پڑھیں‘ فقہ پڑھیں اور چارپائی بُننے کا علم سیکھیں تو اس میں بھی ہمارا مقصود اللہ ہے۔ بندہ بننا ہے۔ یہ علم ہے‘جبکہ بندگی کا علم سیکھنا تعلیم ہے‘ چاہے وہ معاش کے لیے ہو یا کسی اور چیزکے لیے ۔
اب یہ ہے کہ آپ کو معاذ اللہ‘ خدا سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ جدید علم خدا سے آزاد کرنے کا ایک انسٹرومنٹ جبکہ جدید تعلیم خدا سے باغی کرنے کا ایک میکنزم ہے۔ اکبر نے کہا تھا :؎
اِک علم تو ہے بُت بننے کا‘ اِک علم ہے حق پر مرنے کا
اُس علم کی سب دیتے ہیں سند‘ اِس علم میں ماہر کون کرے!جدید تعلیم بت بنانے کا عمل ہے۔ یہ اپنی ساخت میں ایسی ہی ہے۔ اب اس میں علوم دینیات وغیرہ داخل کردیں تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اپنے جوہر میں یہی ہے۔ پچھلے آٹھ دس سال میں کھمبیوں کی طرح موٹیویشنل سپیکر اٹھے اور جگہ جگہ انہوں نےنوٹنکی لگائی تو اس میںیہی چورن بیچا کہ جناب تم سب کچھ کر سکتے ہو‘ تم یہ ہو تم وہ ہو اور تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔خاص طور پر پوپ سائیکالوجی بالکل غیر شرعی ہے‘ یعنی وہ بت بنانا چاہتے ہیں‘ وہ خدا سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ میں بار بار انگریز لوگوں کے ریفرنس دیتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جیسے ان پہ ایسے ہی تھوپ رہے ہیں ۔ہر دور میں ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو فیشن میں ہوتا ہے اور ہمارے ہاں جو لوگ دین سے بھاگنا چاہتے ہیں وہ اس کی کتابیں لے کر رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں وہ کارل مارکس تھا‘ پھر برٹرینڈ رسل تھا۔ اس کے بعد اکیسویں صدی کے شروع میں نیو ایتھیزم میں Richard Dawkins تھا اور پچھلے چھ سال میں وہ ہراری((Yuval Noah Harari ہے۔ اب اس نے پوری انسانیت کی تاریخ لکھ دی ہے Sapiens: A Brief History of Humankind اس نے بتایا ہے کہ مستقبل کا انسان کون ہوگا۔اس نے بتایا انسان خدا بننے جا رہا ہے۔ یعنی وہ جو تصوّر دیا گیا تھا کہ ہم نے خدا کو معاذاللہ‘ ذبح کر دیا ہے‘ اب ہم سب کو چھوٹا موٹا خدا بننا ہے ۔سارے تو بنیں گے نہیں‘ یہ ماسٹر کلاس بنے گی۔میں آپ کو نام لے کر بتا سکتا ہوں‘ پانچ چھ لوگ ہیں Adam Smith نےاپنی کتاب میں ایک ٹرم Masters of Mankindاستعمال کی تھی۔ یہ کون لوگ ہیں؟وہ جو کہتے ہیں سب کچھ ہمارا ہو ‘ہمارے علاوہ کسی کا کچھ نہ ہو۔ وہElon Reeve Musk ہے‘ وہMark Elliot Zuckerberg ہے‘وہ George Soros ہے وغیرہ۔یعنی جو ماسٹر کلاس ہے وہ چند لوگوں پر مبنی ہے۔ اب اس علم کی بنیاد پر یہ لوگ ایک ماسٹر ریس پیدا کر لیں گے۔ یعنی اس وقت کرائسز یہ ہے کہ جیسے جین ایڈیٹنگ ہو رہی ہے‘ ہم ڈیزائنر babies کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی آپ کو ایک مینیو دیا جائے گا کہ بچے کی کیا رنگت چاہیے ‘ بال کیسے چاہئیں ‘آنکھیں کیسی چاہئیں۔ نقش کیسے ہوں‘ وہ آپ بتادیں اور پیسے بھریں۔ آئی کیو کتنا چاہیے۔ آپ خود سوچیں کہ یہ جو ماسٹر کلاس بنے گی تو ہمارے جیسے لوگ ان سے کیسے مقابلہ کریں گے؟ یعنی اس وقت جہاں تک بات جا رہی ہے ہم تو اصل میں غور نہیں کرتے‘ اور اچھی بات ہے غور نہیں کرتے کیونکہ غور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اگلے تین چار سال میں اے آئی وغیرہ جہاں تک پہنچ جائے گی‘ اس کے بعد پتا نہیں ہمارا اور آپ کا کیا بنے گا۔ یعنی وہاں پہ ایک روبوٹ کھڑا ہوگا‘ نہ اس کو اونگھ آئے‘ نہ اس کو نیند آئے‘ یعنی اس کی خدائی صفات ہیں۔ نہ وہ بھولتا ہے{وَمَا کَانَ رَبُّکَ نَسِیًّا} نہ اس کو چھینک آئے ‘نہ اس کے سر میں درد‘ نہ وہ بیگم سے لڑ کر آیا‘ گھر میں مسائل ہی نہیں ہیں۔ وہ جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ہر لیکچر کے لیسن پلانز بنائیں‘ لرننگ آؤٹ کمز بنائیں۔ وہ انسان ہے کوئی روبوٹ تو نہیں ہے۔البتہ روبوٹ کو لیسن پلانز بتائے جائیں گے۔وہ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ روبوٹ ہو۔جب روبوٹ ا ٓجائے گا پھر ہم آپ پتا نہیں کیا کریں گے۔ یہ علم اب یہاں تک جا رہا ہے۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ جونام نہاد ہیومنزم تھا اس کا جنازہ دو تین سو سال میں ہی نکل گیا ہے کہ انسان اب فارغ ہو گیا ۔ مولانا روم نے کہا تھا کہ ’’ انسانم آرزو ست!‘‘(مجھے انسان کی تلاش ہے۔) آج اس مصرعے کو پڑھیں تو کچھ عرصے بعد آپ کو لگے گا کہ انسان کدھر ہے‘ پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ اس کامعلوم نہیں کام کیا ہوگا۔ جب انڈسٹریل ریولیوشن آیا تھا تو وہاں پر بھی ایک بہت بڑا ہیومن ویسٹ پیدا ہوا تھا۔ اس کوdump کرنے کے لیے ان کے پاس کالونیز تھیں۔یہ پورا ایک الگ موضوع ہے۔ اب کہاں dumpکریں گے؟ جدیدیت ایجادِ وجود سے ایجادِ شعور کا سفر ہے۔ پہلے انہوں نے ہیومن باڈی کو مشین کے ذریعے replace کیا ‘ اب وہ اپنے تئیں ہیومن consciousness کو replace کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہراری کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ۔یہ اے آئی ہے ‘ اے سی نہیں ہے یعنی وہ آرٹیفیشل consciousness نہیں ہے۔
یہ سب باتیں خوف ناک ہیں لیکن میں الحمدللہ ایک پورے اعتماد کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں۔ کس بنیاد پہ کھڑا ہوا ہوں؟ میں اپنی وحی کی بنیاد پہ کھڑا ہوا ہوں کہ انسان کہیں نہیں جا رہا۔ انسانوں کی اکثریت بہ جائے گی لیکن انسان ان معنوں میں کہ وہ مسجودِ ملائک ہے‘ وہ زمین کا دولہا ہے‘ ختم نہیں ہو سکتا ۔ یہ انسان اللہ کا بندہ بھی ہے۔ انہی انسانوں میں اللہ کے دین کے کسٹوڈین بھی ہیں ۔انہی انسانوں میں اللہ کی کتاب کے وارث بھی ہیں۔ یہ گویا جیسے ہمارے لیے ایک بڑی سہولت ہو گئی ہے کہ اگر ہم اپنے دین سے جڑے رہ جائیں گے تو پھر بچ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو گا کہ ہم فنا ہو جائیں گے۔ہمارے جسم ختم کر دیے جائیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے ‘مر تو ویسے بھی جانا ہے۔ یعنی اس وقت جو سب سے زیادہ مزے میں ہیں وہ تو غزہ کے لوگ ہیں۔ ہمیں لگتا ہے سب سے مشکل میں ہم ہیں۔ ان میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے شاید کبھی نماز بھی نہ پڑھی ہو لیکن ان کو کوئی میزائل لگ جائے تو وہ ان شاءاللہ جنت الفردوس میں چلے جائیں گے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کی لاٹری کیسے نکلی ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی مدد نہ کریں لیکن وہ تو بہت اچھے رہ گئے۔ مطلب مرنا تو ہے ہی ‘موت کا کیا مسئلہ ہے۔ اصل میں اس وقت ہمارا سب سے بڑا کرائسز یہی ہے کہ ’’حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ‘‘ یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ۔
جدید تعلیم کے مقاصد
جدید تعلیم ایک پیداواری عمل ہے۔میں چند نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ John Taylor Gatto کی بہت مشہور کتاب ہے Weapons of Mass Instruction ۔اس کے شروع میں وہ ایک دوسرے مفکر Alexander Inglis کا ذکر کرتا ہے۔ اس نے ۱۹۱۸ء میں کتاب Principles of Secondary Education لکھی ۔ الیگزینڈر انگلس کے نام پہ ہاورڈ میں ایک لیکچر سیریز بھی ہے ‘جیسے چومس کی کتاب پہ ہے ‘رسل کے نام پہ ہے۔ انہوں نے چھ نکات بتائے ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن کے مقاصد کیا ہیں۔
پہلا یہ ہے کہ Adjustive or adaptive function ۔تعلیم کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کو خاص طرح کے لوگ پیدا کرنے ہیں جو اتھارٹی کے سامنے خاص طرح سے submissiveness اختیار کریں ۔ ۱۹۲۰ء میں شیخ الہند جب مالٹا سے آزاد ہوئےتھے‘اس کے بعد وہ علی گڑھ گئے اور وہاں جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔اس موقع پر انہوں نے جو خطبہ دیا اس کا ایک جملہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ’’ ہماری عظیم الشان قومیت کا اب یہ فیصلہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنےکالجوں سے بہت سستے داموں پر غلام پیدا کرتے رہیں۔‘‘ جدید تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ کیپٹل ازم کی اس امپائر کے لیے سستے مستری پیدا کرنا۔ جو بچہ سرکاری سکولوں سے پڑھا‘ وہ یہاں کے کیپٹل ازم کا کلپرزہ بنے گا۔ جو برائٹ بچہ ہے‘ جو۲۵ اے گریڈ لے کر چھت توڑ دیتا ہے وہ یہاں کی ملٹی نیشنلز کا کل پرزہ بنے گا۔ ترقی کرے گا تو گوگل یا مائیکروسافٹ کے ہیڈ آفس میں پہنچ جائے گا۔پھر جو دجل اور ظالمانہ نظام ہے اس کا ایک انتہائی ادنیٰ کل پرزہ بن جائے گا۔ یہ آپ کی تعلیم ہے۔ بڑے برائٹ بچے ہوتے ہیں لمز کے اور آئی بی اے وغیرہ کے ‘وہ کیا کرتے ہیں ؟ اکبر نے کہا تھا: ؎
سند مجھ کو ملی تو جل گئے واعظ لگے کہنے
خری کی ہوگئی تکمیل باقی صرف لدنا ہےیعنی آپ کو جو سند ملی ہے تو آپ کا کھوتا پن مکمل ہو گیا۔تو ’’خری‘‘ کی تکمیل ہو گئی‘ باقی صرف لدنا ہے۔ یعنی آپ کو جاب ہینڈلنگ کرنی ہے اور اس سسٹم میں ایک لدے ہوئے اونٹ کی طرح آپ کو فکس ہونا ہے۔ تو یہ صورت حال ہے جدید تعلیم کی۔
اب ہمارے ہاں یہ تبدیلی کہاں سے آئی ؟ہمارے ہاں تبدیلی آئی استعمار کے ذریعے۔ اگر ہم استعمار کے تحت نہ بھی آتے تب بھی ہو سکتا ہے اسّی‘ سو یا ڈیڑھ سو سال بعد ہمیں یہ سب کرنا پڑتا ۔ ایسا نہیں ہے کہ استعمار نہ آتا تو ہم اپنی جگہ پہ قائم رہتے۔ ایسا ممکن نہیں تھا۔ ہم بار بار کہتے ہیں ترکی میں جو تبدیلی آئی ‘زیادہ تر عالم ِاسلام میں تبدیلی آئی ہے بائی ان پوزیشن‘ گن پوائنٹ پہ آئی ہے ۔ البتہ کچھ جگہوں پہ امپورٹ سے بھی آئی ہے۔ سلطنت ِ عثمانیہ تھی‘ ترکی تھا ‘اس نے تو خود سے کیا ۔وہ تو colonize نہیں ہوا۔ تھوڑا ٹائم لگ جاتا ‘ کچھ اپنی شرائط پر آپ لین دین کر لیتے لیکن ہوا یہ کہ آپ پر قابض ہو گئے اور سب کچھ ختم کر دیا ۔ انہوں نے کہا تھا کہ: ؎
دستار و پیراہن گم اور جیب و کیسا خالی
تہذیب مغربی نے ہم کو چھتار ڈالابالکل گھٹنوں پہ لے آئے ‘سب کچھ ختم کر دیا ۔پھر نئے ادارے قائم کیے ۔یہ ایک لمبی بحث ہے ۔ڈاکٹر ناصر عباس صاحب نے اس پہ کافی لکھا ہے۔نوآبادیاتی نظام کے جو سب سے بڑے ہتھیار ہیں لوگوں کو مائل کرنے کے لیے وہ دو ہیں: زبان اور تعلیم ۔انگریز نے یہاں جو کلاس پیدا کی اس کے لیے زبان کے ذریعے اور تعلیم کے ذریعے عمل کیا۔
میں نے ابھی تک اس موضوع کی اہمیت پر گفتگو کی ہے ۔ اہلِ مغرب کا تصوّرِ علم کیا ہے اور ہمارا کیا ہے؟ ان کا تصوّرِ تعلیم کیا ہے اور ہمارا کیا ہے؟ دوسرا ہے Integration functionکہ ایک سسٹم میں ضم ہونا ہے۔ آپ کھپ جائیں ۔ہر جگہ ایک رٹا ہے کہ مدارس کے بچوں کا کیا کرنا ہے۔ جو اتنے بے تحاشا لوگ نکل رہے ہیں ان کو مین سٹریم میں لانا ہے۔ یہ تو بالکل الگ سے ایک مخلوق بن گئے ہیں۔ ان کو انگریزی پڑھائیں‘ کمپیوٹر سکھائیں تاکہ یہ سماج میں integrate ہو سکیں۔ تیسرا differentiating function ہے کہ کچھ لوگ آگے ہوں گے‘ کچھ پیچھے ۔ ایک تھنکر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ جو ڈگریاں حاصل کرنے کا دورانیہ اتنا زیادہ کیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ اگر جلدی جلدی سے لوگ مارکیٹ میں آ جائیں گےتو کہاں سے کھپیں گے!یعنی یہ انہوں نے ایک safety valve لگایا۔ پانچواںselective function ہے کہ وہ جو Darwinian Theory of Natural Selection ہے کہ اس تعلیمی نظام کے ذریعے سے طبقات بھی بن جاتے ہیں ـ۔چھٹا propaedeutic functionہے‘ یعنی اس سسٹم کے پروردوں میں سے پھر آپ پڑھانے والے بھی نکال لیتے ہیں۔ یہ تبدیلی استعمار کے ذریعے آئی اور اس میں میری ناقص رائے میں جتنا سبب افکار بنے ہیں اتنا ہی سبب مشین بنی ہے۔ مشین نے جو تبدیلی پیدا کی ہے وہ بہت سے نظریات سے زیادہ ہے۔C.S.Lewisنے کہا تھا کہ جدیدیت میں سب سے اہم چیز مشین ہے۔ اکبر کہتے ہیں کہ: ؎
ایک دن وہ تھا کہ دب گئے تھے لوگ دین سے
ایک دن یہ ہے کہ دین دبا ہے مشین سےہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ میں چند نکات میں عرض کردیتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ شخصی تعلیم ہوتی تھی۔ فرد اہم ہوتا تھا۔ استاد مرکز میں ہوتا تھا۔ استناد کی اہمیت تھی‘ کیونکہ ہمارا علم سند پہ کھڑا ہوا ہے۔ اب ادارہ سازی (institutionalization)ہے۔اب ادارے کو اہمیت حاصل ہے ۔آج سے ۲۰۰ سال پہلے ایک عالم دین سے یہ سوال نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہےبلکہ یہ سوال ہوتا کہ آپ نے کس سے پڑھا ہے؟ عبدالباری فرنگی محلی ہوں ‘ قاسم نانوتوی ہوں ‘ احمد رضا خان صاحب بریلوی ہوں یا فضل حق خیر آبادی ہوں‘ ان کے سوانح عمری پڑھ لیں تو مختلف لوگوں سے پڑھ رہے ہیں۔جس کو آج ہم مدرسہ کہتے ہیں‘ وہ بنیادی طور پر شخصی نظام تھا۔ آج آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کہاں سے فارغ ہیں ! وہ بتائیں گے کہ میں بنوری ٹاؤن سے فارغ ہوں ‘میں دارالعلوم سے فارغ ہوں وغیرہ۔ یعنی وہ بندوں کا نام نہیں بتاتے۔پہلے استادتھا ‘ وہ تو غائب ہو گیا۔ اب نظام سازی (systamization) اور تدریسی خاکے (lesson plans) وغیرہ ہیں‘ اسی لیے تو ہیں کہ آدمی کسی بھی وقت replace کرتے ہیں کیونکہ وہ تو ایک آپریٹس ہے۔ یعنی Modern Education is a technique۔جس طرح سٹیٹ ایک ٹیکنیک ہے‘اسی طرح یونیورسٹی بھی ایک ٹیکنیک ہے۔ اُسی طریقے سے انٹرنیٹ بھی ایک ٹیکنیک ہے۔ تو ہماری پوری زندگی ٹیکنیک سے چل رہی ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ علم اور معاش کو آپس میں جوڑ دیا گیا‘ یہ پہلے نہیں ہوا تھا ۔پہلے لوگ معاش کے لیے فنون سیکھتے تھے‘وہ علم نہیں تھا۔ علم تو کسی اور چیز کے لیے تھا‘جس پر میں نے آپ کو ارسطو کی مثال دی تھی۔ بقول اقبال: ؎
وہ علم نہیں موت ہے احرار کے حق میں
جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کف جوپھر عقائد پر جو سب سے بڑا اثر پڑا وہ یہ کہ غیب جدید علم شہود کے دائرے سے باہر ہے۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ ؎
محسوس پر بِنا ہے علومِ جدید کی
اس دَور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاشاور بقول اکبر الٰہ آبادی ؎
منزلوں دُور اُن کی دانش سے خدا کی ذات ہے
خردبیں اور دُوربیں تک ان کی بس اوقات ہےاور ؎
کیونکر خدا کے عرش کے قائل ہوں یہ عزیز!
جغرافیہ میں عرش کا نقشہ نہیں ملاکسی چیز کے ہونے کا مطلب ہے اس کا مشہود ہونا‘ تو غیب تو علم سے نکل چکاہے۔ اسی لیے ہمارے بچے جو انگلش اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے سامنے جب معراج وغیرہ کا ذکر کیا جائے تو وہ مسکراتے ہیں۔ ابھی وہ اتنے شوخ نہیں ہوئے کہ بدتمیزی کردیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ معجزات وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے ۔بقول اکبر ؎
نظر ان کی رہی کالج کے بس علمی فوائد پر
گرا کے چپکے چپکے بجلیاں دینی عقائد پر
طریقِ مغربی کی کیا یہی روشن ضمیری ہے
خدا کو بھول جانا اور مہر ماسوا ہونا!یعنی اب جیسے یہی تعلیم ہے اور یہی علم ہے۔ ہمارے ہاں جو بہت برائٹ بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ‘اس بارے میں اکبر کہتے ہیں: ؎
قابلیت تو بہت بڑھ گئی ماشاءاللہ
مگر افسوس یہی ہے کہ مسلماں نہ رہے!
اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے۔سوال و جوابسوال:جدید تعلیم نے ہمارے عقائد کو کیسے متاثر کیا؟
جواب:جدید تعلیم کا ہمارے عقائد پر جو اثر پڑا ہے اُس کا بنیادی سبب جدید علم کی ساخت ہے۔ جدید علم حواس مرکز ہے‘ شہود مرکز ہے۔ اُس میں غیب کے لیے گنجائش نہیں ہے‘ اسی لیے ہمارے ہاں عام طور پہ جب بھی اسلامک ایجوکیشن کی یااسلامک اسکولنگ کی بات ہوتی ہے تو زیادہ تر گفتگو نصاب پر ہوتی ہے کہ اس میں کچھ بہتری لائی جائے اور دینیات کا پہلو بڑھا دیا جائے۔مثلاً سائنسز چاہے وہ فزیکل ہوں یاسوشل‘ عمومی خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو واقعاتی اور matter of fact ہیں ‘ اُس میں کچھ چیزیں شامل کر دی جائیں توکام بن سکتا ہے۔البتہ جس کو آپ matter of fact کہہ رہے ہیں‘ اُس میں بہت سے مسئلے ہیں۔
پھر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مذہب اور سائنس میں کوئی conflict نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبد الباری ندوی صاحب نے بہت پہلے ایک کتاب لکھی تھی ’’مذہب اور سائنس‘‘۔اُنھوں نے ایک تشبیہ بیان کی تھی کہ مذہب اور سائنس میں تصادم کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے بحری جہاز اور ٹرین میں ٹکر ہو جائے یا ہوائی جہاز اور سائیکل میں ٹکر ہو جائے۔گویا دونوں کے دائرے بالکل الگ الگ ہیں۔ میری ناقص رائے میں content سے زیادہ اہم جدید تعلیمی اسٹرکچر ہے‘ جوآپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ ہم ایک جملہ طالب علموں سے کہتے ہیں اور وہ جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو جدید دنیا کی بہت سی چیزیں کھل جائیں گی۔ وہ جملہ مارشل مکلوہن کا ہے اور بڑا سادہ سا لیکن گہرا جملہ ہے۔ اُس نے کہا تھا: The medium is the message۔ جس ذریعے سے آپ کوئی چیز ڈیلیور کر رہے ہیں یا حاصل کر رہے ہیں‘وہ ذریعہ بہت اہم ہے۔مثلاً جدید دور میں دورۂ حدیث شریف منعقد ہوتا ہے تو ہمارے علماء جدید کیوں نہیں ہو رہے؟ وہاں یہ جدید ٹیکنالوجی کیوں نہیں استعمال ہو رہی؟پروجیکٹر کیوں نہیں استعمال کرتے؟ پاور پوائنٹ پر حدیثوں کا تجزیہ آنا چاہیے ‘علیٰ ہذا القیاس۔ دراصل یہ سمجھنا چاہیے کہ حدیث کا علم اِس اسٹرکچر کے ساتھconducive نہیں ہے۔ اُس علم میں تو میز کرسی بھی مسئلہ بنے گی۔ہر علم کو حاصل کرنے کا ایک پروٹوکول ہے‘ ایک طریقہ ہے۔ہر میڈیم ہر علم کے لیے ساز گار نہیں ہے۔
اسی طرح اسلامک اسکولز کا تصور ہے۔ا سکولز ہیں‘ کالجز ہیں‘ پھر یونی ورسٹیز ہیں۔آپ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کریں گےکہ کچھ دعائیں ڈال دیں‘ تھوڑے بہت اذکار اور کلمے یاد کرا دیے‘ آداب رٹوا دیے‘ ویلنٹائنز ڈےنہیں منایا جائے گا‘ہیلو وین نہیں منائی جائی گی‘ خواتین اساتذہ ڈھنگ کا لباس پہنیں گی۔ اچھی بات ہے‘ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو تعلیم دینی ہے‘ اِس بات پر کیوں سوال نہیں اٹھتے کہ لڑکیوں اور لڑکوں کا نصاب ایک کیوں ہے؟
سوال:بظاہر روایتی تعلیمی نظام میں عورت کو دنیوی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع نہیں تھے لیکن اب جیسے عورتوں کو آگے بڑھنے کے مواقع دیے جاتے ہیں‘ اِس معاملے میں ہمارا کیا نقطۂ نظر ہونا چاہیے؟
جواب:آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ بچیوں کو تو رہنے دیں‘ہمارے بچوں کو بھی یہ تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں بھی ہمیں اکبر یاد آتے ہیں‘ اُنھوں نے کہا تھا:؎
دو اسے شوہر و اطفال کی خاطر تعلیم
قوم کے واسطے تعلیم نہ دو عورت کو
تعلیم دختراں سے یہ امید ہے ضرور
ناچے دلہن خوشی سے خود اپنی برات میںاور یہ بات تو ہمارے مشاہدے کی ہے۔ ہم نے کچھ ایسے اداروں میں پڑھایا ہے جو بہت ٹیڑھے میڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں‘وہاں جو بچیاں پڑھتی ہیں‘ اُن کو دیکھ کر ہی یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ بیوی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ اِن میں تسلیم کی صفت ہےہی نہیں‘انھیں تو قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ لاکھوں کروڑوں لگا کر شادیاں ہوتی ہیں لیکن کوئی ہفتے چل رہی ہے‘ کوئی مہینے چل رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ازدواجی رشتہ ایسے مزاج کے ساتھ نہیں چلتا۔
سوال: آپ نے سائنس کے حوالے سے بات کی‘ میں خود سائنس کا استادہوں۔ عموما ً فلسفے کے اساتذہ سائنس سے ناواقف ہوتے ہیں ‘اس لیے وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ سائنس مذہب سے دور کرتی ہے‘ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سائنس تو مذہب سے قریب کرتی ہے۔ یعنی جتنی سائنس قرآن میں بیان کی گئی ہے دوسری جگہ نہیں ہے‘صرف relate کرنے کی ضرورت ہے ۔ ہمارے دینی اساتذۂ کرام نا واقفیت کی وجہ سے اُس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر پاتے۔
جواب: ایک ہے پاپولر سائنس جو ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے‘ اور ایک ہے سائنس کی تھیوری۔ سائنس کی ایک تعریف جو عرصے سے چلی آ رہی ہے وہverificationہے۔تجربے کے ذریعے جس چیز کی تصدیق ہو جائے وہ سائنس سے ثابت ہے۔ کارل پوپر وغیرہ کے بعد اب تعریف یہ ہو گئی کہfalsification سائنس کی بنیاد ہے۔ جس چیز کی تلبیس ہو سکے وہ سائنس ہونا qualifyکرتی ہے۔چنانچہ خدا‘ آخرت‘ فرشتے‘روح‘جنت ‘جہنم یہ non-falsifiable ہیں۔اِس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائنٹفک نہیں ہیں تو ان کا ہونا‘ نہ ہونا برابر ہے۔ آج ایک تھیوری آئی ہے‘ وہ کسی مذہبی چیز کا اثبات کر رہی ہے‘ ہو سکتا ہے کل وہ بدل جائے۔ نیوٹن کی فزکس اور تھی‘ آئن سٹائن کی اور ہے‘ آئزن برگ کی اور ہے۔ اب ہم اگر اِس میں پڑ جائیں کہ سائنس کی جو نئی تحقیقات سامنے آئیں‘ ہم کہیں کہ قرآنِ مجید میں اِس کا بیان ہے اور تیس چالیس سال بعد وہ تھیوری جھوٹی ثابت ہو جائے‘ پھر ہم خالی ہاتھ بیٹھے رہیں۔یہ بہت سلپری سلوپ ہے۔’’مذہب اور سائنس‘‘یا ’’قرآن اور سائنس‘‘ بہت حساس موضوع ہے۔ ہم بہت سی چیزوں کو بہت جلدی قبول کر کے اور اُس کی مرعوبیت میں آ کر اللہ کی کتاب سے اُس کوrelate کرنے کی کوشش کرتے ہیں‘ اِس سے ہمارا مذاق اڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں سائنس دان محنتیں کر کر کے‘ سر مار مار کے کوئی چیز دریافت کرتے ہیں‘ یہ مولوی آرام سے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں پہلے سے ہی تھا۔اگر پہلے سے ہی تھا تو آپ کس خوابِ غفلت میں تھے؟آپ کیوں نہیں بر آمد کر سکے؟ قرآن تو آپ کے پاس تھا۔لہٰذا اِس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔