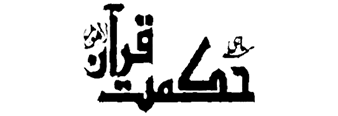(فکر و نظر) ہمارے نظامِ تعلیم پر استعماری طاقتوں کے اثرات - ڈاکٹر محمد رشید ارشد
10 /ہمارے نظامِ تعلیم پر
استعماری طاقتوں کے اثراتپروفیسر ڈاکٹر رشید ارشد
ہمارے ملک میں سیاسی اور معاشی اعتبار سے جو استبداد ہے‘ اور اسی طرح بین الاقوامی سطح پر غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے‘ اس تناظر میں اُمّت ِ مسلمہ کے عوام کی بے بسی اور حکمرانوں کی بے حسی ظاہر و باہر ہے۔ ایسے حالات میں یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے علمی موضوع کا کیا محل ہے! بہرحال‘ اس وقت ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہم جس آشوب سے گزر رہے ہیں ان حالات میں اس طرح کے موضوع کی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ آج کے موضوع کا ان دونوں چیزوں سے براہ راست تعلق ہے۔ مثلاً آج جب بین الاقوامی تنازعات ہوتے ہیں تو ہم کچھ اداروں اور کچھ تصوّرات کی دہائی دیتے ہیں‘ جیسے اقوامِ متحدہ ایک ادارہ ہے اور اسی طرح ہیومن رائٹس ایک تصوّر ہے۔ یہ دو چیزیں بھی استعمار اور نو آبادیاتی نظام کا امتداد ہیں۔ علامہ اقبال کی زندگی میں پہلی جنگ ِ عظیم کے بعد ’’لیگ آف نیشنز‘‘ بنی‘ اور دوسری جنگ ِ عظیم کے بعد اسے ’’یونایٹڈ نیشنز آرگنائزیشن‘‘ (UNO)میں بدل دیا گیا۔ اقبال نے اس موقع پر جو کہا تھا وہ آج بھی بہت متعلق ہے: ؎
برفتد تا روشِ رزم درین بزم کہن
دردمندانِ جہان طرحِ نو انداختہ اند
من ازین بیش ندانم کہ کفن دزدی چند
بہر تقسیم قبور انجمنی ساختہ اند!’’یہ جو بزمِ کہن یعنی یہ دنیا ہے اس میں سے جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے دُنیا کے درد مندوں نے ایک نئی طرح ڈالی ہے۔ میں تو اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ چند کفن فروشوں نے قبروں کی فروخت کے لیے ایک انجمن بنائی ہے۔‘‘
بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے
ڈر ہے خبرِ بد نہ مرے مُنہ سے نکل جائے
تقدیر تو مُبرم نظر آتی ہے و لیکن
پیرانِ کلیسا کی دعا یہ ہے کہ ٹل جائے!
ممکن ہے کہ یہ داشتۂ پِیرکِ افرنگ
اِبلیس کے تعویذ سے کچھ روز سنبھل جائے!علامہ اقبال نے لیگ آف نیشنز کو ’’داشتۂ پِیرکِ افرنگ ‘‘کہا ہے اور یہی یو این او کے لیے بھی صحیح بات ہے۔ کراچی کے ایک شاعر جون ایلیا نے کیا کہا ہے:
حل نہ کرنے کے لیے ہر مسئلہ ہے زیر ِغور
مسئلوں کو اور اُلجھانے کا فن ہے سامراج
بستیاں ہیں مضطرب‘ آبادیاں ہیں مضمحل
بربطِ خود پروری پر زخمہ زن ہے سامراجسامراج کے اور بھی کئی نام ہیں جیسےاستعمار‘ نو آبادیاتی نظام وغیرہ۔ یہ آج بھی مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ اُمّت ِمسلمہ کو دو طرح کی نابودی کا سامنا ہے۔ کچھ علاقوں میں طبعی نابودی کا اندیشہ ہے‘ جسے ہم physically elimination کہتے ہیں‘ یعنی جسمانی طور پر ختم کر دیا جائے۔ اس سے بڑھ کر تہذیبی نابودی (civilizational annihilation) ہے‘یعنی ایک کلچر کا خاتمہ ۔ اب دوڈھائی سو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس صورتِ حال کا سامنا ہے۔ ہماری اکثر مسلم ریاستوں کو پوسٹ کلونیل سٹیٹس کہا جاتا ہے‘ اس طرح کی ریاستیں ہمیشہ سے استعمار کی پٹھو ریاستیں رہی ہیں۔ آج تک ہم نے اپنے اسٹیٹس کو بدلا نہیں ہے‘ یعنی ہم اسی پر راضی اور مطمئن ہیں۔ لہٰذا جو آج ہم بھگت رہے ہیں اس کے پیچھے وہی استعمار ہے۔ کیا اچھا شعر ہے میر کا کہ:
امیرزادوں سے دلی کے مل نہ تا مقدور
کہ ہم فقیر ہوئے ہیں انہیں کی دولت سےاکبر الٰہ آبادی نے کہا تھا کہ: ؎
گو سانس چل رہی ہے خوں اب نہیں جہَِندَہ
مشرق بہ دست مغرب مردہ بہ دست زندہاکبر نے یہ اگرچہ نو آبادیاتی دور میں کہا تھا‘ لیکن آج بھی ’’مشرق بہ دست ِمغرب مردہ بہ دست ِ زندہ‘‘ والی کیفیت ہے۔ یہاں استعمار آیا اور اس کے ساتھ جدیدیت بھی آئی۔ Mignolo ایک لاطینی امریکن مفکر ہے‘ اس کی ایک کتاب ہے: The Darker Side of Western Modernity (مغربی جدیدیت کا تاریک پہلو) ۔اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ: Coloniality is the flip side of modernity یعنی نو آبادیات جدیدیت کا دوسرا پہلو ہے۔ نو آبادیات اور جدیدیت کو آپ الگ نہیں کر سکتے‘ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔
مغربی افکار کی قبولیت و عدمِ قبولیت کا تصوّر
اس بحث میں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہم استعمار کا شکار نہ ہوتے تو کیا ایسے ہی روایتی طریقے پر رہتے؟ ظاہر بات ہے ایسا نہیں ہوتا۔ ہم روایتی طریقے پر نہیں رہتے‘ کیونکہ تہذیبوں میں آپس کا لین دین چلتا رہتا ہے۔ پیغمبر اسلامﷺ کے دور میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کا مشورہ دیا۔ اسی طرح منجنیق اختیار کی گئی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ خلافت ِراشدہ میں نظامِ حکومت کے سلسلے میں ایرانی اور رومی طرزِ حکومت سے استفادہ کیا گیا۔ اسی طرح لباس‘ سواری جیسی چیزوں میں تبدیلی آتی رہی۔ یہ معاملہ چند چیزوں تک محدود نہیں تھا بلکہ تصورات بھی لیے گئے۔ ان تصورات کے زیرِ اثر جبریہ‘ قدریہ‘ حشویہ اور معتزلہ جیسے مختلف فِرق وجود میں آئے۔ پھر جوہر‘ عرض‘ ہیولا‘ استحالہ‘ وجوب‘ ممکن الوجود‘ واجب الوجود اور ممتنع الوجود جیسی اصطلاحات بھی آگئیں۔ ان میں بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو یونانی فکر کے اثر سے آئیں۔ البتہ یہ سب کچھ گن پوائنٹ پر نہیں تھا‘ جبر کے ساتھ نہیں تھا‘ بلکہ ہم نے اپنی شرائط پر یہ ساری چیزیں لیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم غالب تھے‘ تو ہمارے پاس یہ اختیار تھا‘ مگر مغربی تہذیب کے مقابلے میں آج ہمارے پاس ردّ و قبول کا اختیار ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اسلامک ماڈرنسٹ یہ مقولہ بہت استعمال کرتے ہیں کہ: خُذْ ما صَفا ودَعْ ما کَدِر’’ جو اچھا ہے وہ لے لو‘ جو آلودہ ہے اسے چھوڑ دو‘‘۔ بظاہر یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی منہج ہو ہی نہیں سکتا‘ لیکن یہ تب ہے جب ہمارے پاس اختیار ہو۔ماضی میں ہمارے پاس انتخاب کا اختیار تھا اور ہم نے اس کا استعمال بھی کیا‘ مگر جب سے ہم استعمار کے قبضے میں آئے تو ہم مغلوب تھےاور وہ طاقت کے ساتھ آئے۔ انہوں نے ہمارے اداروں کو تحلیل کیا اور ہم پر ایک جبر مسلط کیا۔ گویا ہم حالت ِاختیار سے حالت ِاضطرار میں چلے گئے۔ یہ ایک جوہر ی تبدیلی ہے۔ چنانچہ عقل ونقل کی کشمکش یا روایت و جدیدیت کا ٹکراؤ جو اٹھارہویں صدی عیسوی سے شروع ہوا اور بیسویں صدی عیسوی میں مکمل ہو گیا‘ اس میں ہمارے پاس اختیار نہیں تھا۔
تعلیم کے دُوررَس اثرات
تعلیم میں اصالت اور عصبیت ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی روایت کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے اور اسے ٹھیک ٹھیک اپنی اگلی نسلوں تک پہنچانا ہوتاہے:؎
باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اَزبر ہو
پھر پسر قابلِ میراثِ پدر کیونکر ہو!تعلیم کے لیے جہاں rootedness درکار ہوتی ہے وہاں ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے‘ یعنی اگر ایک طرف اصالت ہے تو دوسری طرف معاصرت ہوتی ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم کا ایک پہلو ہے rootedness اور ایک پہلو ہے relatedness۔ ہم جس دنیا‘ جس زمان و مکان اور جس سیاق و سباق میں رہ رہے ہیں اس سے بھی وہ علم اور تعلیم متعلق رہنی چاہیے۔ اسلامک ماڈرن ازم کا ایک بڑا اور بنیادی مسئلہ ہے ’’الثوابت والمتغیرات‘‘‘ یعنی ثوابت وہ پختہ چیزیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور ایک متغیرات ہیں۔ علامہ اقبال کی کتاب Reconstruction میں بھی یہ تھیم بار بار آتا ہے۔ چنانچہ دورِ استعمار میں ان دونوں چیزوں کو نقصان پہنچا۔ ایک ہماری اصالت کو ڈز پہنچی کہ وہ لوگ آگئے ۔انہوں نے آ کر ایک تو زبان بدل دی‘ پھر نظامِ تعلیم بدل دیا۔ نظامِ تعلیم کی تبدیلی کے ساتھ پڑھے لکھے ہونے کا مطلب بھی بدل گیا۔ کہا گیا کہ: ’’پڑھے فارسی اور بیچے تیل۔‘‘ کہ اب وہ جو پرانا علم تھا‘ جس کے لیے عالم‘ فاضل وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے تھے ‘غیر متعلق ہو گیا‘کیونکہ اب یہ مارکیٹ میں چلنے والا علم نہیں ہے۔ مارکیٹ میں تو اب انگریزی دان چلیں گے ۔اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ جو ہماری اصل تھی اس سے ہمارا تعلق ختم ہوگیا۔ پھرجو جدید علوم آ رہے تھے‘ انگریزوں نے ایسا نہیں کیا کہ وہ سارے علوم جو اپنے ہاں رائج کیے وہ سارے یہاں رائج کر دیے ‘بلکہ انہوں نے اس میں انتخاب کیا۔ جو سائنس اور ٹیکنالوجی تھی وہ یہاں رائج نہیں کی۔ لٹریچر‘ ادب‘ ثقافت اور تاریخ ‘اس طرح کی چیزوں کو فروغ دیا۔ اسی لیے اکبر نے کہا تھا: ؎
علم پورا اگر سکھائیں ہمیں
تب کریں شکر مہربانی کا!یعنی ہمیں پورا علم نہیں سکھا رہے۔ اس میں بھی ایک خاص انتخاب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پڑھ لکھ کے سیانے ہوجائیں اور ہمارے منہ کو آئیں۔
باقی یہ بات کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے جو ہمارا علم تھا کیا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم طالب علموں کی ناقص رائے یہ ہے کہ دونوں پہلوؤں سے اس میں کمزوری واقع ہو چکی تھی۔ ایک جو اصالت والی بات ہے اس میں بھی کمزوری ہو گئی تھی۔ علومِ عالیہ یعنی متن کے علم میں گہرائی پیدا کرنا‘ اس کے اندر تفقہ اور بصیرت پیدا کرنا کم ہوتا جا رہا تھا جبکہ علومِ آلیہ پر توجّہ زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ یعنی قبل ِاستعمار بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ٹھیک جگہ پر کھڑے تھے۔ یہاں وحدانی نظامِ تعلیم تھا۔ اس میں اپنے زمانے کا علم بھی تھا‘ اگرچہ کافی حد تک خارج میں یعنی یورپ میں جو ہو رہا تھا اس سے بر ِصغیر کے لوگ ناواقف تھے۔ اسی طرح ماقبل استعمار جو علوم و فنون‘ مثلاً ہندسہ‘ طب‘ ہیئت‘ جغرافیہ وغیرہ تھے‘ انہیں جدید تحقیق سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت تھی۔لہٰذا ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ معاملات بالکل ٹھیک چل رہے تھے اور ساری خرابی انگریز نے کی ہے۔ بلکہ دونوں پہلوؤں سے یعنی قرآن وسُنّت میں تفقہ میں کمزوری تھی اور اسی طرح زمانے کے جو علوم تھے ان میں بھی ہم کافی پیچھے تھے۔ بہرحال ہمارے ہاں جب انگریز آیا تو ہم نے جدید علوم کا استقبال ویسے نہیں کیا جیسے ماضی میں یونانی علوم کا کیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ فاتح بن کر آیا‘ جبر سے معاملہ ہوا اور ہمیں ایک وجودی خطرہ لاحق ہو گیا۔ جب ایسی صورتِ حال کا سامنا تھا تو اس کے مقابل میں جو لائحہ عمل اختیار کیا گیا تھا اس کے دو تناظر مولانا قاسم نانوتوی اور سرسید احمد خان تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دونوں مولانا مملوک نانوتوی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ دونوں کا تجزیہ یہی تھا کہ یہ جو اِدبار اور زوال ہم پر آیا ہے اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کا نسخہ تعلیم اور تربیت‘ علم اور اخلاق ہے۔ سر سید احمد خان اور مولانا قاسم نانوتوی دونوں ایک تجزیے پر پہنچے‘ مگر ان میں فرق یہ تھا کہ سرسید نے کہا علم و اخلاق وہ جو یورپ کا ہے‘ جبکہ مولانا قاسم اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ علم بھی سلف کا اور اخلاق بھی سلف کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں دونوں نے مرض کی درست تشخیص کی مگر علاج میں اختلاف رونما ہوا۔ انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یو پی کے لڑکوں میں سر سید احمد خان کے بیٹے سید محمود منتخب ہوئے تھے۔ انہیں داخل کرانے کے لیے سر سید لندن گئے‘ اس سفر کی روداد ’’مسافرانِ لندن‘‘ کے نام سے لکھی۔ انہوں نے وہاں کا نظامِ تعلیم اور تمدن دیکھا اور اس سے بہت متاثر ہوئے۔ وطن واپسی پر انہوں نے وہاں کے نظامِ تعلیم کو اپنایا بلکہ عمارتیں بھی آکسفورڈ اور کیمبرج کے ماڈل پر بنائیں۔ پھر اخلاق کی درستگی کے لیے ’’تہذیب الاخلاق‘‘ کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ کھانے پینے کا کیا طریقہ ہے؟ چھری کانٹے سے کیسے کھانا ہے؟ کیسے اٹھنا ہے؟ کیسے بیٹھنا ہے؟ کیسے چلنا ہے؟ یہ سکھانا شروع کیا۔ لہٰذا انہوں نے انگریزی طرزِ زندگی کو ماڈل بنایا جبکہ مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے رفقاء نے دوسرا ماڈل بنایا۔ اکبر کا ایک معجز نما شعر ہے: ؎
توپ کھسکی پروفیسر پہنچے
جب بسولا ہٹا تو رندا ہےایک اور جگہ کہا: ؎
مشرقی تو سرِ دشمن کو کچل دیتے ہیں
مغربی اُس کی طبیعت کو بدل دیتے ہیںمغرب یہ دونوں کام کرتا ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ توپ والا ہے کہ اسے سردشمن کو کچل دینا ہوتاہے۔ پھر اگلا مرحلہ اس کی طبیعت کو بدلنا ہے‘ اس کے لیے پروفیسر آئےگا۔ کتنی اچھی تشبیہ دی ہے کہ وہ جو بسولا ہے وہ تو کاٹ دیتا ہے جبکہ رندا چھیلتا ہے اور درست کر دیتا ہے۔ اقبال نے بھی کہا کہ: ؎
میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ
نہایت تیز ہیں یورپ کے رندےلوئس التھوسر ( Louis Althusser ) بائیں بازو کے ایک مشہور مفکر ہیں‘ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دو طرح کے آلات و اوزار( (apparatus ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جابر ریاستی آلہ(repressive state apparatus) جس میں آرمی‘ فوج‘ طاقت اور جیلیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے نظریاتی ریاستی آلہ (ideological state apparatus) جس میں سکول‘ کالج‘ میڈیا انڈسٹری ہے۔ یعنی جو سر دشمن کو کچل دیتا ہے‘ وہ توپ ہے‘ اور دوسرا پروفیسر ہے جو طبیعت کو بدل دیتا ہے۔
ثقافتی اجارہ داری
اسی طرح ایک اور تصور ثقافتی اجارہ داری کا ہے ‘جو ایک اطالوی مفکر Gramsci کا ہے ۔ اس میں طاقت کا استعمال نہیں ہوتا‘ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ خوشی خوشی یہ سب ہو رہا ہے۔ اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ذہنی تبدیلی پیدا کر دی جاتی ہے جس کے تحت اجارہ زدہ گروہ خود برضا و رغبت اپنے خیالات سے دست بردار ہو جاتا ہے اور اجارہ دار کے نظریات کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ hegemony کہلاتی ہے۔ عام طور پر یہ تب ہوتا ہے جب ان دونوں گروہوں میں طاقت‘ ثقافت اور معیشت کا عدمِ مساوات ہو۔ جس پر اجارہ قائم کیا جا رہا ہے وہ اپنے خیالات‘ ثقافت‘ شناخت سے دست بردار ہو جاتا ہے۔ کالونی اس کو کہتے ہیں کہ حاکم اور محکوم کے درمیان نظریات‘ خیالات وغیرہ کا تعلق یک طرفہ ہوتا ہے‘ وہ ایکسچینج نہیں ہوتا۔ چنانچہ استعمار کے تسلط کے بعد ہندوستان میں لوگوں نے اس کو قبول کر لیا۔ ولیم ولسن ہنٹر ( William Wilson Hunter) کی ’’ہندوستانی مسلمان‘‘ ایک مشہور کتاب ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب مسلمانوں نے برطانوی ہندوستان کو دار الحرب کے بجائے دار الامان کے طور پر قبول کر لیا تو انہوں نے اپنی محکومانہ حیثیت بھی تسلیم کرلی۔ جب تک مسلمان ہندوستان کو دارالحرب سمجھتے رہے تو مزاحمت کو اپنا مذہبی فرض سمجھتے رہے‘ مگر جب اپنی محکومانہ حیثیت کو قبول کر لیا تو مزاحمت کی جگہ متابعت نے لے لی۔ سرسید احمد خان نے کہا تھا :
’’ہم صاف صاف کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کو مشرقی علوم کی ترقی کے پھندے میں پھنسانا ہندوستانیوں کے ساتھ نیکی کرنا نہیں بلکہ دھوکے میں ڈالنا ہے۔ ہم لارڈ میکالے کو دعا دیتے ہیں ‘خدا اس کو بہشت نصیب کرے کہ اس نے اس دھوکے کی ٹٹی کو اٹھا دیا تھا۔ ہم کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ ہندوستان اور انگلستان کے درمیان جو اتحاد ہوا ہے وہ مدتِ دراز تک قائم رہے گا۔‘‘
یہ دیکھتے ہوئے تعجب ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہم سر سید مرحوم کو کہا ں سے تحریک ِپاکستان میں ڈال دیتے ہیں‘ حالانکہ وہ تو قیامت تک ملکہ عالیہ کا راج قائم رکھنا چاہتے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں:
’’پس اپنے ہم و طنوں کے دلوں پر ان باتوں کا روشن کرنا اور ان کو اس پر تعلیم دینا کہ وہ ان برکتوں کی قدر شناسی کر سکیں اور زمانۂ سلف کے دھوکا دینے والے خیالات کو باطل کرنا جو ہماری ترقی کے مانع ہوتے ہیں‘ اور ہندوستان کے مسلمانوں کو سلطنت انگریزی کے لائق و کار آمد رعایا بنانا اور ان کی طبیعتوں میں اس قسم کی خیر خواہی پیدا کرنا جو ایک غیر سلطنت کی غلامانہ اطاعت سے نہیں ‘بلکہ عمدہ گورنمنٹ کی اصلی قدر شناسی سے پیدا ہوتی ہے۔‘‘
Hegemony اسی کو کہتے ہیں ۔وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر نکارت پیدا نہ ہو بلکہ آپ واقعی سمجھیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ آگے کہتے ہیں:
’’جو شخص اپنی قومی ہمدردی سے اور دُور اندیش عقل سے غور کرے گا وہ جانے گا کہ ہندوستان کی ترقی ‘ کیا علمی کیا اخلاقی‘ صرف مغربی علوم میں اعلیٰ درجے کی ترقی حاصل کرنے پر منحصر ہے۔ اگر ہم اپنی اصلی ترقی چاہتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی مادری زبان تک کو بھول جائیں‘ تمام مشرقی علوم کو نَسیاً منسیاً کردیں۔ ہماری زبان یورپ کی اعلیٰ زبانوں میں سے انگلش یا فرینچ ہو جائے۔ یورپ ہی کے ترقی یافتہ علوم دن رات ہمارے دست مال ہوں۔ ہمارے دماغ یورپین خیالات سے بجز مذہب کے لبریز ہوں۔ ہم اپنی قدر‘ اپنی عزت کی قدر کرنا خود سیکھیں۔ ہم گورنمنٹ انگریزی کے ہمیشہ خیر خواہ رہیں اور اسی کو اپنا محسن سمجھیں۔‘‘
پنجابی میں کہتے ہیں: ’’لو کر لو گل۔‘‘ یہ بانیانِ پاکستان میں سے معلوم نہیں کہاں سے آئے۔ بہرحال یہ جو ایک مقولہ ہے کہ: Divide and rule یعنی تقسیم کرو اور حکومت کرو‘ ایسے ہی کسی نے لکھا ہے کہ: Define and rule ‘ یعنی تعریف کرو اور حکمرانی کرو۔ پہلی والی بھی ایک strategy ہے اور دوسری بھی۔ اکبر نے کہا ہے: ؎
میری نصیحتوں کو سن کر وہ شوخ بولا
نیٹو کی کیا سند ہے‘ صاحب کہیں تو مانوں!
سر سید کے نقطۂ نظر کے ضمن میں میکالے کا یہ جملہ بھی اہم ہے کہ:
" We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern. "
’’ہمیں فی الحال ایک ایسا طبقہ بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے جو ہمارے اور اُن لاکھوں لوگوں کے درمیان ترجمان ہو جن پر ہم حکومت کرتے ہیں۔‘‘
آگے وہ مزید کہتے ہیں :
" A class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect."
’’ لوگوں کا ایک طبقہ‘ جو خون اور رنگ کے لحاظ سے ہندوستانی ہو لیکن ذوق‘ رائے‘ اخلاق اور عقل کے لحاظ سے انگریز ہو۔‘‘
اقبال نے کہا تھا : ؎
ترا وجود سراپا تجلّیٔ افرنگ
کہ تُو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر
بہرحال اس مقصد کے حصول کے لیے وہ تمام گر بروئے کارلاتے ہیں جن میں سے ایک کلچر انڈسٹری بھی ہے۔ اکبر کہتے ہیں : ؎
یورپ میں گو ہے جنگ کی قوت بڑھی ہوئی
لیکن فزوں ہے اس سے تجارت بڑھی ہوئی
اگلے شعر میں وہ کہتے ہیں: ؎
ممکن نہیں لگا سکیں وہ توپ ہر جگہ
دیکھو مگر پیئرز کا ہے سوپ ہر جگہ
اگر کہیں وہ توپ نہ بھی لگا سکیں لیکن پیئرز کا سوپ تو ہر جگہ پہنچا دیں گے۔
ایک غلط فہمی
جب بھی استعمار اور نو آبادیاتی نظام کی بات کی جاتی ہے تو فوری طور پر ایک سوال اُٹھتا ہے کہ ہمارے ہاں عرب سامراج بھی تو تھا‘ یعنی ہندوستان میں جب مسلمان آئے تھے وہ بھی تو سامراجی طاقت کے طور پر آئے تھے۔ علامہ اقبال نے خطبۂ الٰہ آباد میں بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ عرب ملوکیت کے متعلق جو دھبہ ہے ‘ہمیں اسے صاف کرنا ہے۔ درحقیقت اس سوال کی بنیاد ہی درست نہیں ہے‘ کیونکہ عرب ملوکیت اور مغربی استعمار میں بڑا فرق ہے۔ پہلے تو زمانے کو دیکھنا چاہیے کہ مغربی سامراج اور عرب فتوحات مختلف دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ نام نہاد جمہوریت سے پہلے سلطنت کا دور تھا جسے ہم ملوکیت کہتے ہیں۔ اس دور میں ہندوستان میں جتنے لوگ آئے وہ سب عہدِ وسطیٰ سے تعلق رکھتے ہیں‘ جبکہ مغربی استعمار انڈسٹریل ریولیوشن کے ساتھ ملحق ہے۔لہٰذا دونوں کے درمیان موازنہ سرے سے درست نہیں ہے۔ پھر ایک اور جو بہت بڑا فرق ہے جسے انصاف پسند سیکولر لوگ بھی مانتے ہیں ‘ کہ ماضی میں جتنے لوگ آئے چند کو چھوڑ کر باقی سب یہاں رہے ‘بسے اور یہیں ان کی قبریں بنیں ۔ انہوں نے اس مٹی کو اپنا لیا۔ پھر وہ دور سلطنت کا دور تھا۔ وہاں بادشاہوں میں تعیش تو تھا لیکن سرمایہ داری نہیں تھی۔ انڈسٹریل ریولیوشن جب آیا ہے اس کے بعد ایک تو ان کو خام مال (raw material)چاہیے تھا‘ دوسرا ان کو منڈیاں چاہئیں تھیں۔ یہ دونوں کام انہوں نے کیے۔ بہرحال پہلے یہ نہیں تھا کہ پیسہ جمع کرنا ہے اور اسے مزید بڑھانا ہے۔
ایک ہندو مؤرخ ہربنس مکھیہ نے یہ فرق واضح کیا ہے کہ ہندوستان میں انگریز سے پہلے جو حملہ آور آتے رہے ان میں اور انگریز میں کیا فرق تھا۔ اس کے لیے انہوں نے کچھ مثالیں دیں۔ ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ اکبر کے دور میں عبد الرحیم خانِ خاناں ایک بہت مشہور شاعر تھے جو بڑے عہدے دار بھی تھے۔ اس زمانے میں فارسی کے ایک مشہور شاعر نظیری تھے۔ نظیری نے آکر ان سے کہا کہ بھائی میں نے کبھی ایک لاکھ روپے اکٹھے نہیں دیکھے‘ تو خانِ خاناں نے ایک لاکھ روپے ان کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ جب نظیری نے ایک ساتھ ایک لاکھ روپے دیکھے تو کہا :خدا کا شکر ہے مَیں نے ایک لاکھ روپے اکٹھے دیکھ لیے۔ خانِ خاناں نے کہا کہ بھائی اتنے معمولی کام کے لیے خدا کا شکر آپ کیوں ادا کر رہے ہیں۔ پھر وہی سارے روپے نظیری کے حوالے کر دیے۔ چنانچہ وہ مؤرخ کہتے ہیں کہ اس عہد کے لوگوں میں اتنی سخاوت تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مغربی سامراج کی دولت سے محبت کا جائزہ لیں کہ غالب نے پنشن کی وصولی کے لیے کتنی جوتیاں چٹخائیں اور کتنے چکر لگائے!لہٰذا دولت کی طرف بے نیازی کا رویہ عہد ِوسطیٰ اور جدید عہد میں خط ِامتیاز کھینچتا ہے‘ اور یہ بہت جوہری فرق ہے۔
علم کی تقسیم: کار آمد علم کی ترویج
انگریز کے آنے کے بعد تین قسم کی تبدیلیاں آئیں‘ ان میں زبان‘ علم اور تعلیم میں تبدیلی شامل تھی۔ علم اور تعلیم ایک نہیں ہے۔ تعلیم پورے میکنزم کا نام ہے‘ یعنی اپنا ورثہ‘ تہذیبی اوضاع اور علوم کو آگے منتقل کرنے کا پورا عمل تعلیم کہلاتا ہے۔ چنانچہ ایک انہوں نے زبان کو بدل دیا اور اس کی جگہ ایک اجنبی زبان لے کر آئے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ان کی نظر میں مقامی زبانیں غیر علمی زبانیں ہیں۔ ایک جملہ بہت معروف ہے کہ میکالے نے کہا تھا کہ ہندوستان کا کل علمی سرمایہ یورپ کی لائبریری کی ایک شیلف کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہ یہاں ان کی زبانوں میں کوئی بڑائی ہے اور نہ علوم میں کوئی وسعت ہے۔ اگرچہ ابتدا میں انہوں نے کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا جس میں مقامی زبانوں کی ترویج کی گئی‘ مگر پھریہ تجویز لائی گئی کہ ہمیں انگریزی زبان کو رائج کرنا چاہیے۔ اس تحریک میں ایک بڑے عہدے دار ٹی بی میکالے نے اہم کردار ادا کیا۔ آج بھی برِ صغیر پاک و ہند میں جو نظامِ تعلیم رائج ہے اس کا بانی وہی میکالے ہے۔ اس نے جو مقصد متعین کیا اسے چھپا کر نہیں رکھا۔ اس نے واضح طور پر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے علوم سیکھیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علوم بھی ہمارے ہوں اور زبان بھی ہماری ہو۔ پھر علم کے حوالے سے ان کا تصور Knowledge Useful یعنی کار آمد علم کا ہے کہ ہمارا علم کار آمد ہونا چاہیے۔ کار آمد ہونے کا مطلب ہے کہ ہم یہاں سے سرمایہ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہماری حکومتی مشنری چلانے کے لیے یہ لوگ کار آمد ہیں یا نہیں! اس اعتبار سے وہ علم جو کار آمد نہیں ہے اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اب جو روایتی علم تھا وہ کار آمد نہیں تھا اس لیے اسے نصابِ تعلیم سے خارج کر دیا گیا۔ شیخ الہند رحمہ اللہ جب ۱۹۲۰ء میں مالٹا سے رہائی کے بعد علی گڑھ گئے تووہاں انہوں نے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم انگریزوں کے لیے سستے مزدور پیدا کریں۔
کار آمد علم کے تصور نے ہمارے پورے نظامِ تعلیم میں تبدیلی پیدا کی‘ جس کی وجہ سے آج تک ہم اسی طرزِ عمل پر چل رہے ہیں۔ یعنی وہ جو انگریزوں کے لیے سستے مزدور پیدا کرنے کا عمل تھا وہ آج بھی لمز اور آئی بی اے میں جاری ہے۔ سافٹ ویئر سینٹرز‘ کال سینٹرز میں بیٹھے ہوئے کسی کا نام عبد اللہ ہے ‘کسی کا نام عبدالرحمٰن ہے لیکن وہ انگریزی لہجے میں بات کر رہے ہیں اور امریکہ میں لوگوں کے مسائل وہ یہاں بیٹھ کے حل کر رہے ہیں۔ عالمگیریت کے بعد جو سستے مزدور ہیں انہیں آؤٹ سورس کر دیا گیا۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ بھائی لیبر بہت مہنگی ہے ‘فی گھنٹا اتنے ڈالر یا پائونڈ نہیں دیں گے۔ اسی طرح ان کے ممالک میں ورکنگ کنڈیشنز بہت سخت ہیں۔ اس کے برعکس سری لنکا‘ بنگلہ دیش اور ویت نام میں تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہاں لیبر سستی ہے۔ اسی طرح بارہ بارہ گھنٹے کام کروائیں ‘کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ۵۰ درجے سنٹی گریڈ سے اوپر کھلی جگہ پر لیبر سے کام نہیں لیا جا سکتا‘ مگر عرب امارات‘ کویت وغیرہ میں درجہ ٔ حرارت کبھی ۵۲ یا ۵۳ پر بھی جاتا ہے مگر پھر بھی آفیشل درجہ حرارت کو ۴۸ یا ۴۹ سے بڑھنے نہیں دیا جاتا تاکہ اعتراض نہ کیا جاسکے۔ اس تصورِ علم کا اثر ادب پر بھی پڑا۔ حالی نے مثنوی میں اپنے علوم‘ علم ِ کلام‘ فقہ‘ تصوف‘ بلاغت‘ منطق اور فلسفے پر ایک ایک کا نام لے کر تبرا کیا ہے۔ ادب پر تبرا کرتے ہوئے وہ کہتےہیں: ؎
وہ شعر اور قصائد کا ناپاک دفتر
عفونت میں سنڈاس سے جو ہے بدتر
گنہ گار واں چھوٹ جائیں گے سارے
جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے
اسی طرح ڈپٹی نذیر احمد کے افسانے ’’توبۃ النصوح ‘‘سے میں کچھ اقتباسات پڑھنا چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علم کا تصور‘ ادب کا تصور کیسے بدلا۔ وہ کہتے ہیں کہ نصوح جب خلوت خانے میں پہنچا تو وہاں کیا دیکھتا ہے کہ:
’’اُس میں تکلف کے معمولی سازو سامان کے علاوہ کتابوں کی الماری تھی۔ دیکھنے میں تو اتنی جلدیں تھیں کہ انسان ان کی فہرست لکھنی چاہے تو سارے دن میں بھی تمام نہ ہو‘ لیکن کیا اردو کیا فارسی سب کی سب کچھ ایک ہی طرح کی تھیں: جھوٹے قصے‘ بےہودہ باتیں‘ فحش مطلب‘ لچے مضمون‘ اخلاق سے بعید‘ حیا سے دور.....آخر میں یہی رائے قرار پائی کہ ان کا جلا دینا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ بھری الماری کتابیں‘ لکڑی کنڈے کی طرح اوپر تلے رکھ آگ لگا دی۔ نصوح کا یہ برتاؤ دیکھ اندر سے باہر تک تہلکہ اور زلزلہ پڑ گیا۔ علیم دوڑا دوڑا جا اپنا’’کلیاتِ آتش‘‘ اور ’’دیوانِ شرر‘‘ اٹھا لایا‘ اور باپ سے کہا کہ جناب میرے پاس بھی یہ دو کتابیں اسی طرح کی ہیں۔ نصوح نے ان کتابوں کو بھی دو چار جگہ سے کھول کر دیکھا اور کہا کہ واقع
میں ان کے مضامین بھی جہاں تک میں دیکھتا ہوں برے اور بے ہودہ ہیں لیکن تمہاری نسبت مجھ کو خدا کے فضل سے اطمینان ہے.....علیم نے ’’آتش‘‘ کو دہکتی آگ اور ’’شرر‘‘ کو جلتے انگاروں میں پھینک دیا۔ علیم کی دیکھا دیکھی میاں سلیم نے بھی ’’واسوخت امانت‘‘ لا باپ کے حوالے کی اور کہا کہ ایک دن کوئی کتاب فروش کتابیں بیچنے لایا تھا۔ بڑے بھائی صاحب نے فسانۂ عجائب‘ قصہ ٔ گل بکاؤلی‘ آرائشِ محفل‘ مثنوی میر حسن‘ مضحکاتِ نعمت خان عالی‘ منتخب غزلیاتِ چرکین‘ ہزلیاتِ جعفر زٹلی‘ قصائد ِہجویہ مرزا رفیع سودا‘ دیوانِ جان صاحب‘ بہارِ دانش باتصویر‘ اِندر سبھا‘ دریاے لطافت میر انشاء اللہ خان‘ کلیاتِ رند وغیرہ بہت سی کتابیں اس سے لی تھیں۔‘‘ (توبۃ النصوح‘ ص:۳۳۲‘ مجلس ترقی ادب لاہور)
آپ غور کریں کیا ذہن سازی ہو رہی ہے کہ یہ جو ہمارا علم تھا یہ بےکار تھا۔ حسن عسکری صاحب نے محسن کاکوروی پر ایک بڑا اچھا مضمون لکھا ہے کہ انہوں نے نعت کے تصور کو کیسے بدلا‘ اور جو جدید شاعر آئے انہوں نے کس طریقے سے پیغمبرﷺ کو humanize کیا۔ یعنی پہلے زیادتی یہ تھی کہ پیغمبرﷺ کو لوگوں نے divinize کیا تھا‘ مگر پھر پیغمبرﷺ کو humanize کیا گیا۔ ؎
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
مرادیں غریبوں کی بر لانے والا
اگرچہ یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں‘ مگر یہاں علم اور ادب میں افادیت کا پہلو نمایاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
نظم ِ تعلیم پر اثرات
جب استعمار آیا تو علی گڑھ جیسے جدید نظام کے اداروں پر اثرات تو ظاہرو باہر ہیں‘ مگر بات یہاں تک محدود نہیں رہی بلکہ اگر گہرائی میں اس کا جائزہ لیں تو روایتی نظم ِ تعلیم میں بھی غیر معمولی تبدیلی پیدا ہوئی۔ دینی تعلیم اور مدرسے کے نظم پر بھی اس جدید نظامِ تعلیم کا بہت اثر پڑا ہے۔ Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900 کے مصنفBarbara D.Metcalf ہیں۔ اُس میں اس بات کا ذکر ہے کہ مدرسے کا نظم اور اس کا تصور بدل گیا۔ مختلف اداروں کے بانیان انگریز کے یہاں آنے کے بعد کمپنی کی ملازمت سے وابستہ رہے۔ ملازمت کے دوران انہوں نے یہاں انگریزوں کا نظم اور انتظام دیکھا‘ ان کی خاص طرح کی مینجمنٹ دیکھی۔ جو روایتی نظمِ تعلیم تھا اس میں نہ کوئی متعین نصاب ہوتا تھا‘ نہ متعین سال ہوتے تھے کہ اتنے سال میں یہ کورسز ہو ں گے‘ اور نہ ہی کلاسز کا کوئی مخصوص نظام تھا۔ البتہ انگریز کے آنے کے بعد روایتی دینی اداروں میں کافی تبدیلیاں آئیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ چندے کا پیدا ہو گیا جو آ ج تک چل رہا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے شروع ہی میں اصولِ ہشت گانہ لکھے تھے ۔اس میں سب سے پہلے یہ بات واضح کی گئی کہ مدرسہ کسی مستقل آمدنی کے بجائے اصحابِ خیر کے تعاون سے چلےگا۔ اسی طرح ایک نظم کے تحت ادارے کے امور انجام دیے جائیں گے۔ اصولِ ہشت گانہ کے موضوعات کو دیکھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تبدیلی کیسے پیدا ہوئی۔ پھر جدید ادارہ جاتی مسائل پیدا ہوئے۔ دیوبند جیسے روایتی اور دینی ادارے میں طلبہ کی ہڑتالیں ہوئیں۔ ہڑتال کے خلاف حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ۔ غور کریں تو یہ سارا اس نظم کی وجہ سے ہوا۔ اسی طرح جدید نظم سے پہلے سوال یہ ہوتا تھا کہ آپ کے استاذ کون ہیں‘ آپ نے کن سے پڑھا ہے؟ جبکہ آج یہ پوچھا جاتا ہے کہ: آپ کہاں سے فارغ ہیں؟ اب استاد کون ہے‘ یہ اہم نہیں رہا۔ جدیدیت (modernity) کی تعریف ایک یہ بھی ہے کہ ہیومن ایجنسی کا نان ہیومن سٹرکچرز کے تابع ہو جانا۔ اس تبدیلی کے باوجود مدرسہ جیسا تیسا تھا‘ ہماری چاہت یہ ہوتی تھی کہ یونی ورسٹی اس کے ماڈل پر آئے لیکن اب تو الٹا مدرسہ یونی ورسٹی کے ماڈل پر ڈھل رہا ہے‘ اور یونی ورسٹی کے نظام کو اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسے ایک سانحہ ہی کہہ سکتے ہیں۔
بہرحال جدید نظام نے ہمارے اوپر جو اثرات مرتب کیے اور اس کی وجہ سے جو تبدیلی آئی ‘ وہ بہت واضح ہے۔ آپ ’’مسافرانِ لندن‘‘ کا مطالعہ کریں جب سر سید انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے بیٹے محمود کو لے گئے تھے۔ اس سفر میں ان کے ایک اور بیٹے اور خادم بھی تھے۔ ان کا سفر سمندری جہاز کے ذریعے تھا اور راستے میں سید محمود بیمار ہوگئے۔ جب طبیب نے ایسی دوا تجویز کی جس میں الکحل ملا ہوا تھا تو سید محمود نے پینے سے انکار کیا‘ باوجود اس کےلوگ سمجھا رہے ہیں کہ یہ عذر ہے اور دوائی کے طور پر اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اس حالت میں انہوں نے کئی دن بہت مشکل سے گزارے لیکن شراب پی کے نہیں دی۔ پھر یہی سید محمود جب تعلیم مکمل کر کے آئے تو یہ تبدیلی آئی تھی کہ ان کی وفات بھی شراب نوشی کی کثرت کی وجہ سے ہوئی۔ اسی طرح انہوں نے اپنے والد سرسید احمد خان کو گھر سے بھی نکال دیا اور سر سید کا جنازہ کسی اور جگہ سے اٹھا۔ ’’تقاریر ِسر سید‘‘ میں سب سے چھوٹی مگرعبرت آموز تقریر اسی سید محمود کے بارے میں ہے۔ مرتب اسماعیل پانی پتی نے اس کا عنوان قائم کیا ہے: ’’سرسید کی سب سے مختصر اور درد انگیز تقریر:۱۸۹۷ء بمقام علی گڑھ‘‘۔ شروع میں اسماعیل پانی پتی کا ایک چھوٹا سا نوٹ ہے کہ:
’’آنر ایبل جسٹس سید محمود ‘سر سید کے فرزند نے جب ہائی کورٹ کی ججی سے استعفا دے دیا تو اس کے بعد نہ معلوم کس طرح ان کو شراب پینے کی لت پڑ گئی۔ سر سید کو خبر ہوئی تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ بیٹا یہ عادت چھوڑ دے‘ مگر باپ کی ہر نصیحت بے اثر رہی۔ آخر تنگ آ کر سر سید نے ایک پرائیویٹ اجتماع کیا‘ جس میں اپنے خاص خاص دوستوں کو بلایا‘ سید محمود بھی موجود تھے‘ مگر یہ کسی کو پتا نہ تھا کہ آخر سر سید نے کیوں لوگوں کو جمع کیا ہے‘ اور ہر شخص اپنی جگہ پر حیران تھا۔ جب سب لوگ آگئے تو سر سید کھڑے ہوئے اور انتہائی رقت ِقلب کے ساتھ انہوں نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا: ’’میرے معزز احباب! میں نے آپ صاحبان کو اس وقت اس لیے یہاں تشریف لانے کی زحمت دی ہے کہ آپ سب حضرات جو میرے ہمدرد اور بہی خواہ ہیں‘ میں آپ سب سے نہایت منّت و زاری کے ساتھ اپنی ایک دعا پر آمین کہنے کی التجا کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ میرے فرزند سید محمود کی موت کو شراب آلود زندگی پر ترجیح دیں اور میرے ساتھ اس کی موت مانگنے میں شریک ہوں۔ میں خداوند ِکریم کے حضور اس کی موت کی دعا مانگتا ہوں اور آپ میرے ساتھ آمین کہیں۔ چونکہ میرے نزدیک شرابی زندگی سے موت بدرجہ بہتر ہے۔‘‘
یہ اس نظام تعلیم کے اثرات کی بالکل ٹھوس مثال ہے کہ سر سید کے بیٹے سید محمود جب انگلینڈ جا رہے تھے اس وقت ان کی حالت کیا تھی‘ پھر جب پڑھ کے آگئے‘ جج بن گئے اور انگریزوں سے بہت اچھے مراسم تھے اور پھر ان کا حال یہ ہوا۔ شیخ محمد اکرام نے ’’موجِ کوثر‘‘ میں جامعہ ملیہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ کن حالات میں بنی۔ اس کے ضمن میں وہ کہتے ہیں کہ سر سید نے جو خواب دیکھا تھا علی گڑھ کا‘ علی گڑھ اس کی تعبیر ثابت نہیں ہو سکا۔ وہ لکھتے ہیں:
’’سرکاری ملازمت کو علی گڑھ کا اہم ترین عملی مقصد بنانے کا برا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں ایک پست درجے کی مادیت اور شیئیت پسندی پیدا ہو گئی‘ جو نہ صرف طلبہ کی مذہبی ترقی اور روحانی تربیت کے لیے ناسازگار تھی بلکہ جس نے ان کی اصل دنیوی ترقی پر بھی اثر ڈالا۔ دنیا میں ترقی کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحت ِجسمانی‘ ہوش و خرد اور کیرکٹر۔ صحیح کامیابی کے لیے تینوں چیزیں درکار ہیں‘ لیکن کیرکٹر کی ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ اگر عزائم بلند نہ ہوں یا بلند ارادوں کی تکمیل کے لیے شوق‘ محنت‘ مستعدی‘ قربانی‘ ارادے کی پختگی‘ ایمانِ کامل اور طبیعت پر قابو نہ ہو تو قوی ہیکل جثوں اور تیز طرار دماغوں سے فائدہ نہیں اُٹھایا جا سکتا۔ علی گڑھ میں یہی ہوا۔ حقیقی یا خیالی ضروریات نے مطمحِ نظر کو محدود کر دیا اور روحانی کمزوری سے کیرکٹر پست ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جدید اور باقاعدہ تعلیم کے باوجود نہ صرف قدیمی نقطۂ نظر سے بلکہ دنیوی اور ظاہری کامیابی کے لحاظ سے بھی طلبہ ٔ علی گڑھ اس بلندی پر نہ پہنچے جو اس کالج کے دقیانوسی اور قدیم الخیال لیکن روحانی طور پر سر بلند اور کیرکٹر کے لحاظ سے پختہ کار بانیوں نے حاصل کی تھی۔ جن لوگوں نے مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر تعلیم پائی تھی ان میں تو سرسید‘ محسن الملک اور وقار الملک جیسے مدبر اور منتظم پیدا ہو گئے۔ جو لوگ انگریزی سے قریب قریب نا واقف تھے اور جن کے لیے تمام مغربی ادب ایک گنجِ سربستہ تھا انہوں نے نیچرل شاعری اور ایک جدید ادب کی بنیاد ڈال دی اور آبِ حیات‘ سخن دانِ فارس‘ شعر و شاعری‘ مسدسِ حالی جیسی کتابیں تصنیف کر لیں۔ لیکن جن روشن خیالوں نے کالج کی عالی شان عمارتوں میں تعلیم حاصل کی تھی اور جن کی رسائی مغرب کے بہترین اساتذہ اور دنیا بھر کے علم و ادب تک تھی‘ وہ مطمحِ نظر کی پستی اور کریکٹر کی کمزوری سے فقط اس قابل ہوئے کہ کسی معمولی دفتر کے کل پرزے بن جائیں یا اپنے بانیوں کے خیالات اور اُن کی عظمت کا کوئی اندازہ کیے بغیر جو باتیں ان کے مخالف کہہ رہے تھے (جو خود مکتبوں اور مسجدوں کے پروردہ تھے) انہی کو زیاده آب و تاب اور رنگ وروغن دے سکیں۔‘‘
(موجِ کوثر‘ ص: ۱۴۷‘۱۴۸)
اس مادیت اور شیئیت پسندی کا جو اثر اساتذہ پر بھی ہوا اس کے متعلق لکھتے ہیں:
’’اساتذہ کی علمی اہلیت اور فنی قابلیت تو ساری تھی‘ لیکن ان کی نگاہیں بلند نہ تھیں۔ انہوں نے یہ تو نہ کیا کہ دولت ِدنیا میں سے مختصر سے مختصر پر کفایت کریں‘ اور اپنے علمی شوق کی تکمیل‘ تصنیف و تالیف اور نامِ نیک کو حاصلِ زندگی سمجھیں۔ ان کے نزدیک علم و فن کھانے کمانے کا ذریعہ تھا۔ اس لیے بالعموم یہی خواہش ہوتی کہ علمی زندگی پر مُردنی چھا جائے تو کوئی حرج نہیں‘ لیکن مادی زندگی کی بہار ضرور لوٹی جائے۔‘‘(موجِ کوثر‘ ص: ۱۴۹)
پھر آگے کہتے ہیں:
’’علی گڑھ کے پروفیسروں میں علمی قابلیت‘ مذاق کی شستگی اور نیک ارادوں کی کمی نہیں‘ لیکن جب خیالات کا رخ پھر گیا اورہمتیں پست ہو گئیں تو یہ خوبیاں بے کار ثابت ہوئیں۔ اساتذہ کا وقت ِعزیز ڈرائنگ روم کی تزئین‘ خوش معاشی‘ ضیافت بازی‘ کلب بازی‘ گپ بازی (اور ہاں‘ پارٹی بازی) کی نذر ہونے لگا۔ اس فضا میں علمی زندگی کا فروغ پانا محال تھا۔‘‘ (موجِ کوثر‘ ص: ۱۵۰)
پھر مزید کہتے ہیں:
’’خیالات میں ایک عجب طرح کی ’’ڈھل مل یقینی‘‘ یعنی روحانی کمزوری اور ذہنی بزدلی آ گئی۔‘‘
(موجِ کوثر‘ ص: ۱۵۰)
اور آگے کہتے ہیں کہ کیفیت یہ ہوگئی ہے کہ اگر:
’’ کسی طرف سے اسلام یا مسلمانوں یا علی گڑھ کے خلاف کوئی آواز اٹھے‘ اس پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے علی گڑھ سے نکلیں گے۔‘‘ (موجِ کوثر‘ ص: ۱۵۰)
اسی طرح Beverley Nicholsایک مصنف ہے ‘جو ہندوستان میں رہا ہے۔ غالباً ۱۹۴۴ء میں انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کانام ہے: Verdict on India۔اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہوا۔ اس میں آخری باب کا نام ہے: To Quit or Not to Quit? ۔ چونکہ اس زمانے میں ’’ہندوستان چھوڑ دو‘‘ کی تحریک چل رہی تھی‘ تو انگلستان میں بھی بحثیں چل رہی تھیں کہ کیا کریں ! مصنف نے لکھا ہے کہ یہ لوگ تو اس قابل ہی نہیں کہ اپنا دفاع کر سکیں‘ ان کو ہماری ضرورت ہے۔ ہم سے پہلے یہاں بہت بڑا فساد برپا تھا‘ طوائف الملوکی تھی۔ ہم یہاں آئے اور اس ملک کو استحکام بخشا۔ یہاں امن نہیں تھا‘ ہم نے ہندوستان کو امن دیا۔ کوئی طاقت ور قانون نہیں تھا گویا سرزمین بے آئین تھا‘ ہم نے قانون دیا ۔اور آخر بہت بڑا دعویٰ کیا کہ ہم نے ہندوستان کو آزادی بھی دی۔ آپ اندازہ کریں کہ کس ڈھٹائی سے یہ بھی کہا جا رہا ہے اور آج تک انگریز کے اس قابوس کا بھوت یہاں موجود ہے۔
بہرحال اب سوال یہ ہے کہ :کرنا کیا چاہیے اور ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ تنقیدی جائزہ لینا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہونا چاہیے مگر یہ خیال کریں کہ ساری تنقید دین اور دینی روایت پر نہ ہو بلکہ جو جدید علم اور جدید ادارے ہیں‘ ان کو بھی تنقیدی نظر سے دیکھیں۔ ان پر بھی غور کریں کہ ان افکار‘ ان اداروں اور ان آلات میں سے کون سے ایسے ہیں جو ہماری تاریخ‘ ہماری روایت‘ ہمارے انفس اور ہمارے آفاق کے ساتھ موافق ہیں ۔انہیں لینا چاہیے جبکہ جو سازگار نہیں ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ اکبر نے کہا تھا: ؎
ہشیار رہ کے پڑھنا اس جال میں نہ پڑنا
یورپ نے یہ کہا ہے‘ یورپ نےوہ کہا ہے !