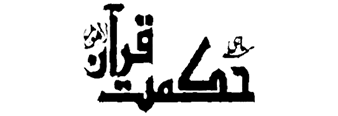(تذکر و تدبر) مِلاکُ التأویل(۳۹) - ابو جعفر احمد بن ابراہیم الغرناطی
8 /مِلاکُ التأوِیل (۳۹)تالیف : ابوجعفر احمد بن ابراہیم بن الزبیرالغرناطی
تلخیص و ترجمانی : ڈاکٹر صہیب بن عبدالغفار حسنسُورۃُ الاَنْبِیَاء(۲۵۱) آیت ۴۵
{وَلَا یَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآئَ اِذَا مَا یُنْذَرُوْنَ(۴۵) }
’’اور بہرے پکار کو نہیں سن سکتے جب کہ انہیں ڈرایا جا رہا ہو۔‘‘
جماعت قراء (یعنی ابن کثیر‘ نافع‘ عاصم‘ ابوعمرو‘ حمزہ‘ الکسائی وغیرہم) نے اسی طرح پڑھا ہے ‘سوائے ابن عامر کے جو اسے یوں پڑھتے ہیں:
’’وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ‘‘ (ت پر ضمہ اور اَلصُّمَّ پر فتحہ )
’’اور آپ بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے۔‘‘
اور سورۃ النمل (آیت۸۰) اور سورۃ الروم (آیت ۵۲) میں ارشاد فرمایا:
{وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآئَ }
’’اور آپ بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے۔‘‘
یہاں جمہور نے تو ابن عامر کی طرح تُ پر ضمہ اور الصُّمَّ پر فتحہ کے ساتھ پڑھا ہے‘لیکن ابن کثیر نے یہاں بھی سورۃ الانبیاء کی آیت کی طرح تَ پر فتحہ اور الصُّمُّ ضمہ کے ساتھ پڑھاہے۔
گویا تینوں آیات کو دو طرح پڑھا گیا ہے لیکن اختتامی کلمات مختلف ہیں۔سورۃ الانبیاء کی آیت کے آخر میں کہا گیا : {اِذَا مَا یُنْذَرُوْنَ} جبکہ سورۃ النمل اور سورۃ الروم کے آخر میں کہا گیا: {اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِیْنَ} ’’جب کہ وہ پیٹھ پیچھے کر کے بھاگ جاتے ہیں ۔‘‘ تو اس اختلاف کی وجہ کیا ہے ؟
اس کا جواب یہ ہے ‘ واللہ اعلم‘ کہ سورۃ الانبیاء کی آیت سے پہلے نبیﷺ کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے مخاطبین کو اللہ کی وحی سنا کر ڈرائیں اور پھر نبیﷺ کو یہ بھی بتا دیا کہ علم أزلی کے مطابق ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا ‘یعنی یہ اپنے کفر پر قائم رہیں گے‘ اور آپ کو یہ بتانا آپ کی تسلی کے لیے ہے۔
اس کے بعد جب یہ فرمایا :{وَلَا یَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَآئَ } تو اللہ کے رسول ﷺاللہ ہی کی طرف سے دی جانے والی خبر بتا رہے ہیں کہ جس وقت انہیں ڈرایا جاتا ہے‘ وہ اس دعوت کو سننے کے قابل نہیں ہوتے اور دعوت کو قبول کرنے کے فوائد سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ یہی بات ان آیات میں بھی کہی گئی ہے:
{ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰی قُلُوْبِہِمْ اَکِنَّۃً اَنْ یَّفْقَہُوْہُ وَفِیْٓ اٰذَانِہِمْ وَقْرًاط } (الکہف:۵۷)
’’ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھنے سے قاصر رہیں اور ان کے کانوں میں ایک بوجھ ڈال دیا ہے۔‘‘
لیکن سورۃ النمل اور سورۃ الروم میں جب یہ کہا گیا :
{ فَاِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰی وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ }
’’بے شک تم مُردوں کو سنا نہیں سکتے اور نہ ہی بہروں کو دعوت سنا سکتے ہو۔‘‘
تو یہ بتانے کے لیے کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہو گا ان کی حالت زار کی یوں تصویر کشی کی کہ وہ ایسے وقت میں بھاگتے نظر آتے ہیں:{اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِیْنَ} ۔اور یوں ان آیات سے ملحقہ اختتامی کلمات کی مناسبت واضح ہو جاتی ہے‘ واللہ اعلم!
(۲۵۲) آیت ۵۲۔۵۳
{ اِذْ قَالَ لِاَبِیْہِ وَقَوْمِہٖ مَا ہٰذِہِ التَّمَاثِیْلُ الَّتِیْٓ اَنْتُمْ لَہَا عٰکِفُوْنَ(۵۲) قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآئَ نَا لَہَا عٰبِدِیْنَ(۵۳)}
’’جب اُس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا: یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا: ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔‘‘
اور سورۃ الشعراء میں ارشاد فرمایا:
{ وَاتْلُ عَلَیْہِمْ نَبَاَ اِبْرٰہِیْمَ (۶۹) اِذْ قَالَ لِاَبِیْہِ وَقَوْمِہٖ مَا تَعْبُدُوْنَ(۷۰) قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَہَا عٰکِفِیْنَ(۷۱) قَالَ ہَلْ یَسْمَعُوْنَکُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ(۷۲) اَوْ یَنْفَعُوْنَکُمْ اَوْ یَضُرُّوْنَ(۷۳) قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآئَ نَا کَذٰلِکَ یَفْعَلُوْنَ(۷۴) }
’’اور انہیں ابراہیم کی خبر بھی بتا دو! جب اُس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا: یہ تم کیا عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور پھر ان کے مجاور بن کر بیٹھے رہتے ہیں۔ کہا: کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو‘یا تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں یا تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟کہنے لگے: بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔‘‘
یہاں دو سوال جنم لیتے ہیں:
پہلی آیت میں {قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآئَ نَا} کہا گیا اور دوسری آیت میں {قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآئَ نَا} کہا گیا یعنی دوسری آیت میں ’’بَلْ‘‘ کا اضافہ کیا گیا۔
دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا خطاب دونوں آیا ت میں اختلاف کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ پہلی آیت میں کہا گیا: {مَا ہٰذِہِ التَّمَاثِیْلُ الَّتِیْٓ اَنْتُمْ لَہَا عٰکِفُوْنَ(۵۲)} اور دوسری میں کہا گیا:{مَاتَعْبُدُوْنَ}۔جب قِصّہ ایک ہی ہے تو یہ اختلافِ حکایت کیوں ہے؟
پہلی بات کا جواب یہ ہے ‘واللہ اعلم‘ کہ دونوں جگہ سوال مختلف ہیں‘ اس لیے دونوں کا جواب بھی مختلف ہے۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء کی آیت میں سوال اس شخص کی طرف سے آیا ہے جو ان کے معبودات کو بخوبی جانتا ہے‘ وہ انہیں عبادت کرتے دیکھتا رہا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کیسے وہاں مجاور بنے بیٹھے رہتے ہیں ۔ اور اس لحاظ سے اس کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں:
{مَا ہٰذِہِ التَّمَاثِیْلُ الَّتِیْٓ اَنْتُمْ لَہَا عٰکِفُوْنَ(۵۲) }
’’یہ مورتیاں کیسی ہیں کہ جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟‘‘
تو انہیں پھر یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہم اپنے آباء و اَجداد کی تقلید میں ایسا کرتے ہیں:
{وَجَدْنَآ اٰبَآئَ نَا لَہَا عٰبِدِیْنَ(۵۳) }
’’ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔‘‘
گویا وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ مورتیاں ہیں جنہیں تصویر کی شکل میں گھڑا گیا ہے۔ لفظ ’’تمثال‘‘ کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی چیز کی ہوبہو تصویر بنائی جائے۔ اس طرح وہ ایک کافی و شافی جواب دینے سے اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس با ت کو بھی محسوس کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی عبادت کررہے ہیںجن کو وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں‘ ان کے پاس سوائے تقلید آباء کے اور کوئی حُجّت دکھائی نہیں دیتی۔
جہاں تک سورۃالشعراء کی آیات کا تعلق ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ’’مَا تَعْبُدُوْنَ‘‘ کہہ کر یہ سوال کیا ہے کہ ان معبودات کی ماہیت کیا ہے‘ کیفیت کیا ہے؟ گویا وہ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس چیز کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہیں جو عبادت کے لائق نہیں ‘ تو انہوں نے پھر یہ پوچھا کہ بتائو ان بتوں کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے کہ تم انہیں اپنا معبود سمجھتے ہو؟ انہوں نے جواباً کہا:
{ نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَھَا عٰکِفِیْنَ}
’’ہم کچھ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور پھر وہاں مجاور بنے بیٹھے رہتے ہیں۔‘‘
یعنی اس بات کا اقرار کر لیا کہ وہ صرف بت ہیں اور یہی ان کی ماہیت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بالکل خاموش کرنے کے لیے یہ سوال کر دیا:
{ہَلْ یَسْمَعُوْنَکُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ(۷۲) اَوْ یَنْفَعُوْنَکُمْ اَوْ یَضُرُّوْنَ(۷۳) }
’’جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہیں سنتے ہیں ؟یا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟‘‘
یعنی اگر وہ ایسی کوئی قدرت رکھتے ہوتے تو تم ان کی پوجا کرنے کا جواز رکھ سکتے تھے‘ اور جب ایسا نہیں ہے تو ان کی عبادت کرنا کیا معنی رکھتا ہے ؟اب جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے انہوں نے آباء و اجداد کی تقلید کا بہانہ کیا:
{ بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآئَ نَا کَذٰلِکَ یَفْعَلُوْنَ(۷۴)}
’’بلکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا تھا۔‘‘
اب یہاں با ت کو ’’بَلْ‘‘ سے شروع کرنا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ان کے معبود نہ کسی پکار کو سنتے ہیں‘ نہ ہی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ان میں یہ قدرت پائی جاتی تو وہ جواباً ’’بَلْ‘‘ کا سہارا نہ لیتے۔سیدھا سیدھا کہہ اٹھتے کہ ہاں وہ تو سنتے ہیں‘ نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
اب اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے نہ تو ان صفات کا اقرار کیا ہے اور نہ ہی انکار‘تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کا اقرار کر رہے ہیں؟ تو جواباً کہا جائے گا کہ اگرانہیں ذرا سا بھی شبہ ہوتا کہ ان میں یہ صفات پائی جاتی ہیں تو وہ لپک کر اُسے پیش کرتے نہ کہ ’’بَلْ‘‘ کے سہارے راہِ فرار اختیار کرتے!!
ان کے سامنے صرف دو ہی راستے تھے ‘ یا تو وہ ایک محسوس اور معقول چیز کا انکار کرتے ہوئے یہ کہتے کہ نہیں وہ تو سنتے ہیں اور نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں (اور ایسا کہنا ان کے لیے ممکن نہ تھا) یا وہ ان صفات کا انکار کرتے اور ایسی صورت میں ان پر حُجّت قائم ہو جاتی کہ اگر وہ اتنے کمزور اور عاجز ہیں تو پھر ان کی عبادت کرنا کیا معنی رکھتی ہے؟ اس لیے انہوں نے آباء و اَجداد کی تقلید کا سہارا لے کر بات ختم کرنے کی کوشش کی‘ اور اسی لیے پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ کر ان کو آئینہ دکھلا دیا:
{ لَقَدْ کُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُکُمْ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ (۵۴) }
’’بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب ہی کھلی گمراہی میں تھے۔‘‘
گویا سورۃالشعراء کی آیت میں ’’بَلْ‘‘ کا لانا مناسب تھا کہ وہاں بتوں کی صفات کے بارے میں ایک چبھتا ہوا سوال کیا گیا تھا کہ جس کے جواب میں ’’بَلْ‘‘ کہہ کر راہِ فرار اختیار کی گئی تھی۔ لیکن سورۃ الانبیاء میں ایسا سوال نہیں اٹھایا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہاں پر بھی ’’بَلْ‘‘ لایا جاتا ۔
(عربی نحو میں اسے ’’بَلْ‘‘ للاضراب کہا جاتا ہے‘ یعنی اگر سیدھا سیدھا جواب نہ دیا جانا ہو تو پھر بات کو پلٹنے کے لیے ’’بَلْ‘‘ لایا جاتا ہے۔ اردو میں یہی لفظ ذرا سے اضافے کے ساتھ ’’بلکہ‘‘ کی شکل میں موجود ہے۔ (مترجم)
دوسرا سوال کہ قصہ ایک ہی ہے تو جواب مختلف کیوں ہے؟
جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ قصہ ایک ہی ہو‘ عین ممکن ہے کہ یہ دو الگ الگ اوقات اور الگ الگ جگہوں میں وقوع پزیر ہوا ہو ‘اور اگر ایسی بات ہے تو ضروری نہیں کہ دونوں جگہ ایک ہی جواب لازمی ہو ‘واللہ اعلم!
(۲۵۳) آیت ۷۰
{وَاَرَادُ وْا بِہٖ کَیْدًا فَجَعَلْنٰہُمُ الْاَخْسَرِیْنَ(۷۰) }
’’اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ فریب کرنا چاہا تو ہم نے انہیں ان لوگوں میں بنا دیا جو گھاٹے میں سب سے زیادہ تھے۔‘‘
اورسورۃ الصافات میں ارشاد فرمایا:
{فَاَرَادُوْا بِہٖ کَیْدًا فَجَعَلْنٰہُمُ الْاَسْفَلِیْنَ (۹۸)}
’’اور انہوں نے اس کے ساتھ فریب کرنا چاہا تو ہم نے انہیں نیچے سے نیچے کر دیا۔‘‘
یہاں دو سوالات پیدا ہوتے ہیں:
(۱) جب دونوں آیات کا مقصود ایک ہی ہے تو اختلافِ عبارت کیوں ہے؟
(۲) جو الفاظ جس آیت کے ساتھ آئے ہیں وہ اسی کے ساتھ کیا خصوصیت رکھتے ہیں؟
دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ خسارہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں جو مال ہے یا دوسرے اسبابِ معیشت ہیں وہ اس کے ہاتھ سے چلے جائیں‘ یا یہ کہ وہ مال کمانے کے لیے خوب ہاتھ پیر مار رہا ہو لیکن ہاتھ کچھ نہ آتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ’’الْخُسْرَانُ الْمُبِیْنُ‘‘ (الحج:۱۱)(کھلا کھلا خسارہ) اس شخص کے لیے کہا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ناکام ہو جائے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ’’الْاَخْسَرِیْنَ‘‘ (سب سے زیادہ خسارے میں گرنے والے) وہ ہیں جن کا بروزِ قیامت کوئی وزن نہ ہو گا۔ ارشاد فرمایا:
{قُلْ ہَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْاَخْسَرِیْنَ اَعْمَالًا(۱۰۳) }
’’کہہ دیجیے کہ کیا میں تمہیں نہ بتائوں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے کون لوگ ہیں؟‘‘
{اَلَّذِیْنَ ضَلَّ سَعْیُہُمْ فِی الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَاوَہُمْ یَحْسَبُوْنَ اَنَّہُمْ یُحْسِنُوْنَ صُنْعًا(۱۰۴)}
’’یہ وہ لوگ ہیں کہ دُنیوی زندگی میں ان کی ساری جدّوجُہد رائیگاں گئی‘ پھر بھی وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔‘‘
{اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِاٰیٰتِ رَبِّہِمْ وَلِقَآئِہٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُہُمْ فَلَا نُقِیْمُ لَہُمْ یَوْمَ الْقِیٰمَۃِ وَزْنًا(۱۰۵) }(الکھف)
’’یہ وہ لوگ ہیںجنہوں نے اپنے ربّ کی آیات اور ربّ سے ملاقات کا انکار کیا تو ان کے سارے کے سارے اعمال رائیگاں ہو گئے ‘تو ہم قیامت کےدن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔‘‘
چنانچہ ایسے لوگوں سے زیادہ بدحال کوئی نہیں ہو گا۔
ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جب ان کے ساتھ مکر و فریب کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ سزا دی جو اُن کے برے عمل اور بدترین قصد کے مطابق تھی۔ ’’الاَخْسَرُوْنَ ھُمُ الْاَسْفَلُوْنَ‘‘ یعنی جو سب سے زیادہ خسارے میں ہوںگے وہی سب سے نیچے ہوں گے۔ اسی لیے کافر آخرت میں یہ تمنا کریں گے کہ جِنّ و انس میں سے جن جن لوگوں نے انہیں بہکایا تھا ‘ کاش ان کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوتا:
{رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَیْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْہُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِیَکُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِیْنَ(۲۹)}(فُصِّلَتْ)
’’اےہمارے ربّ! ہمیں جِنّ و اِنس میں سے ان لوگوں کو دکھا دے جنہوںنے ہمیں گمراہ کیا تھا کہ ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے کر لیں‘ تاکہ وہ نیچے سے نیچےہو جائیں۔‘‘
یہ دونوں صفات خسارہ اور نیچے گرایا جانا‘ ایک کافر کی ذلت کی نشانی ہے ‘ جو کہ خسرانِ مبین کی نشان دہی کرتی ہے۔ تو ان دونوں صفات میں کوئی تضاد نہیں ہے ‘ سوائے اس کے کہ یوں کہا جائے کہ نچلا ہونا اس کی ذات کے ساتھ ہے اور خسارہ کا حاصل ہونا خارج میں ایک حقیقت ہے۔نچلا ہونا ذلت کو زیادہ نمایاں کرتا ہے‘ اس لیے خارج میں حاصل ہونے والی چیز کو پہلے ذکر کیا اور نچلے ہونے کو بعد میں‘ کہ یہ وصف اس کی ذات کے ساتھ خاص ہے اور اسے بطور تتمہ ذکر کیا گیا ہے اور اس لیے بھی کہ اس میں ذلت اپنے عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ اور یہاں ترتیب ِمراتب کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ نیچے ہونا ترقی کی ضد ہے‘ اس لیے اس کا ذکر آخر میں آنا چاہیے تو واضح ہوگیا کہ ہر آیت کے الفاظ اپنی اپنی جگہ بالکل مناسب ہیں۔
کتاب ’’دُرّۃ التنزیل‘‘ کے مولف نے ایک اور اچھا نکتہ ذکر کیا ہے کہ سورۃ الصافات کی آیت ۹۷ میں کُفّار کا یہ قول نقل کیا گیا تھا:
{قَالُوا ابْنُوْا لَہٗ بُنْیَانًا فَاَلْقُوْہُ فِی الْجَحِیْمِ(۹۷)}
’’انہوںنے کہا کہ اس کے لیے ایک عمارت بنائو اور پھر اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو‘‘
یعنی انہوں نے چاہا تھا کہ اس تمام ڈرامہ بازی سے ان کا نام بڑا ہو گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کا اُلٹ کرکے دکھا دیا۔ وہ عُلُوّ (بلندی) چاہتے تھے تو وہ اسفل سافلین میں جا پڑے۔ واللہ اعلم!
(۲۵۴) آیت ۸۳۔۸۴
{وَاَیُّوْبَ اِذْ نَادٰی رَبَّہٗٓ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ(۸۳) فَاسْتَجَبْنَا لَہٗ فَکَشَفْنَا مَا بِہٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَیْنٰـہُ اَہْلَہٗ وَمِثْلَہُمْ مَّعَہُمْ رَحْمَۃً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِکْرٰی لِلْعٰبِدِیْنَ(۸۴) }
’’اور (یاد کرو) ایوب کو جب اس نے اپنے ربّ کو پکاراکہ مجھے بیماری نے آ گھیرا ہے‘ اور تُو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا سن لی اور اس کی بیماری کو دور کر دیا اور اسے اس کے اہل و عیال سے نوازا بلکہ ویسے ہی اور بھی دیے اپنی خاص مہربانی سے اور تاکہ نصیحت بن جائے تمام عبادت گزاروں کے لیے۔‘‘
اور سورئہ صٓمیں ارشاد فرمایا:
{وَاذْکُرْ عَبْدَنَآ اَیُّوْبَ م اِذْ نَادٰی رَبَّہٗٓ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الشَّیْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ(۴۱) اُرْکُضْ بِرِجْلِکَ ج ہٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ(۴۲) وَوَہَبْنَا لَہٗٓ اَہْلَہٗ وَمِثْلَہُمْ مَّعَہُمْ رَحْمَۃً مِّنَّا وَذِکْرٰی لِاُولِی الْاَلْبَابِ(۴۳)}
’’اوریاد کرو ہمارے بندے ایوب کو۔ جب اُس نے پکارا کہ مجھے شیطان نے اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے۔(اللہ تعالیٰ نے کہا:) اپنے پیر کو مارو (زمین پر)‘ یہ ایک ٹھنڈا پانی (ملے گا) نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ اور ہم نے اُسے اس کے اہل وعیال سے نوازا اور اتنے ہی اور دیے‘ ہماری طرف سے خاص مہربانی کے طور پر‘ اور عقل والوں کے لیےنصیحت کی خاطر !‘‘
دونوں سورتوں کے ان الفاظ کے فرق کو ملاحظہ کریں:
الانبیاء: رَحْمَۃً مِّنْ عِنْدِنَا سورئہ ص : رَحْمَۃً مِّنَّا
الانبیاء ذِکْرٰی لِلْعٰبِدِیْنَ سورئہ ص : ذِکْرٰی لِاُولِی الْاَلْبَابِ
تو اس فرق کی وجہ کیا ہے ؟
اس کا جواب یہ ہوگا ‘ واللہ اعلم‘ کہ سورۃالانبیاء میں ایوب علیہ السلام کا اندازِ دعا بڑا لطیفانہ ہے‘ وہ اپنی مصیبت کی شدّت کو بیان کیے بغیر صرف اتنا کہتے ہیں: ’’مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ ‘‘ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ازالہ بیماری کے لیے کسی سبب کے ذکر کیے بغیر دعا قبول کیے جانے کی نوید عطا کی:’’فَکَشَفْنَا مَا بِہٖ مِنْ ضُرٍّ‘‘اور سورئہ صٓ میں ایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت کی شدت کو یوں بیان کیا تھا:’’مَسَّنِیَ الشَّیْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ‘‘ (یعنی مصیبت کے سبب کو بیان کیا)تو اللہ تعالیٰ نے بھی مصیبت کی دُوری کے لیے ایک سبب اختیار کرنے کی تلقین کی اور فرمایا:’’اُرْکُضْ بِرِجْلِکَ‘‘یعنی اپنا پیر زمین پر رگڑ دیجیے اور پھر دیکھیے کہ جہاں پائوں مارا تھا وہیں ٹھنڈے پانی کا چشمہ نمودار ہو جائے گا تو اس کا پانی پیجیے اور اسی سے پانی سے نہائیے۔
چونکہ سورۃ الانبیاء کی آیت میں حضرت ایوب علیہ السلام نے صرف بیمار ی کے لاحق ہونے کا ذکر کیا تھا‘ اس کے سبب کا ذکر نہیں کیا تھا تو ’’مَسَّنِیَ الضُّرُّ‘‘ کے جواب میں فوراً ’’فَکَشَفْنَا مَا بِہٖ مِنْ ضُرٍّ ‘‘ کے الفاظ سے تسلی دی گئی اور اپنی رحمت کے خاص اپنے پاس سے آنے کو ’’رَحْمَۃً مِّنْ عِنْدِنَا‘‘ سے تعبیر کیاگیا۔ اور سورئہ صٓ میں یہی بات بیان کی گئی‘ لیکن صرف ’’رَحْمَۃً مِّنَّا‘‘ کہہ کر کہ اس میں وہ خصوصیت اور عنایت نہیں پائی گئی جو لفظ ’’مِنْ عِنْدِنَا‘‘ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ فرق اس لیے ہوا کہ پہلے صرف بیماری کا شکوہ تھا‘ بیماری کے سبب کا تذکرہ نہ تھا اور دوسری آیت میں بیماری کے ساتھ ساتھ اس کے سبب کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا۔
اسی فرق کی بنا پر سورۃ الانبیاء کے آخر میں ’’ذِکْرٰی لِلْعٰبِدِیْن‘‘ کہا گیا کہ عابد کا مقام بہت اعلیٰ ہے اور سورئہ صٓ کی آیت کے آخر میں ’’ذِکْرٰی لِاُولِی الْاَلْبَابِ‘‘ کہا گیا کہ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے‘ اور ان کا ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنا انہیں بالآخر ’’عابدین‘‘ کے مرتبے تک پہنچا دینے والا ہے۔ بہرصورت دونوں ہی اونچے مقامات ہیں لیکن اپنی اپنی جگہ پوری مناسبت رکھتے ہیں۔ واللہ اعلم!
اب رہی یہ بات کہ ہر دو سورت میں جو اندازِ بیان اختیار کیا گیا وہ اسی سورت کے مناسب تھا‘ تو وہ دونوں سورتوں میں وارد قصوں پر نظر ڈالنے سے واضح ہو جاتا ہے۔
سورۃ الانبیاء میں ایوب علیہ السلام کے قصے سے قبل حضرت ابراہیم ‘ حضرت نوح‘ حضرت دائود اور حضرت سلیمان علیہ السلام کےقصص بیان ہوئے ہیں۔ ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے:
{وَلَقَدْ اٰتَیْنَآ اِبْرٰہِیْمَ رُشْدَہٗ مِنْ قَبْلُ وَکُنَّا بِہٖ عٰلِمِیْنَ(۵۱) }
’’اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو سمجھ بوجھ عطا کی تھی اور ہم اس کے بارے میں خوب جانتے تھے۔‘‘
اور پھر مذکورہ انبیاء کے قصص کے بعد اس آیت پر اختتام ہوتا ہے:
{ وَکُنَّا لَہُمْ حٰفِظِیْنَ }
’’اور ہم ان سب کی حفاظت کرنے والے تھے۔‘‘
ان آیات میں ان انبیاء کے اعلیٰ مقامات کو واضح کیا گیا ہے۔ اور اسی مناسبت سے ایوب علیہ السلام کےقصے میں بھی اسی پہلو پر اقتصار کیا گیا ہے۔
سورئہ صٓمیں بھی یہ قصے بیان ہوئے ہیں‘ وہاں ملاحظہ ہو کہ دائود او رسلیمان علیہما السلام کے قصوں میں دونوں کی آزمائش کا ذکر ہے اور پھر دونوں کے مغفرت طلب کرنے کا تذکرہ ہے۔ دائود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:
{وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰہُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّہٗ وَخَرَّ رَاکِعًا وَّاَنَابَ(۲۴) فَغَفَرْنَا لَہٗ ذٰلِکَ ط }
’’اور دائودسمجھ گیا کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے تو اس نے اپنے رب سے مغفرت چاہی اور جھکتے ہوئے گر پڑا اور پوری طرح رجوع کیا ‘تو ہم نے اسے معاف کر دیا۔‘‘
اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا:
{وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیْمٰنَ وَاَلْقَیْنَا عَلٰی کُرْسِیِّہٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ (۳۴) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِیْ}
’’اور ہم نے سلیمان کو بھی آزمایا اور اس کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا‘ پھر اس نے رجوع کیا اور کہا :اے رب میری مغفرت فرما۔‘‘
اور اسی مناسبت سے جب ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا تو ان کے اپنے الفاظ میں شیطان کے ہاتھوں انہیں اذیت اور تکلیف پہنچائے جانے کا ذکر زبان پر آ گیا۔ گویا وہ بھی اس آزمائش کا ذکر کر رہے ہیں جس میں انہیں مبتلا کر دیا گیا تھا۔اس کے مقابلے میں جہاں دائود اور سلیمان علیہما السلام کا قصہ سورۃ الانبیاء میں بیان ہوا ہے ‘ وہاں پہلے اس فیصلے کا ذکر کیا گیا ہے جو ایک کھیت میں کسی کی بکریاں چرانےسے متعلق تھا اور آخر میں کہا گیا: { فَھَلْ اَنْتُمْ شٰکِرُوْنَ(۸۰) } ’’تو کیا تم شکر گزار نہ بنو گے؟‘‘اور پھر اسی مناسبت سے ایوب علیہ السلام کے قصے میں بھی اختصار اور ملاطفت کا لحاظ رکھا گیا۔
ایک دوسری بات دونوں سورتوں کی آیات کے آخری الفاظ (فواصل) سے بھی مناسبت رکھتی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اکثر آیات کا اختتام جمع سالم کے صیغے پر ہوتا ہے جیسے فاعلین‘ شاکرین‘ عالمین ‘ عابدین۔ اور سورئہ ص میں بروزن شراب‘ عذاب‘ اولوا الالباب کے الفاظ ہیں۔ اس لیے الفاظ کے انتخاب میں بھی اس اندازِ بیان کا خیال رکھا گیا ہے۔ واللہ اعلم!
(۲۵۵) آیت ۹۱
{وَالَّتِیْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَہَا فَنَفَخْنَا فِیْہَا مِنْ رُّوْحِنَا}
’’اور وہ خاتون جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا۔‘‘
اور سورۃ التحریم میں ارشاد فرمایا:
{وَمَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِیْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَھَا فَنَفَخْنَا فِیْہِ مِنْ رُّوْحِنَا} (آیت۱۲)
’’اور مریم عمران کی بیٹی جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا۔‘‘
دونوں جگہ حضرت مریمؑ کی مدح مقصود ہے اگرچہ سیاق و سباق مختلف ہے‘لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ دونوں جگہ ضمیر کااختلاف کیوں ہے؟ یعنی پہلی آیت میں ’’فَرْجَھَا‘‘ کے بعد ’’فَنَفَخْنَا فِیْہَا‘‘ (ضمیر مؤنث) لائی گئی اوردوسری آیت میں ’’فِیْہِ‘‘ (ضمیر مذکر) لائی گئی۔ اور دوسری یہ بات کہ اس انداز ِ بیان کا متعلقہ سورت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
پہلےسوال کا جواب تو یہ ہے‘ واللہ اعلم‘ کہ یہ بات تو طے ہے کہ دونوں جگہ مدح مقصود ہے‘ اور یہ کہ پہلی آیت میں ضمیر مؤنث ’’الَّتِیْٓ‘‘ کی طرف لوٹتی ہے‘ یعنی ہم نے روح اس خاتون میں پھونکی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی اور جس سے مرا د مریم بنت عمران ہیں جن کا سورۃ التحریم میں خصوصی طور پر نام بھی لیا گیا۔ یہاں ان کی ذاتِ گرامی کی تخصیص اور تکریم مقصود تھی‘ ان کی بھی اور ان کے بیٹے (عیسیٰ علیہ السلام ) کی بھی‘ جن کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ فرمایا:{وَجَعَلْنٰہَا وَابْنَہَآ اٰیَۃً لِّلْعٰلَمِیْنَ(۹۱)} ’’اورہم نے انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔‘‘
سورۃ التحریم میں ان کے بیٹے کا ذکر نہیں ہے‘ گویا یہاں کلام میں پھیلائو ہے جو کہ سورۃ التحریم میں نہیں ہے۔ اور اس مناسبت سے ان کی تکریم کے دائرے کو بھی پھیلا دیا گیا اور بتایا گیا کہ روح ان کی تمام ذاتِ مطہرہ میں پھونکی گئی۔چونکہ سورۃ التحریم میں کلام مختصر تھا اس لیے ’’فِیْہِ‘‘ کہہ کر صرف مقامِ مخصوص تک روح کے پھونکے جانے کا بیان ہوا اور سورۃ الانبیاء میں وسعت تھی تو اس روح کے پھونکے جانے کو تمام بدن سے عام کر دیا گیا۔
دونوں جگہ مدح کی گئی ہے لیکن سورۃ التحریم میں خاص طو رپر حضرت مریم علیہا السلام کی قوتِ ایمانی اور اطاعت گزاروں میں ان کی پہچان اور قدر و قیمت کا بیان ہے‘ ان کا اور آسیہ (امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ) کا بحیثیت مومنہ کے ایک مثالی کردار کو اُجاگر کیا گیا ہے اور اس ضمن میں ان کی ایک خصوصیت یعنی پاک دامنی کا ذکر بھی آ جاتا ہے‘ اور سورۃ الانبیاء میں حضرت مریم اور ان کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی تعظیم اور اکرام مقصود ہے کہ جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔اور پھر وہاں ایک ہی آیت میں تمام ضمائر کا ایک جیسا ہونا بھی سلاست ِبیان کا ایک حصہ ہے۔ ملاحظہ ہو: {الَّتِیْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَہَا فَنَفَخْنَا فِیْہَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰہَا وَابْنَہَآ}
دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ سورۃ الانبیاء میں سلسلہ وار کئی انبیاء و رسل علیہم السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہیں ‘پھر ان کے بیٹے اسحاق‘ان کے بیٹے یعقوب‘ پھر نوح ‘لوط‘ دائود‘ سلیمان‘ ایوب‘ اسماعیل ‘ ادریس‘ ذوالکفل‘ ذوالنون اور زکریا علیہم السلام کا تذکرہ ہے اور ان کے اعلیٰ مقامات اور اوصافِ حمیدہ کا ذکر ہے‘ اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہا السلام کا تذکرہ خاص مناسبت رکھتا ہے۔ اور جہاں تک سورۃ التحریم کا تعلق ہے تو یہاں دو اہم قضایا کا بتانا مقصود ہے کہ جن کا تعلق تقدیر الٰہی سے ہے‘ کون ایمان پر جیتا ہے‘ اور کون کفر پرمرتاہے۔
پہلے نوح اور لوط علیہما السلام کی بیویوں کا بیان ہوا کہ گو وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے دو مقرب بندوں سے زوجیت کا تعلق رکھتی تھیں لیکن یہ قربت انہیں اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہ دے سکی۔ پھر فرعون کی بیوی کا ذکر ہے کہ فرعون کا کفر اُس کا کچھ بگاڑ نہ سکا ۔اور پھرمریم علیہا السلام کا ذکر ہے کہ جو سعادت ان کے لیے مقدر ہو چکی تھی وہ ابتلاء و آزمائش کے باوجود ان کو حاصل ہو کر رہی۔ یہاں ان کے بیٹے کے ذکر کا کوئی موقع نہ تھا اس لیے ان کا ذکر نہیں کیاگیا۔ تو واضح ہو گیا کہ سورۃ الانبیاء میں جو کچھ بیان ہوا وہ سورت کے مضامین کے بالکل مطابق تھا اور ایسے ہی سورۃ التحریم کی آیات اس سورت کے مضمون کے مطابق تھیں۔
اضافات از مترجم
آیئے اب ذرا عراق کے عالم لغات القرآن ‘ ڈاکٹر فاضل صالح ساقرائی کے ملفوظات کی طرف جو ان دونوں آیات کے تدبر کے بعد انہوں نے اپنی کتاب (من اسرار البیان القرآنی) میں رقم فرمائے ہیں۔ ہم ان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں:
(۱) سورۃ الانبیاء میں حضرت مریم علیہا السلام کا ان کے نام کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا اور سورۃ التحریم میں ان کے بیٹے کا ذکر نہیں ہے‘ تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سورۃ الانبیاء میں آیت۵۱ سے ۹۰ تک چودہ انبیاء کا اُن کے ناموں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور پھر مریم ؑکا ان کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے وصف کے ساتھ (وَالَّتِیْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَہَا) ذکر کیا گیا ہے ‘اور شاید اس لیے کہ وہ انبیاء کی صف میں شامل نہیں۔ اور پھر ان کے بیٹے کا بھی (وَجَعَلْنٰہَا وَابْنَہَآ اٰیَۃً لِّلْعٰلَمِیْنَ) کہہ کر ذکر کر دیا گیا۔ اور سورۃ التحریم کاسیاق و سباق تو عورتوں سے متعلق ہے۔ سورت کا آغاز ہی نبیﷺ کی زوجات کے ذکر سے ہوتا ہے۔ فرمایا:
{یٰٓـاَیـُّھَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللہُ لَکَ ج تَـبْتَغِیْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِکَ ط} (آیت۱)
’’اے نبی(ﷺ)! جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اسے حرام کیوں قرار دیتے ہو؟ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو؟‘‘
اور پھر سورت کے اختتام پر چار خواتین کا ذکرہے‘ نوح اور لوط علیہما السلام کی بیویوں کا جو کافروں میں سے تھیں اور پھر فرعون کی بیوی کا اور مریم بنت عمران کا جو مؤمنات میں سے تھیں‘ تو یہاں ان کے نام کی صراحت کی گئی۔اور یہ بات بھی ملاحظہ ہو کہ جب کسی کی مدح یا مذمت مقصود ہواور نام کے ساتھ کی جائے تو زیادہ بلیغ شمار ہوتی ہے اور ان چار خواتین میں ان کا سب سے اعلیٰ مقام تھا‘ اس لیے صرف ان کے نام کی صراحت کی گئی ۔ سورۃ الانبیاء میں وہ تمام انبیاء کے مقابلے میں ان کے مرتبہ و منزلت سے کم تھیں اس لیے ان کے نام کی صراحت نہیں کی گئی۔
(۲) سورۃ الانبیاء میں قولِ باری تعالیٰ ’’فَنَفَخْنَا فِیْہَا مِنْ رُّوْحِنَا‘‘ عموم کا تقاضا کرتا ہے‘ یعنی یہ نفخ ان کی ساری شخصیت میں ہوا بمقابلہ آیت سورۃ التحریم (فَنَفَخْنَا فِیْہِ) کہ وہاں نفخ مقامِ مخصوص کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بھی ملاحظہ ہو کہ پہلی آیت میں مدح کا پہلو غالب ہے کہ وہ ساری شخصیت پر حاوی ہے اور دوسری آیت میں وہ ایک جزو کا احاطہ کرتا ہے۔
عموم اور خصوص کے اعتبار سے ایک دوسرا پہلوبھی ملاحظہ ہو۔سورۃ التحریم کی آیت میں چونکہ وصف کے ساتھ نام بھی ہے (جسے عربی گرامر میں عَلَم کہا جاتا ہے) اس لیے وہ ایک خاص شخصیت کے ساتھ خاص ہو گیا۔اور سورۃ الانبیاء کی آیت میں صرف وصف بیان ہوا ہے (وَالَّتِیْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَہَا) یہ وصف عموم کے حکم میں ہے ۔گو یہاں اس سے صرف حضرت مریمعلیہا السلام مراد ہیں‘ لیکن یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ وہ ان عورتوں میں سے ایک عورت ہیں جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور یوں اس میں عموم پیدا ہو گیا۔ اس لحاظ سے عموم کے ساتھ ’’فِیْہَا‘‘ کہہ کر عمومِ شخصیت کا اظہار ہو گیا اور جہاں خصوصی طور پر نام لیا گیا تھا وہاں ’’فِیْہِ‘‘ کہہ کر خصوصیت کا اظہارکر دیا گیا۔یہ بھی ملاحظہ ہو کہ سورۃ الانبیاء میں چونکہ مریم علیہا السلام کے ساتھ ان کے بیٹے کا بھی ذکر ہے‘ اس لیے بمقابلہ آیت سورۃ التحریم میں اس میں زیادہ عمومیت پائی جاتی ہے کہ وہاں صرف حضرت مریمؑ کا ذکر ہے‘ بیٹے کا ذکر نہیں ہے۔
(۳) سورۃ الانبیاء میں باعتبار عمومیت حضرت مریم علیہا السلام کی مدح بمقابلہ آیت سورۃ التحریم زیادہ بلیغ ہے ‘ اس لیے کہ ان کا ذکر انبیاء کے ساتھ کیا گیا ہے ۔پھر یہ کہنا کہ انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنایا گیا‘ مدح کے اعتبار سے زیادہ عالی مقام رکھتا ہے بہ نسبت سورۃ التحریم کے اس وصف کے جو حضرت مریم علیہا السلام کے بارے میں بیان ہوا: {وَصَدَّقَتْ بِکَلِمٰتِ رَبِّھَا وَکُتُبِہٖ وَکَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِیْنَ(۱۲)} یعنی انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور ان کی کتابوں کی بھی‘ اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھیں۔
دونوں آیات میں ان کی مدح بیان کی گئی ہے لیکن ظاہر ہے کہ انہیں اور ان کے بیٹے کو تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنایا جانا‘ اس مقام سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہے جو سورۃ التحریم میں بیان ہوا ‘ اس لیے کہ اللہ کی کتابوں اور کلمات کی تصدیق کرنے والے مَردوں اور عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے برخلاف ان کے جنہیں تمام جہانوں میں نشانی کی فضیلت دی گئی۔
(۴) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورۃ الانبیاء میں کیا گیالیکن سورۃ التحریم میں نہیں؟تو اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سورۃ الانبیاء میں نبیوں کا خصوصی ذکر ہے تو اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں ذکر مناسب تھا اور سورۃ التحریم میں عورتوں کا ذکر تھا تو ان کا ذکر مناسب نہ تھا۔
یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بیٹے بلکہ پوتے تک کا ذکر ہے : {وَوَہَبْنَا لَہٗٓ اِسْحٰقَ ط وَیَعْقُوْبَ نَافِلَۃًط } (آیت۷۲)’’اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور اس پر مزید یعقوب بھی۔‘‘ تو اس لحاظ سے مریم علیہا السلام کے ساتھ ان کے بیٹے کا ذکر بھی آ گیا۔
(۵) ایک ضمنی بات بھی ملاحظہ ہو کہ مریم علیہا السلام کے بارے میں جو نفخ کیا گیا اُسے دونوں آیات میں ضمیر جمع کے ساتھ بیان کیا گیا{فَنَفَخْنَا فِیْہَا}لیکن جہاں آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو وہاں ضمیر مفرد استعمال کی گئی: {وَنَفَخْتُ فِیْہِ مِنْ رُّوْحِی } (ص:۷۲)’’اور مَیں نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔‘‘اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:{ ثُمَّ سَوّٰىہُ وَنَفَخَ فِیْہِ مِنْ رُّوْحِہٖ } (السجدۃ:۹) ’’پھر اسے تراشا خراشا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔‘‘ اس لیے کہ جہاں فرشتوں کا عمل دخل ہو وہاں اللہ تعالیٰ ضمیر جمع سے خطاب کرتے ہیں اور سورئہ مریم میں اس بات کی صراحت کر دی گئی ہے کہ مریم علیہا السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا جس نے نفخ کیا تھا :
{ فَاَرْسَلْنَآ اِلَیْہَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَہَا بَشَرًاسَوِیًّا(۱۷)} (مریم)
’’تو ہم نے اس کے پاس اپنی روح (جبرائیل علیہ السلام ) کو بھیجا‘ پس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔‘‘
اور ایسا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا تھا‘ اسی لیے وہاں ’’نفخ‘‘ کے ساتھ دونوں آیات میں ضمیر مفرد (نفَخْتُ، نَفَخَ) لائی گئی۔ واللہ اعلم!
(۲۵۶) آیت ۹۲۔۹۳
{اِنَّ ہٰذِہٖٓ اُمَّتُکُمْ اُمَّۃً وَّاحِدَۃً ز وَّاَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوْنِ(۹۲) وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَہُمْ بَیْنَہُمْ ط کُلٌّ اِلَیْنَا رٰجِعُوْنَ(۹۳)}
’’بے شک یہ تمہاری اُمّت‘ اُمّت ِواحدہ ہے‘ اور مَیں تمہارا ربّ ہوں تو میری عبادت کرو! اور پھر لوگوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈال دی اور ہر ایک ہماری طرف لوٹنے والا ہے۔‘‘
اور سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرمایا:
{وَاِنَّ ہٰذِہٖٓ اُمَّتُکُمْ اُمَّۃً وَّاحِدَۃً وَّاَنَا رَبُّکُمْ فَاتَّقُوْنِ(۵۲) فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَہُمْ بَیْنَہُمْ زُبُرًاط کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْہِمْ فَرِحُوْنَ(۵۳)}
’’اور بے شک یہ تمہاری اُمّت‘ اُمّت ِواحدہ ہے اور مَیں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرتے رہو! تو وہ لوگ اپنے اس دین میں فرقوں میںبٹ گئے‘ اور ہر فرقہ اپنے کیے پر اِترا رہا ہے۔‘‘
یہاں دونوں سورتوں میں چار جگہ عبارت کا اختلاف واقع ہوا ہے :
سورۃ الانبیاء
سورۃ المؤمنون
(۱)
فَاعْبُدُونِ
فَاتَّقُوْنِ
(۲)
وَتَقَطَّعُوْا
فَتَقَطَّعُوْا
(۳)
...........
زُبُرًا
(۴)
کُلٌّ اِلَیْنَا رٰجِعُوْنَ
کُلُّ حِزْبٍم بِمَا لَدَیْھِمْ فَرِحُوْنَ
تو ایسا کیوں ہے؟
جواباً تمہید کے طور پر عرض ہے کہ اُمّت سے مراد یہاں ملّت ہے‘ اور ’’ھٰذِہٖ‘‘ سے یہاں ملّت ِاسلامیہ کی طرف اشارہ ہے۔زمخشری لکھتے ہیں:
’’ تمہاری ملّت‘ ملّت ِاسلامیہ ہے جس پر تمہیں قائم رہنا چاہیے اور اس سے سر ِمو انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک متحدہ ملّت ہے جس میں اختلاف نہیں ہےاور میں تمہارا رب ہوں اور تم سب کو میری ہی عبادت کرنی چاہیے۔اصل میں تو مراد خطاب ہے یعنی ’’تَقَطَّعْتُمْ‘‘ (تم لوگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے) لیکن یہاں غائب کاصیغہ استعمال کیا گیا جس سے مراد انہیں تنبیہہ کرنا ہے کہ دیکھو وہ کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ذرا دیکھو کہ انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ کیا کھلواڑ کر دیا تھا۔ اپنے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا بالکل ایسے جیسے ایک جماعت ہو جو اپنے اثاثوں کو تقسیم کر ڈالے اور ہر فرقہ اپنے اپنے حصے کو لے کر مصروف ہو جائے اور پھر سرپھٹول کی سی کیفیت واقع ہو جائے۔ پھر یاد رکھو کہ یہ سارے فرقے ایک دن اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں‘ اور پھر وہ ان کا محاسبہ بھی کرے گا اور انہیں بدلہ بھی دے گا۔‘‘ (الکشاف۲:۳۳۶۔۳۳۷)
اب ہم اصل جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ۔پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ساری سورۃ الانبیاءمیں شروع سے آخر تک کہیں بھی لفظ ’’تقویٰ‘‘ وارد نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس آیت سے ’’عبادت‘‘ کا حکم دینا شروع کیا ہے۔ فرمایا:
{وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِیْٓ اِلَیْہِ اَنَّہٗ لَآ اِلٰہَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ(۲۵) }
’’اور ہم نے تم سے قبل کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف ہم نے یہ وحی کی ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے تو پھر میری ہی عبادت کرو۔‘‘
اور سورۃ المؤمنون میں تقویٰ کا ذکر تین جگہ آیا ہے :
(۱) {وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰی قَوْمِہٖ فَقَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللہَ مَا لَـکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرُہٗ ط اَفَلَا تَتَّقُوْنَ(۲۳)}
’’اور ہم نے نوحؑ کو اُس کی قوم کی طرف بھیجا اور اُس نے کہا: اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو‘ تمہارے لیے سوائے اُس کے اور کوئی معبود نہیں‘ تو کیا تم نہ ڈرو گے؟‘‘
(۲) نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے رسول کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:
{فَاَرْسَلْنَا فِیْہِمْ رَسُوْلًا مِّنْہُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللہَ مَالَـکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرُہٗ ط اَفَلَا تَتَّقُوْنَ(۳۲)}
’’ پھر ہم نے اُن کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو ‘ تمہارے لیے سوائے اس کے اور کوئی معبود نہیں۔ کیا تم نہیں ڈرتے؟‘‘
(۳) {قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ(۸۷)}’’کہہ دیجیے کہ کیا پھرتم نہیں ڈرتے!‘‘
تو پہلی سورت میں اس لفظ کی رعایت کی گئی جو شروع میں آ چکا تھا اور دوسری سورت میں اس لفظ کی جو اس میں دہرایا جا رہا تھا۔
یہ بھی ملاحظہ ہو کہ عبادت کا حکم اس لیےدیا گیا کہ تقویٰ حاصل ہو‘ تو اس کا ذکر بطور سبب پہلے آنا چاہیے اور مسبّب کا بعد میں۔ سورۃ البقرۃ کے شروع ہی میں ارشاد فرما دیا تھا:
{یٰٓـاَیـُّھَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّــکُمُ الَّذِیْ خَلَـقَـکُمْ وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّــکُمْ تَـتَّقُوْنَ(۲۱)}
’’اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیداکیا اور ان کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرسکو۔‘‘
اور یہی انبیاء کی دعوت رہی ہے جس کا ذکر سورۃ المؤمنون میں ہے:
{وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰی قَوْمِہٖ فَقَالَ یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللہَ مَا لَـکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرُہٗ ط اَفَلَا تَتَّقُوْنَ(۲۳)}
دعوتِ عبادت تاکہ لوگ متقی بن سکیں (اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں) ۔دعوتِ عبادت پہلے اور تقویٰ کا حصول اس کے نتیجے میں‘اس لیے سورۃ الانبیاء میں ذکر ’’فَاعْبُدُوْنِ‘‘ اور سورۃ المؤمنون میں ’’فَاتَّقُوْنِ‘‘۔ یہاں بھی ترتیب کا خیال رکھا گیا۔ سورۃ الانبیاء پہلےہے اور سورۃ المؤمنون بعد میں ہے۔
پھر ایک اور پہلو سے ملاحظہ ہو کہ دونوں سورتوں میں انبیاء کے قصص کا بیان ہوا ہے لیکن سورۃ الانبیاء جس میں بیس کے قریب انبیاء کا بیان ہوا ہے ۔(مذکورہ آیت {اِنَّ ہٰذِہٖٓ اُمَّتُکُمْ .....} سے قبل ۱۷ انبیاء کا ذکر ہے اور پھر {وَمَآ اَرْسَلْنٰکَ اِلَّا رَحْمَۃً لِّلْعٰلَمِیْنَ(۱۰۷)} میں اللہ کے آخری رسولﷺ کا تذکرہ ہے ۔ تو یہ کل ۱۸ نبی اوررسول ہوئے۔)وہاں زیادہ تر ان عنایات کا بیان ہوا ہے جو انہیں حاصل رہی ہیں اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے دشمنوں سے نجات دی اور اپنی تائید و نصرت سے نوازا۔ ان کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکرپر ختم ہوتا ہے کہ جس کے بعد مذکورہ آیت لائی گئی ہے‘ اور ان انبیاء کے ذکر میں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا‘ لطف و انس اور الطافِ ربانیہ کا بیان ہے جو انبیاء کو حاصل رہا‘ جو کہ اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ مخلوق ہیں۔ رہی یہ بات کہ ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا تو اس کا بہت کم ذکر آیا بلکہ نہ ہونے کے برابر‘ اور اس لحاظ سے سورۃ الانبیاء میں ’’فَاعْبُدُوْنِ‘‘ کا لانا بڑا معنی خیز ہے کہ اس میں ’’فَاتَّقُوْنِ‘‘ والی وارننگ یا تنبیہہ کو شامل نہیں رکھا گیا۔
سورۃ المؤمنون میں یہ دوسرا پہلو غالب ہے کہ جو سورۃ الانبیاء کا محورِ بیان نہیں رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ انبیاء کی دعوت کے جواب میں ان کی قوموں نے کیسے انہیں جھٹلایا اور انہیں کیسے کیسے قبیح خطابات سے نوازا۔ نوح علیہ السلام کی مثال ہی لے لیجیے‘ دعوتِ نوح کے جواب میں ان کی قوم نے کیاکہا‘ ملاحظہ فرمایئے:
{مَا ہٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ لا یُرِیْدُ اَنْ یَّتَفَضَّلَ عَلَیْکُمْ ط وَلَوْ شَآئَ اللہُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِکَۃًج مَّا سَمِعْنَا بِہٰذَا فِیْٓ اٰبَآئِنَا الْاَوَّلِیْنَ(۲۴)}
’’یہ تم جیسا ایک انسان ہی تو ہے ‘تم پر اپنی فضیلت اور بڑائی چاہتا ہے ۔اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار سکتا تھا‘ ہم نے تو اپنے باپ دادوں میں بھی ایسی باتوں کو نہیں سنا۔‘‘
{اِنْ ہُوَ اِلَّا رَجُلٌ بِہٖ جِنَّۃٌ فَتَرَبَّصُوْا بِہٖ حَتّٰی حِیْنٍ(۲۵)}
’’یہ تو وہ شخص ہے کہ جسے جنون ہے تو اسے ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دو‘‘
پھر جو لوگ نوح علیہ السلام کے بعد میںآئے ‘انہوں نے اپنے نبی کو کیا جواب دیا ‘ وہ بھی ملاحظہ ہو:
{مَا ہٰذَآ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ یَاْکُلُ مِمَّا تَاْکُلُوْنَ مِنْہُ وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ(۳۳)}
’’یہ شخص تم جیسا ایک انسان ہی تو ہے‘ وہی کھاتا ہے کہ جس سے تم کھاتے ہو ‘ وہی (پانی) پیتاہے کہ جس سے تم پیتے ہو۔‘‘
اور پھر ان کی بہتان تراشیوں کا مزید بیان ہے‘ یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا:
{اِنْ ہُوَ اِلَّا رَجُلُنِ افْتَرٰی عَلَی اللہِ کَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَہٗ بِمُؤْمِنِیْنَ(۳۸)}
’’یہ تو وہ شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔‘‘
اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بعد مزید رسول بھیجنے کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ کیسے ان کی قومیں انہیں جھٹلاتی رہیں۔ فرمایا:
{کُلَّمَا جَآئَ اُمَّۃً رَّسُوْلُہَاکَذَّبُوْہُ فَاَتْبَعْنَا بَعْضَہُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنٰہُمْ اَحَادِیْثَ ج فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّایُؤْمِنُوْنَ(۴۴)}
’’اور جب کبھی ایک اُمّت کے پاس ان کا رسول آیا‘ انہوں نے اسے جھٹلایا‘ تو ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا۔ تو پھر دوری ہو ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔‘‘
اور اس کے بعدقومِ موسیٰ ؑ کے بارے میں ارشاد فرمایا:
{فَاسْتَکْبَرُوْا وَکَانُوْا قَوْمًا عَالِیْنَ(۴۶)}
’’پھر انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے۔‘‘
اس لحا ظ سے بالکل مناسب تھا کہ اب آخر میں کہا جاتا: فَاتَّقُوْنِ: ’’تو پھر مجھ سے ڈرتے رہو۔‘‘(یا اللہ کے عذاب سے بچو)۔ بالکل ایسے ہی جیسے سورۃ الانبیاء میں سیاق و سباق کی مناسبت سے کہا گیا تھا: فَاعْبُدُوْنِ ’’تو پھر میری عبادت کرو۔‘‘چنانچہ ان دونوں الفاظ کا اپنی اپنی سورت ہی میں آنا مناسب تھا‘ اور اگر اس کا الٹ ہوتا تو بالکل غیر مناسب ہوتا۔
دوسرا سوال کہ سورۃ الانبیاء میں ’’وَتَقَطَّعُوْا‘‘ فرمایا تھا اور سورۃ المؤمنون میں فاء تعقیب کے ساتھ ’’فَتَقَطَّعُوْا‘‘ کہا گیا تو اس کا جواب دونوں سورتوں کے مضمون میں پنہاں ہے۔
سورۃ الانبیاء کے آغاز ہی میں نبیﷺ کی اُنسیت اور دلبستگی کے لیے بیان ہوا:
{وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَکَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِیْٓ اِلَیْہِمْ}
’’اور ہم نے آپؐ سے قبل نہیں بھیجے مگر آدمی کہ جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔‘‘
اور اس کے بعد کہا:
{فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ(۷) }
’’تو پھر اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو (یعنی وہ انسان تھے یا نہیں؟)‘‘
پھر ان کی بشریت کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:
{وَمَا جَعَلْنٰہُمْ جَسَدًا لَّا یَاْکُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا کَانُوْا خٰلِدِیْنَ(۸) }
’’اورہم نے ان کے لیے ایسے جسم نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔‘‘
اس کے بعد رسولوں کی مدد کے ضمن میں ارشاد فرمایا:
{ثُمَّ صَدَقْنٰہُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَیْنٰـہُمْ وَمَنْ نَّشَآئُ وَاَہْلَکْنَا الْمُسْرِفِیْنَ(۹)}
’’پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچ کر دکھائے اور انہیں اور جن کو ہم نے چاہا‘ نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا۔‘‘
یہ کہنا کہ ’’ پھر تم پوچھ لو‘‘ ایک اندازِ تلطف ہے جو اس سورت کا خاصہ ہے اور یہی انداز ان تمام انبیاء کے قصوں میں بھی جھلک رہا ہے جو اس سورت میں مذکور ہوئے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و عنایت ہمیشہ ان کے ساتھ رہا۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ہم آیت ۲۵ اور ۲۶ کو پیش کرتے ہیں‘ فرمایا:
{وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِیْٓ اِلَیْہِ اَنَّہٗ لَآ اِلٰہَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ(۲۵) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا}
’’اور ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی کی کہ سوائے میرے اور کوئی معبود نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رحمٰن کی تو اولاد ہے۔‘‘
اس سے ملتی جلتی آیت سورۃ الرعد کی ہے:
{کَذٰلِکَ اَرْسَلْنٰکَ فِیْٓ اُمَّۃٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِہَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا عَلَیْہِمُ الَّذِیْٓ اَوْحَیْنَآ اِلَیْکَ وَہُمْ یَکْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ط } (آیت۳۰)
’’اور اس طرح ہم نے آپ کو اس اُمّت میں بھیجا ہے کہ جس سے پہلے بہت سی اُمتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ ان پر جو وحی ہم نے اتاری ہے پڑھ کر سنائیں‘ اور وہ رحمان کا انکار کر تے ہیں۔‘‘
گویا نبیﷺ کی دل بستگی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پرواہ نہ کریں اگر یہ رحمٰن کا انکار کرتے ہیں‘بلکہ انہیں وحی سناتے رہیں۔ سورۃ الانبیاء میں بھی یہی اسلوب تھا کہ گو لوگ یہ کہتے رہے کہ رحمٰن نے تو اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے لیکن ہم نے ہر رسول کو یہی ہدایت کر رکھی تھی کہ تم توحید باری تعالیٰ کا بیان کرتے رہو۔ اب ذرا آیت زیر بحث کو ایک دفعہ پھر ذہن میں لایئے:{ وَاَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوْنِ(۹۲) وَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَہُمْ بَیْنَہُمْ ط} (الانبیاء) ’’اورمیں تمہارا ربّ ہوں تو میری عبادت کرو ۔مگر لوگوں نے آپس میں دین کے بارے میں کانٹ چھانٹ کر کے رکھ دی۔‘‘
گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تو انہیں پچھلی قوموں کےانجام سے بھی آگاہ کیا تھا‘ یہ بھی کہا تھاکہ اگر کوئی شک و شبہ ہے تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔اور یہ بھی بتادیا تھا کہ جو انبیاء کے راستے پر چلے گا وہ نجات پائے گا ‘لیکن ان تمام تنبیہات کے باوجود یہ لوگ اپنے عناد پر قائم رہے اور فرقوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے۔ یہاں تعجب کا اظہار ہے‘ وعید (دھمکی) کی شدّت نہیں ہے تاکہ نبیﷺ کو اُمید باقی رہے کہ شاید یہ لوگ راہِ راست پرآجائیں۔یعنی ان کی تفرقہ بازی کی طرف اشارہ تو کیا گیا لیکن امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے کا اشارہ بھی دیا گیا ۔ اسی لیے یہاں ان کے کفر و عناد کا شدّت سے ذکر نہیں کیا گیا اور نہ ہی سورۃ المؤمنون کی طرح تخویف اور تہدید (ڈرانے اور دھمکانے) کا انداز اپنایا گیا۔ وہاں تو ان کے بارے میں کہا گیا تھا:
{ کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْہِمْ فَرِحُوْنَ(۵۳)}(المؤمنون)
’’ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے‘ اس پر اِترا رہا ہے۔‘‘
اور اگلی آیات میں کہا گیاتو پھر انہیں کچھ دیر غفلت ہی میں پڑا رہنے دو‘ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں‘ وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں۔ ’’بَلْ لَّا یَشْعُرُوْنَ‘‘ (بلکہ یہ لوگ تو سمجھتے ہی نہیں۔)
یہاں تک تو سورۃ الانبیاء میں وارد آیت کا بیان ہوگیا‘ اب سورۃ المؤمنون کی آیت کی طرف آیئے جہاں فاء تعقیب کے ساتھ ’’فَتَقَطَّعُوْا‘‘ کہاگیا ہے۔سورۃ المؤمنون کی آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے سورۃ النحل کی اس آیت پر غور کریں:
{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِیْ کُلِّ اُمَّۃٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللہَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج فَمِنْہُمْ مَّنْ ہَدَی اللہُ وَمِنْہُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَیْہِ الضَّلٰلَۃُط} (آیت۳۶)
’’اور ہم نے ہر ایک اُمّت میں ایک رسول کو بھیجا کہ (لوگو) اللہ کی عبادت کرو اور اُس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ تو ان میں بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔‘‘
یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رسولوں نے تو اپنی قوموں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا‘ معبودانِ باطل سے بچنے کی تاکید بھی کی ‘البتہ بعض لوگوں کو تو ہدایت ہوئی لیکن بعض دوسرے بجائے ہدایت حاصل کرنے کے گمراہی کے عمیق گڑھوں میں گرتے چلے گئے۔
اب آیئے سورۃ المؤمنون کی طرف جہاں ایک نہیں کئی رسولوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم نے پچھلے لوگوں کے حالات سنے۔ یہ بھی جان لیا کہ جن لوگوں نےانکار کیا تھا ان کا کیا حال ہوا ۔ تمہیں تو بزبانِ رسل یہ بھی کہا گیا تھا کہ:
{کُلُوْا مِنَ الطَّیِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًاط } (آیت۵۱)
’’پاکیزہ چیزوں میں سے کھائو اور نیک اعمال کرو۔‘‘
تم سب ایک ملت تھے‘ تمہیں کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا جو تمہاری استطاعت سے باہر ہو ‘لیکن تم نے ایک نہ مانی بلکہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے۔اندازِ بیان میں فرق صرف اتنا ہے کہ مخاطب کے صیغے (تَقَطَّعْتُمْ) کے بجائے غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا یعنی فَتَقَطَّعُوْا اَمْرَھُمْ کہا گیا۔
اس طرزِ خطاب کو ’’التفات‘‘ کا نام دیا جاتا ہے یعنی مخاطب کی بے قدری کو ظاہر کرنے کے لیے بجائے صیغہ خطاب کے یوں بات کی جائے جیسے وہ غیر حاضر ہو۔یہ التفات (یعنی توجہ دوسری طرف کرنا) کسی دوسری مصلحت کے لیے بھی ہو سکتا ہے ۔ یعنی انہیں قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا گیا لیکن ان پر جوں تک نہ رینگی‘ وہ بجائے ملّت ِواحدہ کے فرقوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے۔ یہاں خطاب کی شدت اور تندی اپنے عروج پر ہے اور فاءِ تعقیب لا کر ایسے لوگوں کے فعل پر نکیر کی گئی ہے جنہیں ہر قسم کی ترغیب بھی دلائی گئی تھی اور ہر طرح سے ڈرایا بھی گیا تھا لیکن انہوں نے اس کے جواب میں گمراہی اور تفریق کا راستہ اختیار کیا۔اس لحاظ سے ہر دو سورتوں میں جو الفاظ اور حروف آئے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پوری مناسبت رکھتے ہیں اور اگر اس کا عکس کیا جاتا تو قطعاً غیر مناسب ہوتا‘ واللہ اعلم!
تیسرے سوال یعنی سورۃ المؤمنون میں ’’زُبُرًا‘‘ کا اضافہ کیوں کیا گیا ؟تو اس کا جواب ہماری پچھلی گفتگو میں آ چکا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ سورۃ الانبیاء میں کئی انبیاء اور رسولوں کے قصے بیان ہوئے جن میں ان کی دعائوں کے قبول ہونے اور دشمنانِ دین سے چھٹکارا دلائے جانے کا ذکر تھا اوراس لحاظ سے نبیﷺ کی دلبستگی اور تالیف قلب کا اہتمام کیا گیا تھا‘ اور یہی اسلوب سورئہ مریم اور سورئہ طٰہ میں بھی اختیار کیا گیا تھا۔ سورۃ الانعام کی آیت {اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ ہَدَی اللہُ فَبِہُدٰىہُمُ اقْتَدِہْ ط }(آیت۹۰) کے مطابق ان سب کے راستے سے رہنمائی حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ اس لحاظ سے وہاں یہ مناسب نہ تھا کہ مخالفین کے انتشار اور افتراق کا شدت سے ذکر کیا جاتا برخلاف سورۃ المؤمنون کے‘ جس میں پچھلی اُمتوں کی تکذیب اور عداوت کا بار بار ذکر کیا گیا‘ ان کے انجامِ بد کی خبر دی گئی ‘تو مناسب تھا کہ ان کے ٹکڑوں میں بٹ جانے کا ذکر شدت سے کیا جاتا اور اس لحاظ سے ’’زُبُرًا‘‘ کا اضافہ بالکل مناسب تھا۔
چوتھے سوال یعنی دونوں سورتوں کی مذکورہ آیات کا آخری حصہ مختلف ہے۔ سورۃ الانبیاء میں کہا گیا : ’’کُلٌّ اِلَیْنَا رٰجِعُوْنَ‘‘ اور سورۃالمؤمنون میں کہا گیا : ’’کُلُّ حِزْبٍم بِمَا لَدَیْھِمْ فَرِحُوْنَ‘‘ تو اس کا جواب بھی ہمارے پچھلے کلام سے ربط رکھتا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں مذکورہ آیت سے متصل اگلی آیت یہ ہے :
{فَمَنْ یَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَہُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا کُفْرَانَ لِسَعْیِہٖ ج } (آیت۹۴)
’’اور جو شخص بھی حالت ِایمان میں نیک اعمال کرے گا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔‘‘
گویا سورت کے مجموعی مضمون کہ جس میں تأنیس اور تألیف کا پہلو غالب ہے‘اہل ایمان کے انجام کا حسن و خوبی کے ساتھ ذکر آ گیا‘ لیکن اس کے بالمقابل معاندین اسلام کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں آیا۔ ’’کُلٌّ اِلَیْنَا رٰجِعُوْنَ‘‘ میں اشارۃً یہ بات آ گئی کہ مؤمن کا تو اللہ کے پاس جانے کے بعد یہ حکم ہو گا توکافر کا کیا حکم ہو گا وہ خود سمجھ میں آ سکتا ہے ۔ اس کے بالمقابل سورۃ المؤمنون میں مذکورہ آیت کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا:
{فَذَرْہُمْ فِیْ غَمْرَتِہِمْ حَتّٰی حِیْنٍ(۵۴)}
’’تو پھر آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں کچھ مدت پڑا رہنے دیںـ۔‘‘
مزید یہ ارشاد فرمایا:
{ اَیَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّہُمْ بِہٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِیْنَ(۵۵) نُسَارِعُ لَہُمْ فِی الْخَیْرٰتِ ط بَلْ لَّا یَشْعُرُوْنَ(۵۶)}
’’کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں‘ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں۔(نہیں!) بلکہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں۔‘‘
تو واضح ہو گیا کہ ہر دو سورت کے آخر میں جو الفاظ آئے ہیں‘ وہ اس سورت کے موضوع سے مطابقت رکھنے کی وجہ سے بالکل مناسب تھے اور اگر اس کا اُلٹ کیا جاتا تو قطعاً غیر مناسب ہوتا‘ واللہ اعلم!