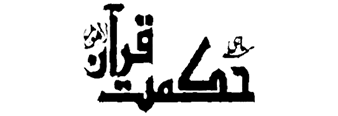(فکر و نظر) علامہ اقبال اور اسلامی جدت پسندی - ڈاکٹر محمد رشید ارشد
8 /علّامہ اقبال اور اسلامی جدّت پسندیڈاکٹر محمد رشید ارشد
ایک وقت تھا کہ اُمّت ِمسلمہ عروج پر تھی۔ان کے پاس طاقت تھی تو ان کے ہاںقدامت پسندی
(Orthodoxy) کاایک تصور پیدا ہوا‘اہل سُنّت والجماعت کا‘سوادِ اعظم کا‘اور اس نے خود سے یہ طے کیا کہ Orthodoxy کسے کہتے ہیں‘ آزاد خیالی) (Heterodoxy کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ عنوانات قائم کیے کہ یہ معتزلہ ہیں‘یہ خوارج ہیں‘یہ جبریہ ہیں‘یہ قدریہ ہیں‘یہ حشویہ ہیں۔لیکن اب چونکہ بہت عرصے سے اُمّت ِمسلمہ ہر پہلو سے زوال کا شکار ہے تو جن لوگوں کے پاس طاقت اور قوت ہے‘ جن کے ہاتھوں میں زمامِ کار ہے تو اب مسلمانوں کی شناخت مغربی اقوام یا یورپی اقوام ہی متعین کرتی ہیں ۔ مسلمانوں کو مختلف حصوں میں بانٹا جاتا ہے کہ یہ لبرل ہیں‘ یہ سیکولر ہیں‘ یہ جدت پسند ہیں‘ یہ روایت پسند(Traditional) ہیں‘ یہ اعتدال پسند (Conservative) ہیں۔ اسی طریقے سے یہ صوفی اسلام ہے‘ یہ سلفی اسلام ہے‘ یہ بنیادپرستی (Fundamentalism ) ہے۔
اسی حوالےسےاسلامی جدت پسندی (Islamic Modernism ) بھی ایک ترکیب (construct) ہے جو کچھ عرصے میں تیزی کے ساتھ نمایاں ہوئی ہے۔ مسلمان مفکرین میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ self-confessed modernist ہوں‘یعنی جو خود یہ پسند کریں کہ ہمیں modernist کہا جائے۔ یہ ترقی پسند اسلام (Progressive Islam ) کا ایک رجحان ہے۔ لوگ خود سے کہتے ہیں کہ ہم Progressive ہیں ۔ امریکہ اور دیگر ممالک میں اس کے بہت سے حامی ہیں‘ لیکن مسلمان مفکرین عام طو رپر اس لیبل کو پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب تو modernist ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ جیسے ان کو گالی دی جا رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گویا ایک ہتک آمیز (pejorative) اصطلاح ہے‘ جس کے ذریعے کسی کی اہمیت و قابلیت کو جانچا جا رہا ہے۔ یعنی کسی کو modernist کہنے سے آپ کی مراد یہ ہے کہ یہ لوگ بدنیت ہیں‘ جومغرب کی شرائط اور جدیدیت کے تقاضوں کے مطابق اسلام کو ڈھال رہے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ اسلامی جدت پسندی یا اسلامی جدیدیت کا سیاق استعماری (colonialistic ) یا سامراجی (imperialistic) ہے۔ یعنی یہ تصور اُس وقت اُبھرا جب ہمارے ہاں جب یورپی اقوام آ کر غالب ہو گئیں تو اب چونکہ ان کے پاس طاقت تھی(معروف لاطینی امریکن دانشورAnibal Quijano اس کے لیے Colonial Matrix of Power کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔) لہٰذاہماری شناخت اور پہچان کا کام بھی انہوں نے ہی کیا۔ مشہور فرانسیسی مفکر Ernest Renan نے Collège de France کے افتتاح کے موقع پر جو لیکچر دیا تھا‘ اس میں اسلام پر بہت سی باتیں کیں۔ جب یہ شائع ہوا تو سر سید احمد خان مرحوم نے اس کا جواب دیا۔جمال الدین افغانی کےہاں بھی اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی گئی۔اس لیکچر کے کچھ اقتباسات سے اندازہ ہو گا کہ Orientalism کا پورا بیانیہ (discourse)مسلمانوں یا اسلامی فکر کو کیسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں:
“Islam is the complete negation of Europe ... Islam is the disdain of science, the suppression of civil society;, it is the appalling simplicity of the Semitic spirit, restricting the human mind, closing it to all delicate ideas, to all refined sentiment, to all rational research, in order to keep it facing an eternal tautology: God is God.”
یہ ہے وہ judgment جو مسلمانوں کے متعلق دی جا رہی ہے۔ ایسی صورت حال میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ہمارے ساتھ کیا غلط ہوا! ایسا کیا ہوا کہ لوگ ہمارے بارے میں یہ سب باتیں کر رہے ہیں؟(اشارہ ہے برنارڈ لیوس کی کتاب ’’What Went Wrong??‘‘ کی طرف‘ جس کا شمار حال ہی میں شائع ہونے والی اہم کتابوں میں ہوتا ہے۔)
ہماری روایت میں ایک تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے اس بات سے کہ دشمن ہم پر تالی پیٹیں‘ہم پر ہنسیں‘
ہمارا مذاق اڑائیں۔ اب پھر اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوا‘مسلمان مفکرین پیدا ہوئے۔ غالب کامشہور شعر ہے کہ: ؎
ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند
گستاخیٔ فرشتہ ہماری جناب میںاور علّامہ اقبال نے ’’شکوہ‘‘ میں یہ سوال اٹھایا کہ: ؎
رحمتیں ہیں تری اغیار کے کاشانوں پر
برق گرتی ہے تو بے چارے مسلمانوں پراس پس منظر (context) میں اسلامی جدیدیت کا گویا آغاز ہوا۔چونکہ اب طاقت نہیں ہے‘ اختیار نہیں ہے تو legitimacy crisis بھی پیدا ہو گیا۔ یہ سوال اٹھا کہ : Who speaks for Islam??۔ اُمّت ِمسلمہ یا مسلمانوں کے بارے میں کون کلام کرے گا؟ اکبر الٰہ آبادی نے اس زمانے کی صورت حال کو تفنن کے انداز میں بیان کیا: ؎
گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ
گلے میں جو آئیں وہ تانیں اُڑاؤ
کہاں ایسی آزادیاں تھیں میسر
اناالحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ!اب میں چاہتا ہوں کہ جدیدیت کے اہم نکات کو چند جملوں میں عرض کر دوں‘ کیونکہ اسی کے حوالے سے پھر اسلامی جدیدیت پر بھی بات ہو گی۔ جدیدیت کا بنیادی تصور یہ ہے کہ ہر طرح کی ماورائیت (transcendence ) یا نیم مطلقیت (semi-transcendent ) اتھارٹی کا انکار کرنا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ سب کیا جاتا ہے تو خدا اور دین کی جو تاریخی‘سماجی‘اور قانونی حیثیت ہے‘اس کا انکار بھی لازم آتا ہے۔یہ جو ہدف ہے کہ ہر طرح کی برتری اور تقدیس (sacredness ) کا انکار کرنا‘ گویا اسی کے ذیل میں ہے کہ آخر کار ہر طرح کی الٰہیات اور مابعدالطبیعیات (metaphysics) کا انکار کرنا۔ جدیدیت یہ ہدف سیاسی طور پر جمہوریت کے ذریعے حاصل کرتی ہے اور سیکولرازم کو ریاستی پالیسی اور معاشرتی قدر کے طور پر سامنے لاتی ہے۔ جہاں پر چیزوں کو دیکھنے کا سیاسی تناظر درکار نہیں ہوتا وہاں ایک نظریاتی تناظر کام میں لایا جاتا ہے۔ وہ تناظر یہ ہے کہ جدید علم کا مزاج تجربی (empiricial) ہے۔ تجربیت (empiricism ) کانعرہ یہ تھا کہ seeing is believing۔
تجربیت یا اثباتیت میں علم کی شرط پہلے تصدیقیت( verifiability) بتائی گئی۔ پھر Karl Popper وغیرہ کے بعد کہا گیا کہ یہ ابطال(falsifiability)ہے۔ یعنی سائنس اور علم کی تعدیل (equate) کر دی گئی‘کہ وہی چیز علم کہلانے کے لائق ہے جو سائنسی طریقے پر پورا اترتی ہے اور جس کی شرط یہ ہے کہ اس کو verify کیا جا سکے یا falsify کیا جا سکے۔ اس صورت حال میں علّامہ اقبال کا کام بھی ہمارے سامنے آتا ہے اور اسلامی جدیدیت کے حوالے سے مختلف مغربی مفکرین نے بھی کام کیا ہے۔ اس ضمن میں Charles Kurzman نے دو مجموعے مرتب کیے۔ پہلا ۱۹۹۸ء میں Liberal Islam اور دو سرا ۲۰۰۲ء میںModernist Islam: A Source Book کےنام سے شائع ہوا۔
Modernist Islam میں اس نے ۱۸۴۰ء سے ۱۹۴۰ء تک‘ یعنی پوری ایک صدی میں جو مسلمان مفکرین سامنے آئے‘ان میں سے جو اس کے خیال کے مطابق جدیدیت کا رجحان رکھنے والے تھے‘ان کی نمائندہ تحریریں جمع کیں۔ان میں حالی ہیں‘چراغ علی ہیں‘سر سید ہیں‘علّامہ اقبال ہیں‘عبدالقادر مولوی (مالا بار کے صاحب ِعلم) ہیں‘ ابوالکلام آزاد ہیں‘ محمد اکرم خان (بنگال کے صاحب علم) ہیں۔اس نے بتایا کہ ان لوگوں نے کن موضوعات پر گفتگو کی اور ان کے ذریعے اسلامی جدت پسندی کا اظہار کس طرح ہوا۔ ان کے افکار میں تہذیبی احیاء(Cultural revival) ‘سیاسی سدھار (Political reform) ‘سائنس اور ایجوکیشن ‘ حقوق نسواں (Women's rights) وغیرہ جیسے بنیادی مضامین تھے۔ Charles Kurzman نے علّامہ اقبال کے حوالے سے بھی بتایا کہ وہ اسلامی جدّت پسندی کے ضمن میں کیا کیا خیالات رکھتے ہیں۔انہوں نے Liberal Islam پر جو تحریریں جمع کیں وہ ۱۹۲۰ء سے ۱۹۹۸ء تک کے مفکرین کی ہیں۔ اس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو جمع کیا ہے‘جن میں اکثرشریعت کی محدودیت کے قائل ہیں۔ چنانچہ ان کے خیال میں Silent Sharia یہ ہے کہ قرآن و سُنّت نے زندگی کے بہت سے پہلوئوں (facets) میں سے چند چیزوں کے بارے میں باتیں کی ہیں‘باقی کے بارے میں شریعت خاموش ہے‘اور اس ضمن میں گویا انسانی عقل پر چیزوں کو چھوڑا گیا ہے۔چنانچہ ہمیں خود سے فیصلہ کرنا ہے‘چیزوں کو دیکھنا ہے۔مزید برآں شریعت کی تعبیر (interpretation) ہمیںخود کرنی ہے۔ جدّت پسند اسلام ( Modernist Islam) میں ایک بہت اہم لفظ ہے: hermeneutics ۔ یہ اصولِ تفسیر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ متن (text )تو پرانا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ binding ہے۔بہت سے لوگوں نے حدیث و سنت کا انکار کر کے اس کے بارے میں اشکالات پیدا کیےلیکن بہرحال قرآن کو تو ماننا ہی پڑتا ہے۔ٹھیک ہے‘ ہم اس متن کو تو مانتے ہیں‘لیکن چونکہ context بدل رہا ہے تو ہمیں نئی نئی تعبیرات کرنی ہیں ۔ ہم اس کی نئے طریقے سے تشریح و توضیح کر یں گے۔
یہاں اکبر الٰہ آبادی کے چند اشعار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بہت پُرلطف اورکاٹ دار ہیں: ؎
کھل گیا مصحف رخسارِ بتانِ مغرب
ہو گئے شیخ بھی حاضر نئی تفسیر کے ساتھیعنی‘اب چونکہ ایک نیا عہد نامہ آ رہا ہے‘ایک نیا پروٹوکول آ رہا ہے‘تو اب شیخ بھی یہ کہتے ہوئے آ گئے کہ چلیں ٹھیک ہے‘ہماری کتاب کی سلف سے مختلف ایک نئی تفسیر ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مغرب میں جب کوئی سائنسی یا سماجی نظریہ منظر عام پر آتا ہے‘ تو لوگ ایک معذرت خواہانہ اور شکست خوردہ ذہنیت کے ساتھ قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں‘پھر بتاتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں تو ۱۴۰۰ سال پہلے یہ فکر موجود تھی۔ پھر ایک اور جگہ انہوں نے کہا: ؎
مری قرآن خوانی سے نہ ہوں یوں بدگماں حضرت
مجھے تفسیر بھی آتی ہے‘ اپنا مدّعا کہیے!کہ آپ جو چاہتے ہیں تفسیر کے ذریعے ہم یہ سب کر دیں گے۔ اکبر نے سر سید مرحوم پر یہ پھبتی بھی چست کی تھی کہ: ؎
دیکھ کاری گریٔ حضرتِ سیّد اے شیخ
دے گئے لوچ وہ مذہب کو کمانی کی طرحچونکہ متن کو تو بدلا نہیں جا سکتا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تفسیر کو بدل دیتے ہیں۔
Kurzman علّامہ اقبال کی شناخت ایک اسلامی جدت پسندکے طورپر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے Shireen Hunter کی ایک کتاب چھپی تھی:
Reformist Voices of Islam:Mediating Islam and Modernity
سوال وہی ہے کہ اب کیا کیا جائے ! اسلام ایک پرانا دین ہے اور اب جدیدیت آ گئی ہے۔ ایک سوال جو بہت سے لوگ اٹھاتے ہیں کہ زندگی تغیر کا شکار ہے۔ ساتویں صدی عیسوی میں عرب میں جو کچھ بھی نازل ہوا‘ اُس وقت جس طرح کے حالات تھے‘ وہاں کا تمدن تھا‘ اب اکیسویں صدی کے لیے وہ کیسے مؤثر ((valid ہو سکتا ہے! Shireen Hunter کی اس کتاب میں اُمّت ِمسلمہ کے مختلف خطوں کے لیے مختلف شخصیات نے ابواب لکھے ہیں۔ برصغیر کے حوالے سے مضمون ڈاکٹر رفعت حسن نے لکھا ہے۔ یہ پاکستانی نژاد امریکی پروفیسر ہیں۔ اب انہوں نے جو genealogy بنائی ہے اور جو نام لے کر آئی ہیں‘وہ بھی بہت چشم کشا ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علّامہ اقبال کو کس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ ان کے باب کا عنوان ہے :
Islamic Modernism and Reformist Discourse in South Asia
انہوں نے آغازسرسید سے کیا۔ پھر ان کے رفقاء کا ذکر کیا ہے جن میں مولوی چراغ علی‘محسن الملک اور سید ممتاز علی نمایاں ہیں‘ خاص طو رپر حقوقِ نسواں کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کے تناظر میں ۔ اس کے بعد خصوصاً اسی ضمن میں علّامہ محمد اقبال‘ڈاکٹر فضل الرحمٰن‘ ان کے شاگرد محمد خالد مسعود‘ پھر رفعت حسن نے خود اپنی پوزیشن کا ذکر کیا ہے۔پھر جاوید احمد غامدی‘بھارت سے اسد علی انجینئر‘ ایک سکھ یوگندر سنگھ سکند جو بعد میں مسلمان ہوئے‘ ان کا بیان ہے۔ یہاں پر بھی رفعت حسن صاحبہ نے علّامہ اقبال کو اسلامی جدت پسندی یا اصلاحی فکر (reformist thought) کی روشنی میں دیکھا ہے۔ اس کتاب کو تفصیل میں جا کر دیکھیں توان تمام مفکرین کے درمیان بھی ‘ خاص طور پر متن کی ترجمانی کا تذکرہ باربار آتا ہے‘ یعنی hermeneutics کا مسئلہ جگہ جگہ سامنے آ رہا ہے۔
اس جدت پسندی یا اسلامی جدیدیت کو روایتی طور پر کیسے دیکھا جائے ؟ہمارے دین میں ایک تصور تجدید کا ہےکہ اسلام چونکہ ابدی اور سرمدی ہے جبکہ دُنیا بدل رہی ہے‘حالات بدل رہے ہیں‘تو مظاہر قدرت میں سے ایک عمل کوتجدید کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے :
((إنَّ اللّٰهَ عزّ وجلّ يبعث لهذهِ الأُمَّةِ علٰی رأسِ كُلِّ مِائةِ سَنةٍ مَن يُجَدِّدُ لها دينَها ))(سنن ابی داوٗد:۴۲۹۱)
’’ اللہ تعالیٰ اس اُمّت کے لیے ہر سو سال کے کنارے پر ایسے افراد پیدا کرتے رہیں گے جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔‘‘
تجدید یہ ہے کہ چیزوں کوان کی اصل پر استوار کرنا۔ امتدادِ زمانہ سے چیزوں پر گرد پڑ جاتی ہےاور ان میں انحراف آ جاتا ہے‘deviations ہو جاتی ہیں۔ایک روایت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نسل میں ایسے عادل لوگ پیدا کرتے رہیں گے جو ((ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاھلین)) (البیھقی ۱۰ / ۲۰۹) یعنی وہ انتہا پسندوں کی تحریفات کو دور کریں گے ۔باطل پرست جو غلط نسبتیں دیں گے اور نئی چیزیں دین میں شامل کر دیں گے‘ان کی نفی کریں گے ۔ جاہل لوگ جو باطل قسم کی تشریحات اور تاویلات کریں گے‘ان کو صاف کریں گے۔ یہ عمل پسندیدہ ہے اور اس میں ایک فعالیت پائی جاتی ہے کہ اصل متن کو سامنے رکھیں۔ اسی کے حوالے سے ایک اہم چیز اجتہاد ہے‘ لیکن ایک دوسری چیز بھی ہے جو منفی ہے یعنی تجدد۔ اجتہاد ایک مثبت عمل ہے۔ اس کے ذریعے دین کا چہرہ مسخ کرنے والے منفی رجحانات جیسے بدعات‘ اختراعات اور زیادتیوں کا ردّ کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں تجدد ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسلامی جدت پسندی یا اسلامی جدیدیت کو لوگ تجدد کے تصوّر سے جوڑتے ہیں۔تجدد میں تکلف ہے اور اس میں گویا ایک طرح سے انفعالیت پائی جاتی ہے۔ اس میں خارجی عقائد کی طاقت کا تاثر ہے۔ Michael Foucault نے بھی یہ بات کہی ہے۔ ویسے بھی یہ ایک بدیہی حقیقت (truism) ہے کہ دنیا میں دو چیزیں درکار ہوتی ہیں: علم اور طاقت ( knowledge and power)۔ تجدد کے ہاں جو علم تخلیق ہوتا ہے وہ گویا طاقت کے زیر اثر ہوتا ہے۔ قوت اس کی راہ متعین کرتی ہے۔ یہ طبع زاد نہیں ہوتا بلکہ اس میں زمانے کے تقاضوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسی کے مطابق دین کو re-model‘ re-fashion‘ re-design‘ reform کیا جاتا ہے۔ اسلامی جدت پسندی کے اندر گویا یہ چیز سامنے آتی ہے۔
اس کا ایک بہت بڑا آلہ اصولِ تفسیر ہیں۔ مثال کے طور پر سرسید احمد خان نے اپنے اصولِ تفسیر مرتب کیے۔ بعد کے لوگوں میں ڈاکٹر فضل الرحمٰن صاحب بھی اس حوالے سے بہت مشہور ہیں۔وہ Gadamer کی Double Movement سے بہت متاثر تھے۔ اس کے ذریعے کچھ ایسے معاملات کیے جاتے ہیں جن میں گنجائش نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اب نیا دور ہے‘ اس کے تقاضے ہیں۔ متن کو بدلنا تو ممکن نہیں ہے‘ وہ تو تکذیب (blasphemy) ہو جائے گی۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اس کی تشریح کے اندر حالات کے مطابق جتنا تغیر و تبدل کیا جا سکے اور اس کو زمانے کے مطابق بنایا جا سکے‘ اتنا کیا جائے۔ جیسے علّامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ایک منہج تو یہ ہے: ع ’’زمانہ با تو نسازد‘تو با زمانہ ستیز!‘‘ یعنی اگر زمانہ تم سے سازگاری نہیں کرتا تو تم زمانے سے لڑو اور اپنے بیانیے کو‘ اپنے نظریے کو غالب کرو۔ دوسرا آسان اور سہل طریقہ یہ ہے کہ ع ’’ زمانہ با تو نسازد تو با زمانہ بساز! ‘‘ یعنی جس کو ہم تجدد کہتے ہیں کہ اگر زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا تو تم زمانے کے ساتھ سازگاری کر لو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کے بیانیے کو خارج کے تقاضوں اور مغرب کے خیالات و نظریات کے مطابق ڈھال دیا جائے۔
اسی حوالے سے اسلامی جدیدیت کے دو تین ٹرینڈز ہیں‘جن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ مغرب کی مرعوبیت کی وجہ سے ہم اپنی اس تعبیر دین کو جو علومِ نبوت کے حوالے سے تھی‘ چھوڑ کر ایک نئی تشریح کی کوشش کریں۔ پورے دین کو revise کرنے کی سعی کریں ۔ اس کو ترمیم پسندی( revisionism)بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک عنوان Islamization of West بھی ہے کہ مغرب کے افکار کے متعلق کہا جائے کہ یہ اسلام ہے اور اسلام بھی یہی چاہتا ہے ۔جیسے Kurzman کہتا ہے کہ لبرل اسلام یا لبرل شریعہ‘یا یہ کہ شریعت بجائے خود لبرل تھی۔ دوسرا رویہ جو جدیدیت کی بگڑی ہوئی شکل ہے‘ کہ کوئی ایک آدمی اٹھے اور کہے کہ اسلام کو تو سمجھا ہی نہیں گیا‘اس کی غلط تفہیم ہو گئی۔ جیسے یہ تصور پیش کیا گیا کہ ایک معیاری اسلام (normative Islam ) ہوتا ہے‘اور ایک historical Islam ہوتا ہے۔یعنی ایک کی بنیاد نص پر ہے جبکہ دوسرے کی تاریخی واقعات پر۔ ہم تو اصل میں معیاری اسلام کے نمائندے ہیں۔ ہم ازسرنو پورے دین کا جائزہ لیں گے اور ایک تعبیر نو کریں گے۔ اس تصور کو Westernization of Islam کہا جاتا ہے کہ اسلام کو مغرب کے سانچے کے مطابق ڈھالنا۔ تیسرا رویہ یہ ہے کہ سیکولرازم کے نظریے کو کھلم کھلا قبول کر لیا جائے اور بلاوجہ اسلام کی مرمت کرنے کی زحمت نہ کی جائے۔ یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ مغرب کے اندر اسلام کی اساسات ڈھونڈیں‘دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو مغرب کی مراد کے مطابق ڈھال لیں‘ تو کہا گیا کہ اس زحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ دین اگر اس دور کے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتا تو ہم لبرل ازم‘ ماڈرن ازم‘ ہیومن ازم اور سیکولرازم کو قبول کر لیں۔ مذہب کا اگر کوئی دائرہ ہے تو محض انفرادی سطح پر پوجا پاٹ اور کچھ عقائد کی حد تک ہے‘ جبکہ زندگی کے اجتماعی پہلوئوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔
اب ہم پھر علّامہ اقبال کی طرف پلٹتے ہیں۔ Kurzman اور رفعت حسن نے ان کا ایک مقام معیّن کیا ہے۔ اب ہم کچھ اور مفکرین کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر Annemarie Schimmel ایک معتدل خاتون ہیں‘ وہ کہتی ہیں:
‘‘ Iqbal's Revaluation of Man is not that of Man qua Man, but of Man in relation to God.’’
یہ بہت اہم نکتہ ہے ۔علّامہ اقبال کے ہاں انسان اور اس کی خودی کا بہت تذکرہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ روایتی علم کلام میں سب سے اہم چیز خدا کا تصور تھا‘ اس کی ذات تھی۔ اسی لیے علم کلام یا علم العقیدہ کا ایک اور نام الٰہیات (theology)بھی ہے۔ علّامہ اقبال کاخیال یہ تھا کہ اس پر تو بہت کلام ہوا کہ خدا کیا ہے اور اس کی صفات کیا ہیں‘ اس کے افعال کیا ہیں‘ اب اس پر گفتگو ہونی چاہیے کہ انسان کیا ہے! یہاں پر بہت اہم بات ہو رہی ہے کہ اقبال کا تصورِ انسان بلحاظ کردار (qua) انسان نہیں ہے یا انسان as such نہیں ہے۔جیسے کہا گیا کہ proper study of mankind is mankind‘یا Protagoras نے کہا تھا کہ man is the measure of all things ۔ علّامہ اقبال کے ہاں انسان پر بہت زور ہے لیکن وہ انسان خدا کے reference سے ہے۔جیسے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے دو ہی ڈھنگ ہیں: ایک consciousness of being in world اور دوسرا consciousness of being with God۔ ایک یہ ہے کہ دُنیا کے ساتھ کیسے رہنا ہے‘دنیا کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے‘جبکہ ایک یہ ہے کہ مجھے خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے تو اس میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے! اسی طریقے سے A.J.Arberry نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ علّامہ اقبال کے ہاں صوفیانہ افکار کا بڑا ذکر ہے‘ اور انہوں نے اس چیز کو واضح کیا ہے۔ علّامہ اقبال نے نکلسن کو جو خط لکھا ‘ اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی خودی کا تصور ایک ایسا ارتقائی عمل ہے جو درحقیقت مسلم صوفیائے کرام کے براہِ راست ذاتی مشاہدے اور غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ علّامہ اقبال خود سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تصورِ خودی نیٹشے(Nietzsche) ‘ برگساں (Bergson) یا مغرب کے کسی مفکر سے مستعار نہیں بلکہ اپنے لوگوں سے ہے۔ اقبال کا ایک قطعہ ہے: ؎
نہ از ساقی نہ از پیمانہ گفتم
حدیث عشق بے باکانہ گفتم
شنیدم آنچہ از پاکانِ اُمت
ترا با شوخیٔ رندانہ گفتمیعنی میں نے جو کچھ لیا ہے وہ اس اُمّت کی پاک ہستیوں‘ اولیاء اللہ سے لیا۔
چونکہ اسلامی جدّت پسندی ہمارا موضوع ہے تو H.A.R.Gibbاپنی مشہور کتاب میں اقبال اور اسلامک ماڈرن ازم کے بارے میں کہتا ہے:
“One looks in vain for any systematic analysis of new currents of thought in the Muslim world, since almost all of the books written in English and French fall into the category of apologetics, seeking either to defend Islam or to show its conformity to contemporary thinking.”
apologetics یا تو ایک دفاعی عمل ہے یا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام عصر حاضر کے جدید فکر سے موافقت پیدا کر رہا ہے۔ Gibb کہتا ہے:
‘‘Outstanding exception is the Indian scholar and poet, Sir Muhammad Iqbal who in his six lecture in the Reconstruction of Religious Thought in Islam faces outright the question of reformulating the basic ideas of Muslim theology and demands a fresh examination of fundamentals of Islamic belief.,,
یعنی علّامہ اقبال نے مکمل طور پر ایک تفصیلی جائزہ لیا ہے اور ان کے ہاں سرسری معاملات نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز چونکہ مغرب سے آ گئی ہے تو اب گویا: ع ’’ہوگئے شیخ بھی حاضر نئی تفسیر کے ساتھ‘‘۔ایسا نہیں ہے۔
پھرW.Cantwell Smith ایک بہت اہم علمی شخصیت تھے ۔ برصغیر میں اسلام کے حوالے سے ان کی بھی کتاب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں:
“ Theologically, Iqbal wrought the most important and the most necessary revolution of modern times. He did this by making God not merely transcendent but also immanent.”
اب یہ بہت اہم بات ہے کہ اقبال کا جو تصورِ خدا ہے اس میںماورائیت (transcendence) ہے لیکن خدا کی مطلقیت (immanence) پر بہت زیادہ زور ہے ۔یہ جو بہت سے لوگ علّامہ اقبال کو اسلامک ماڈرن ازم کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں‘ اس کے پیچھے بھی یہی بات ہے۔ مثال کے طور پر ۲۰۰۷ء میں چارلس ٹیلر کی کتاب آئی تھی: A Secular Age۔ اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ماڈرن فریم ورک پہلے transcendental تھا جبکہ اب immanent ہے۔ یعنی مغرب کا اس وقت پورا بیانیہ یا اس کے سماجی تصورات بنیادی طور پر immanence پرکھڑے ہوئے ہیں۔ علّامہ اقبال کے ہاں بھی یہ چیز بہت زیادہ نمایاں ہے۔
اب میں چاہتا ہوں کہ علّامہ اقبال کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جدید دنیا کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے۔’’خطبات‘‘ میں کہتے ہیں:
‘‘During the last five hundred years, religious thought in Islam has been practically stationary.’’
یہ علّامہ اقبال کاایک گلہ ہے جسے اور بہت سے لوگ بھی شیئر کرتے ہیں کہ ایک خاص طرح کا جمود ہے۔اگر کبھی علّامہ اقبال کی فکر کو دیکھیںکہ وہ سرشتہ کیا ہے‘ وہ کون سا میلان ہے جو علّامہ اقبال کی نثر اور نظم میں دوڑ رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرکت ہے‘تبدیلی ہے اور ایک خاص معنوں میں ارتقا ہے۔ انہوں نے تو اجتہاد کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ: Principle of movement in Islam ۔یہ حرکت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو معاملات میں جمود آ گیا تھا‘ اس پر اقبال نے نقد کی ہے۔
‘‘ There was a time when European thought received inspiration from the world of Islam.’’
اوائل نشاۃِ ثانیہ (Early Renaissance) کے بارے میں مغرب کے منصف مزاج لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس کے اندر مسلمان مفکرین اور فلاسفہ کا ہاتھ ہے ۔ انہوں نے یونانی فلسفیوں کی کتابیں انگریزی زبان میں ترجمہ کیں۔ اندلس کی یونیورسٹیوں میں یورپ کے نوجوان گئے اور انہوں نے اپنے علوم کو دوبارہ سے زندہ کیا تو اس میں مسلمان بہرحال ایک اہم ذریعہ بنے۔ لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ اب خود اہل اسلام مغرب کی طرف بگٹٹ بھاگ رہے ہیں‘ جو کہ بظاہر ایک حیرت انگیز عمل ہے۔ البتہ اس کے پیچھے بھی ایک فکر ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:
‘‘ The most remarkable phenomenon of modern history, however, is the enormous rapidity with which the world of Islam is spiritually moving towards the West.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
There is nothing wrong in this movement, for European culture, on its intellectual side, is only a further development of some of the most important phases of the culture of Islam.’’
یہ ایک بہت اہم بات ہے اور یہ وہ تھیم ہے جو ہمیں اور لوگوں میں بھی ملتی ہے۔ مثلاً حالی نے کہا: ؎
شریعت کے پیمان ہم نے جو توڑے
وہ لے جا کے غیروں نے سب آج جوڑے’’پس چہ باید کرد‘‘ میں علّامہ اقبال کا ایک بہت اہم چھوٹا سا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں: ؎
قوتِ مغرب نہ از چنگ و رباب
نے ز رقص و دخترانِ بے حجاب
نے ز سحر ساحرانِ لالہ رُوست
نے ز عریاں ساق و نے از قطع مُوست
محکمی او را نہ از لادینی است
نے فروغش از خطِ لاطینی است
قوتِ افرنگ از علم و فن استاگلا وہ مصرع ہے جس کے لیے میں نے یہ سب پڑھا ہے کہ : ع’’از ہمیں آتش چراغش روشن است !‘‘ ایک تو یہ تصور ہے جو اقبال نے قبل ازیں بھی کہا کہ مغرب کی ظاہری چکا چوند نے ہمیں مسحور کر دیا ہے تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ایسا شاید مغرب کی قوت کے باعث ہے۔ انہوں نے بال ترشوا لیے ہیں اور اپنی مشرقی کلاہ اتار کے ہیٹ پہن لیا ہے یا خواتین نے بال کاٹ لیے ہیں ۔ پھر کہا کہ خط ِلاطینی بھی اس کا سبب نہیں ہے۔ اس میں بھی گویا طنز ہے مصطفیٰ کمال پاشا پر کہ اس نے رسم الخط بدل دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اصل چیز علم و فن سے ہے۔ یہ آتش گویا ہمارے چراغ سے روشن ہے۔یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے بہت کچھ لیا گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں:
‘‘Our only fear is that the dazzling exterior of European culture may arrest our movement and we may fail to reach the true inwardness of that culture. ’’
اس مغربی کلچر کا ایک اندرون (inner core)ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ یہ اپنی اصل میں قرآنی ہے۔ خاص طور پر یہ کہا کہ استقرائی استدلال (inductive reasoning)کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے۔ ہمارے فلاسفہ یونان کے فلاسفہ سے متاثر ہو گئے تھے اور انہوں نے اس کی تقلید میں آفاق پر توجہ دینے کی بجائے انفس پر بہت زیادہ توجّہ دی۔ پھر کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تھیوری anti-classical ہے ‘ یعنی وہ یونانی فلسفے کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم glittering exterior ہی کے اندر غرق ہو کر رہ جائیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ:
‘‘It is necessary to examine in an independent spirit what Europe has thought and how far the conclusion reached by her can help us in the revision and, if necessary, reconstruction of theological thought in Islam.’’
یعنی ہمیں ذرا آزادانہ سوچ کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے۔ غلامانہ ذہنیت کے ساتھ نہیں کہ بس وہاں سے جو حکم نامہ آرہا ہے‘جو خیال آ رہا ہے اسی کو اسلام میں تلاش کیا جائے۔
‘‘ The only course open to us is to approach modern knowledge with a respectful but independent attitude.’’
جدیدیت یا جدید فکر و فلسفے کے بارے میں علّامہ اقبال چاہتے ہیں کہ حریت ِفکر پیدا کی جائے۔ یہ امر اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ہم ((اَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا))(رواہ الترمذی و ابن ماجہ) کو مانتے ہیں‘ یعنی جہاں سے خیر ملے لینا ہے‘ لیکن ایسا آزادانہ طور پر کرنا ہے۔ اگر یہ احتیاط نہ کی گئی تو وہ یورپ کے بارے میں بہت سخت فیصلہ دے رہے ہیں:
‘‘ Europe today is the greatest hindrance in the way of man's ethical advancement.’’
یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر مسلمانوں نے توجہ نہیں کی اور وہ مغرب کی چمکتی ظاہریت کے درپے ہو گئے تو پھر جیسے وہاں پر انسان کے اخلاقی آدرشوں کو نقصان پہنچاہے‘ مسلمان بھی اسی خرابی کا شکار ہو جائیں گے ۔
Sorokin نے کہا تھا کہ دو طرح کے کلچر ہوتے ہیں۔ ایک حواسی تہذیب (Sensate culture) ہے جس میں ٹھوس اشیاء پر غور کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف تصوری تہذیب (Ideational culture) ہے جس میں خیالات ہیں‘ مثالیت پسندی ہے۔ افلاطون کی World of Forms ہے۔ تصوّرات اور روحانیت پر زور ہے۔ Sorokin کے مطابق‘ مغرب sensate culture کا نمائندہ ہے جبکہ مشرق‘ جس میں اسلام بھی ہے‘ ideational culture کا ترجمان ہے۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ ایسا امتزاج ہونا چاہیے اور ایک مثالی کلچر بنے کہ جس میں sensate elements بھی آئیں اور ideational elements بھی ۔ یوں لگتا ہے کہ علّامہ اقبال بھی کچھ ایسا ہی چاہتے تھے۔ ان کا منہج تطبیق کا ہے۔ ان کو یہ لگتا تھاکہ مغرب والوں کے پاس وسائل ہیں‘ ان کے پاس ذرائع ہیں لیکن ان کے پاس بڑا فکر نہیں ہے اور وہ آفاق میں گم ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے پاس ارفع خیالات ہیں‘ ان کے آئیڈیل بہت بلند ہیں‘ لیکن ان کے پاس ذرائع اور وسائل نہیں ہیں۔ اکبر کا ایک بہت اعلیٰ شعر ہے: ؎
پرانی روشنی میں اور نئی میں فرق اتنا ہے
اُسے کشتی نہیں ملتی‘ اِسے ساحل نہیں ملتایعنی مغرب کے پاس کشتی ہے‘اس کے پاس وہ ذرائع ہیں کہ وہ اپنے ہر خیال کو حقیقت کا روپ دے لیتا ہے ‘ لیکن اس کے پاس ساحل کا‘ منزل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو پرانی روشنی ہے‘جو اسلام کے پاس ہے‘جو مذاہب کے پاس ہے‘ان کے پاس ساحل کا تصور ہے۔ ان کے پاس آدرش ہیں‘ لیکن انہیں مجسم صورت دینے کے لیے ان کے پاس اسباب نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا تھا : ؎
نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی
کہ رُوحِ شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھیاب ہم یہ عرض کریں گے علّامہ اقبال کو جس طرح کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اسلامی جدیدیت کے محرک proponent)) ہیں‘ کیا یہ بات ٹھیک ہے! اس حوالے سے میں نے چند نکات لکھے ہیں ‘ وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔
اگر تو جدیدیت کا مطلب تجدد ہے‘ یعنی خارج کے تصورات کی بنیاد پر ایک انفعالیت کے ساتھ اسلام کو ڈھال دینا‘ تو علّامہ اقبال کے ہاں اس کا شائبہ نہیں ہے۔ البتہ اگر جدیدیت کا مطلب دورِ حاضر کا ایک اندازِ فکر ہے‘ کوئی جدید فکری بحث (discourse) ہے تو اقبال کے ہاں جدید علم کا ہمیں جگہ جگہ تعصب ملتا ہے۔ مذہب کے metaphysical essence کی بھی اگر انہوں نے فلسفیانہ طور پر تائید کی ہے تو اکثر جگہوں پر اس کے لیے استدلال مغربی فلسفے ہی پر رکھا گیا ہے۔ پھر ان کا جو تصوّرِ انسان ہے اس کی تشکیل میں بھی ہمیں بہت سے مغربی مفکرین کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے‘ اگرچہ اس جوہری فرق کے ساتھ کہ وہاں پر خدا غائب ہے‘یہاں پر خدا حاضر ہے۔ بہرحال بہت سی جگہوں پر ہیومن ازم اور انسان کی عظمت کی جو ترانے مغرب میں گائے گئے ہیں اس کی کچھ نہ کچھ چھاپ ہمیں ملتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال کے مطالعے کا ایک دیانت دارانہ تجزیہ یہ ہے کہ جدیدیت یا جدت پسندی کے بہت سے اجزاء ان کے ہاں پائے جاتے ہیں‘لیکن ان سب کو ملا کر جو کُل علّامہ بناتے ہیں وہ بہرحال دینی ہے اور اسلام ہی کا نمائندہ ہے۔ علّامہ اقبال کو جو بہت بڑی شکایت تھی ‘وہ جمود کی تھی۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں چاہے مذہبی تعبیرات ہوں‘چاہے قانون سازی ہو‘چاہے کلامی مباحث ہوں‘وہ برمحل (relevant) نہیں رہے اور زمانے کے لحاظ سے مؤثر اور کارگر ہونے کی صلاحیت ان میں کم سے کم ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں تغیر اور حرکت پر بہت زیادہ زور ہے۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم ماضی کے جس
construct میں قید ہو گئے ہیں وہ اب بوسیدہ ہو چکا ہے اور ہمیں اس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دین کو ہمیں پوری purity پر قائم کرنا ہے‘ یعنی علّامہ اقبال بہت سی جگہوں پر قرونِ اولیٰ کی بات کرتے ہیں۔یہ بات بھی ملحوظِ خاطر رکھنی چاہیے کہ علّامہ اقبال کی شخصیت میں دو بڑے مؤثرات ہیں۔ایک ان کا تعلق بالقرآن ہے جو بچپن سے ان کے ہاں تھا۔قرآن سے محبت‘قرآن سے تعلق اور قرآن کی شان جیسے علّامہ اقبال نے بیان کی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ اسی طریقے سے رسولﷺ کے ساتھ ان کی جو محبت ہے‘ تعلق ہے‘ جو والہانہ شیفتگی پائی جاتی ہے وہ بھی غیر معمولی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دو سیفٹی والوز یعنی قرآن کی عظمت کا غیرمعمولی احساس اور صاحب قرآنﷺ سے محبت نے ان کو ایسے pitfalls سے بچا لیا جن کا بہت سے اسلامی تجددپسند شکار ہو گئے۔ علّامہ اقبال یہ چاہتے ہیں کہ دین کی ایک effective relevance قائم رہے۔ جس چیز پر انہوں نے تنقید کی ہے‘ ایک تو تقلیدی ذہن ہے کہ مکھی پہ مکھی ماری جائے اور پرانی چیزوں کو ہی بار بار دہراتے جانا ہے۔ اگر زوال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور مرعوبیت بہت بڑھ گئی ہے تو ایک جگہ انہوں نے کہا : ؎
ز اجتہادِ عالمانِ کم نظر
اقتدا بر رفتگاں محفوظ تریعنی جو لوگ دین میں کتربیونت کرنا چاہتے ہیں‘ اسے مغرب کی مراد پر ڈھالنا چاہتے ہیںوہ عالمانِ کم نظر ہیں‘ان کے اجتہاد سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے اسلاف کی اقتدا کی جائے۔ یہ احوط ہے‘ اسلم ہے‘ زیادہ سلامتی والا راستہ ہے۔ بہرحال ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ تقلید کے تصوّر نے دین کو منجمد کر دیا ہے‘ اس کو توڑا جائے۔ دوسرے‘ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کو اس کی کلاسیکی صلابت(purity) یعنی قرآن و سُنّت سے تمسک کے ساتھ مانا جائے۔ چونکہ یہ دین عالمگیر ہے‘ لہٰذا ہر تہذیب کے اوضاع اور اصولوں کو دین کی روشنی میں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ان کے ہاں relevance والا پہلو بہت نمایاں ہے۔
کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے انہوں نے روایتی علماء اور روایتی مفکرین پر بھی تنقید کی ہے۔ وہ یہ کہ دنیاوی علم میں ہم پیچھے رہ گئے۔ انسان اور دنیا کا جو تعلق ہے‘ جو رائج الوقت علم ہے اس کے حوالے سے کوتاہی کی گئی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہدایت کا paradigm تمام علوم میں جاری و ساری دکھائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انسان اور دنیا کے حاضر علوم سے لاتعلق رہیں گے‘حاضر علمی روایت میں شامل نہیں رہیں گے تو پھر آپ کے عقائد اور آپ کا ہدایت پر ہونا ایک ایسی چیز بن جائے گی جس کو لوگ نظر انداز کر دیں گے۔
برصغیر میں پہلی مرتبہ یہ مقدمہ علّامہ اقبال نے پیش کیا۔ وائٹ ہیڈ نے کہا تھا کہ بیسویں صدی میں دو بڑی حقیقتیں ہیں‘ایک مذہب جبکہ دوسری سائنس‘ اور ان کے تال میل ہی سے اب یہ طے ہو گا کہ دنیا کے معاملات کیسے آگے جائیں گے۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علّامہ اقبال نے مذہب کو بھی ایک خاص پہلو سے empiricise کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ مغرب نے یہ کہہ دیا تھا کہ علم کی شرط تجربی توثیق ہے تو علّامہ نے کہا کہ ٹھیک ہے‘ ہم مان لیتے ہیں لیکن ایک تجربہ خارجی ہوتا ہے جبکہ دوسرا داخلی ‘ روحانی‘ ذاتی ہوتا ہے۔ پھر اقبال نے وحدتِ آدمؑ کا تصور پیش کیا۔ کئی بڑے لوگوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا کیونکہ وحدتِ آدم کا قرآنی ideal اُس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وحدت کی بنیاد کسی ما بعد الطبیعی اصول پر نہ رکھی جائے‘ اور پھر اس کی کارفرمائی دُنیاوی علوم میں بھی دکھائی جائے۔ مثال کے طور پر سائنس میں اس کا عمل دکھایا جائے۔ یہ تو ایک تصوّر ہےجسے علّامہ اقبال سامنے لے کر آتے ہیں۔ پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ خاص طو رپر خطبات میں علّامہ اقبال کا مخاطب ذہن مغربی علوم کا تعلیم یافتہ ہے‘ اسی کا ساختہ پرداختہ ہے۔ اس کے تقاضے علماء پورے نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی وجہ سے علّامہ اقبال کو خیال ہوا کہ میں اس میں کوئی خدمت کروں ۔ ان کی سچائی اس لحاظ سے بھی سامنے آتی ہے کہ چونکہ علومِ اسلامیہ میں ان کو رسوخ اور گہرائی حاصل نہیں تھی‘تو وہ علماء کو بار بار متوجّہ بھی کرتے رہے۔ ان سے رہنمائی کے لیے خط بھی لکھتے رہے۔
فلسفہ اقبالؒ میں جدیدیت کے حوالے سے جو اشارے ہیں جیسے حلولیت ((anthropomorphism یا بشرمرکزیت (anthropocentrism) ‘ وہ بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ خطبات میں ہمیں انسان مرکزیت نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر تصورِ خودی میں خدا کے قد یا سائز کو کچھ بشری مجبوریوں میں سکیڑ دیا گیا ہے اور انسان کی شان کے اندر الوہیت کے پہلو دکھائے گئے ہیں۔ وحدت الوجود ی منطق تو جیسے فنا پر کھڑی ہوئی ہے‘ وہاں ممکن نہیں کہ وہ جو آخری دائرہ ہے وہاں انائے صغیر انائے کبیر کے مقابلے میں کھڑی ہو‘لیکن علّامہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ وہ آخری درجے میں انسان کے تشخص ‘ اس کی انانیت کو بندے کے طور پر قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ’’بالِ جبریل ‘‘کی پہلی غزل کا پہلا شعر ہے: ؎
میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں
غلغلہ ہائے الاماں بت کدۂ صفات میںوہاں پر بھی وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پوری شناخت کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے انسان کا قد بہت بڑھا دیا ہے اور اسے خدا کا رفیق کار (co-worker) بنا دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں بھی گویا مبہم (problematic) ہیں۔ یہاں پر جو چیز کبھی کبھی ناگوار بھی محسوس ہوتی ہے کہ جدیدیت کے اثر میں بھی ایک safety یہ ہے کہ اقبال کا انسانِ کامل کا تصوّر وہی ہے جو مسلم صوفیوں عبدالکریم جیلی سے‘ ابن عربی سے لیا گیا ہے‘اگرچہ یہاں بھی نبی اکرمﷺ کا ماڈل ہر لحظہ ان کے پیش نظر ہے: ؎
بمصطفیٰؐ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
اگر بہ او نرسیدی‘ تمام بولہبی استگویا یہ سیفٹی والوز بھی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ جہاں بعض اوقات بہت پریشانی ہونے لگتی ہے کہ انسان کا بیان اتنا بڑا کر دیا گیا ہے ‘ اس کے اندر الوہی شان دکھائی گئی ہے اور خدا کے تصورات کمپرومائز کر دیے گئے ۔
علّامہ اقبال ‘ وائٹ ہیڈ سے کافی متاثر تھے۔ وائٹ ہیڈ کی پروسیس تھیولوجی میں ایسے ہی لگتا ہے کہ خدا اور انسان تال میل سے اور مل جل کر اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اس طرح کے تصورات ہمیں اقبال کے ہاں بھی ملتے ہیں۔ جیسے یہ تصور کہ خدا کے ہاں بھی مستقبل ایک open possibility کے طور پر ہے۔ انسان کے لیے تو یہ بات ماننے والی ہے لیکن خدا کے لیے بھی چیزیںopen ہیں ‘یہ تصور مشتبہ ہے۔ علّامہ اقبال کے ’’خطبات‘‘ کا مخاطب جدید مسلم ذہن ہے جو علم اور اخلاق میں مغرب کو ماڈل سمجھتا ہے۔ یہ ذہن جدیدیت تک محض اتفاقاً پہنچا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے پورے شعور کے ساتھ اسے قبول کیا ہے بلکہ درحقیقت اس کے سطحی تاثر ہی کو قبول کر کے اپنی روایت سے انحراف کا ذریعہ بنا لیا ہے۔تاثر کی سطح پر جدیدیت مذہبی ما بعد الطبیعیات ‘مذہبی اخلاق یہاں تک کہ خدا کے ذہنی و جذباتی انکار کا رویہ پیدا کر دیتی ہے ۔اس لیے مغرب سے متاثر مسلمان سب سے پہلے اپنے دین سے اور پھر اپنی تہذیب سے یا تو برگشتہ ہو گئے یا پھر شرمندگی اور احساسِ کمتری محسوس کرنے لگے۔ اقبال نے انہی لوگوں کو اپنا موضوع اور مخاطب بنایا جن کے اندر نفسیاتی طور پر روایت سے جدیدیت اور دین سے لادینی کی طرف منتقلی کا عمل شروع ہو چکا تھا ۔ان خطبات کا موضوع یہ ہے کہ جدیدیت کے بنائے ہوئے ذہن اور دنیا میں مذہب کا امکان رہ گیا ہے یا نہیں!کہنے کو تو آخری خطبے کا نام ہے: Is Religion Possible? لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا پورے خطبات میں انڈر کرنٹ کے طور پر یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ اب ہمارے زمانے میں مذہب کا کیا امکان باقی رہ گیا!
علّامہ اقبال کے ہاں جدیدیت کی طرف مائل تصورات بھی ہیں لیکن کچھ چیزیں انہیں جدیدیت کا نمائندہ بننے سے روکتی ہیں ۔ایک تو یہ کہ ان کا تصور ِکائنات بظاہر لگتا ہے کہ انسان مرکز ہے لیکن درحقیقت وہ انسان خدا کے آگے سربسجود ہے۔ آخری تجزیے میں اقبال کا پورا بیانیہ بشر مرکزی (anthropocentric) نہیںبلکہ خدامرکزی (theocentric) ہے۔ وہ ہر چیز کو خدا کے حوالے سے معین (define) کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مسلم دنیا میں جدیدیت کا ایک بہت بڑا تصوّر نیشنل ازم بنا۔ علّامہ اقبال قومیت یا قوم پرستی کی جتنی بھی تعریفات ہیں‘ ان کو ردّ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے قومیت کی اساس ان کے دین کو بناتے ہیں ۔ بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ تہذیبی تناظر میں اقبال کے تصور ِخودی کی یہ خاصیت واضح ہے کہ اس کے ذریعے سے اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر پایا جانے والا احساسِ کمتری غائب ہونا شروع ہو گیا اور جدیدیت سے بننے والی دنیا اور اس میں کار فرما نظامِ مراتب کے خلاف سب سے طاقتور آواز اقبال کی ثابت ہوئی ‘اور تاحال بھی ایسا ہی ہے ۔
آخر میں چارلس ٹیلر کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک کتاب کے دیباچے میں انہوں نے اقبال کا ذکر کیا ہے اور اس کا آغازیہاں سے کیا ہے : We must re-read Iqbal ۔ ہمیں اقبال کو دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے ایک بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے:transient modernisms۔ ان کے نزدیک ہمارے ہاں کے وقتی جدت پسند(transient modernists ) ‘ مثال کے طور پہ سرسید‘ حالی ‘ شبلی کارآمد نہیں تھے۔ اقبال کےبیانیے کو چارلس ٹیلر بہرحال کارآمد شمار کرتے ہیں۔ خاص طو رپر جس علّامہ اقبال نے مشرق اور مغرب دونوں کے مفکرین سے استفادہ کیا اور ایک امتزاج پید ا کیا ہے وہ غیر معمولی ہے۔ پیٹر برگر کی ایک کتاب۱۹۷۰ء کی دہائی میں چھپی تھی:
‘‘The Heretical Imperative: Contemporary Possibilities of Religious Affirmation’’
جو سوال علّامہ اقبال نے اٹھایا تھا‘ وہی کوئی ۴۵ برس بعد پیٹر برگر اٹھا رہا ہے کہ جدید دنیا میں مذاہب کی تشکیل ِنو کا کیا امکان باقی رہ گیا ہے۔ اس نے ایک بہت اچھی topology بنائی ہے‘جو علّامہ اقبال کے کام کو سمجھنے کے لیے بھی مفید ہے۔ کہتا ہے کہ اہل مذاہب کے پاس ایک راستہ استخراجی ((deductive ہے۔ یعنی آپ مذہب کی حاکمیت کا دوبارہ دعویٰ کریں اور اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں‘isolate کر لیں۔اس کی انتہا بنیادپرستی (fundamentalism) ہے۔یہ وہ رویہ ہے جو عام طور پر روایتی) traditional) علماء کا تھا‘جس کی پہچان و شناخت (symbol) دیوبند رہا۔اسی کے بارے میں مولانا مناظر حسن گیلانی علیہ الرحمۃ نے کہا کہ یہ اصحابِ کہف کی سُنّت ہے کہ اپنا خزانہ‘اپنی روایت کو بچا لو‘علیحدہ ہو جاؤ‘ گوشہ گیری(seclusion )میں چلے جاؤ۔ دوسرا رویہ تقلیل کا عمل ( reductive approach )ہے۔ یعنی :
‘‘to interpret tradition in terms of modern secularity’’
یہ تصوّر secularists نے دیا‘اور اس کی چھاپ سر سید احمد خاں کے ہاں اورڈاکٹر فضل الرحمٰن کے ہاں ملتی ہے۔انہوں نے لادینیت ( secularity )کے سامنے گویا ہار مان لی اور کہا کہ اپنے دین کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ یہ بھی ایک انتہا کی رائے ہے۔ کہتے ہیں کہ مذہب کے لیے تیسرا راستہ استقرائی ((inductive ہے۔ پیٹر برگر کہتا ہے:
‘‘ Inductive option is to turn to experience as the ground of all religious affirmations, one’s own experience to whatever extent this is possible. And the experience embodied in a particular range of tradition.’’
یہ جو کہا گیا ہے کہ تجربے ( experience ) کو بنیاد بنائیں‘صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی‘ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ علّامہ اقبال کی option ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ درمیانی راہ ہے۔ نہ تو یہ deductive ہے کہ آپ اپنے آپ کوبالکل الگ (aloof) کرلیں‘ اور نہ ہی یہ reductive ہے کہ ہر چیز کو جدیدیت کے پیمانے پر پرکھا جائے‘ بلکہ ایک لحاظ سے یہ inductive ہے کہ آزمایا جائے۔ پھر living tradition کے مطابق اقبال کو relate کر کے دکھایا جائے۔ علّامہ اقبال کے ہاں جتنی سخت تنقید ہمیں ملتی ہے‘ وہ اور کہیں نہیں ملتی۔ میں چند اشعار علّامہ اقبال کی مثنوی ’’پس چہ باید کرد‘‘ میں سے بلاتبصرہ اور بغیر ترجمے کے آپ کے سامنے رکھتا ہوںتاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ مغرب پر کیا فیصلہ دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں:
عقلہا بے باک و دِلہا بے گداز
چشمہا بے شرم و غرق اندر مجازآگے سنیے: ؎
علم و فن‘ دین و سیاست‘ عقل و دِل
زوج زوج اندر طوافِ آب و گلجدید تہذیب مادیت پسند اور الحادی (profane )ہے۔ پھر کہتے ہیں: ؎
عقل و دین و دانش و ناموس و ننگ
بستہ فتراکِ لردانِ فرنگیہ جو تصور تھا کہ کس طریقے سے ہمارے نوجوان مغرب گزیدہ ہیں: ؎
ترا وجود سراپا تجلیٔ افرنگ
کہ تُو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیراور ؎
گرچہ مکتب کا جواں زندہ نظر آتا ہے
مُردہ ہے‘ مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفَساور ؎
یورپ از شمشیر خود بسمل فتاد
زیر گردوں رسم لادینی نہادمغرب کا سب سے بڑا جرم الحاد‘ لادینیت(secularity) ہے۔ پھر کہا کہ: ؎
در نگاہش آدمی آب و گل است
کاروانِ زندگی بے منزل استآگے استعماریت (colonialism) اور ملوکیت ( imperialism ) کی طرف اشارہ ہے۔ اس حوالے سے بھی سب سے توانا آواز اقبال کی ہے : ؎
دانش افرنگیاں تیغے بدوش
در ہلاکِ نوعِ انساں سخت کوش
آہ از افرنگ و از آئین او
آہ از اندیشہ لادین او
دانی از افرنگ و از کارِ فرنگ
تا کجا در قید زُنّارِ فرنگہماری صورتِ حال یہ ہے کہ : ؎
زخم ازو‘ نشتر ازو‘ سوزن ازو
ما و جوے خون و اُمید رفویعنی ہم Stockholm syndrome کا شکار ہیں‘ ہمیں اپنے اغواکار اور قاتل سے محبت ہو گئی ہے۔ ؎
خود بدانی پادشاہی قاہری است
قاہری در عصر ما سوداگری استیہ بات کہ ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے لیے آئی اور پھر اس کے ذریعے یہاں پر قبضہ کیا۔ ؎
تختهٔ دُکّاں شریک تخت و تاج
از تجارت نفع و از شاہی خراجیہ دو طرفہ لوٹ ہے‘کہ یہاں سے سارا خام مال لے کر چلے گئے اور پھر اسی سے مصنوعات تیار کر کے ہمیں بیچیں‘ جس پر ٹیکس بھی عائد کیے۔ دونوں پہلوئوں سے لوٹ مار کی۔ پھر کہتے ہیں: ؎
آن جہانبانی کہ ہم سوداگر است
بر زبانش خیر و اندر دِل شر است
کشتن بے حرب و ضرب آئین اوست
مرگہا در گردشِ ماشین اوستچنانچہ استعماریت اور ملوکیت کے بارے میں یہ سارا بیانیہ ہمیں اس امر سے روکتا ہے کہ علّامہ اقبال کو ایک اسلامی جدت پسند گردانیں۔ علّامہ اقبال کی پشت پر دو بڑی طاقتیں تعلق بالقرآن اور تعلق بالرسولؐ ہیں۔ پھر یہ کہ علّامہ اقبال کی آخری تصنیف جو ان کی وفات کے بعد چھپی ہے ’’ارمغانِ حجاز‘‘ اس میں اردو کے حصے میں ’’ابلیس کی مجلس شوریٰ‘‘ ایک غیر معمولی بیان ہے جس میں مغرب اور ابلیسی طاقتوں پر نقد کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے ۱۹۳۶ء میں فارسی کا جو آخری کلام چھپا ’’پس چہ باید کرد اے اقوامِ مشرق‘‘ اس میں علّامہ اقبال نے اپنے نسب نامے (genealogy )کا سراغ لگایا ہے۔ اپنے مرشد بتائے ہیں۔ ایک قریب کے مرشد ہیں اکبر الٰہ آبادی ‘ اور ایک ذرا دُور کے مرشد ہیں رومی ۔ رومی ہماری پوری مسلم روایت کے نمائندے ہیں۔ علّامہ اقبال اور اکبر الٰہ آبادی میں ایک فرق یہ ہے کہ اقبال کے ہاں زیادہ گفتگو اصولی اور نظریاتی ہے‘ جبکہ اکبر نے تہذیبی اوضاع پر اور ان کے مظاہر (manifestations )پرغیر معمولی گفتگو کی ہے۔ بہرحال مغرب کے بارے میں علّامہ اقبال ایک واضح پوزیشن رکھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں: ؎
چو رومیؒ در حرم دادم اذاں من
ازو آموختم اسرارِ جاں من(رومی کی طرح میں نے بھی حرم میں اذان دی ‘انہی سے میں نے روح کے اسرار سیکھے)
بہ دورِ فتنۂ عصرِ کہن او
بہ دورِ فتنۂ عصرِ رواں من(عصرِ کہن کے فتنوں کو رومی نے رد کیا اور عصرِ رواں کے فتنوں کا میں نے)
مغرب کی پوری فکر اور اس کے جو اوضاع ہیں‘اس کو وہ فتنے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی اسلامی جدت پسند یہ کبھی نہیں کرے گا۔ ان کے ہاں تو جیسے ہمیشہ ایک معذرت خواہانہ ( apologetic )انداز رہا ہے۔
ان تمام معروضات کا حاصل یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگرچہ علّامہ اقبال کے تصورِ انسان اور تصورِ علم میں ہمیں جگہ جگہ مغرب کی پرچھائی نظر آتی ہے اور بہت سی جگہوں پر ہم ایک دوجذبیت (ambivalence) بھی دکھا سکتے ہیں‘اور ہر بڑے آدمی کی طرح کچھ تضادات بھی نمایاں کر سکتے ہیں لیکن من جملہ آخری تجزیے میں علّامہ اقبال آج بھی مسلم روایت کے سب سے بڑے محرک اور پیش کنندہ ( proponent) ہیں۔علّامہ اقبال نے جو بات اورنگ زیب عالمگیر ؒکے بارے میں کہی تھی‘ لگتا ہے کہ اس کا اطلاق خود ان پر بھی ہوتا ہے۔انہوں نے کہاتھا: ؎
درمیانِ کارزارِ کفر و دیں
ترکش ما را خدنگ آخریں(کفر و دین کے معرکہ میں ہمارے ترکش کا آخری تیر اورنگ زیب عالمگیر ہے)
آج ہم علّامہ اقبال کے بارے میں بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللّٰہ أعلم بالصواب!
(تہذیب و تدوین : محمد خلیق‘ شعبہ مطبوعات)