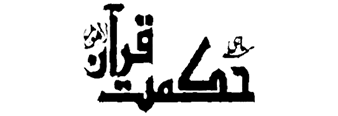(فکر و نظر) جدید اخلاقی بحران کی فکری بنیادیں - ڈاکٹر محمد رشید ارشد
9 /جدید اخلاقی بحران کی فکری بنیادیںڈاکٹر رشید ارشدتعارف
جب آدمی کسی مرض میں مبتلا ہوجائے تو معالج سب سے پہلے عیاں علامت کا معائنہ کر کے لاحق مر ض کی تشخیص کرتے ہوئےاس کے اسباب کی نشان دہی کرتا ہے۔ بعد ازاں لاحق مرض سے نجات کے لیے پرہیز یا ہدایات تجویز کی صورت میں فراہم کی جاتی ہیں۔ فرد کی طرح ایک معاشرہ بھی کئی طرح کے امراض میں مبتلا ہوسکتا ہے۔ معاصر جدید معاشرے کو لاحق امراض کی علامات‘ جنہیں چارلس ٹیلر نے مجموعی طور پر ’’جدیدیت کی گھبراہٹ‘‘ (malaise of modernity ) کا عنوان دیا‘ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ البتہ ان کی درست تشخیص اتنی واضح نہیں ہے۔ چونکہ جدیدیت کے موجودہ مظاہر کی داستان فکری تاریخ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے‘ اس لیے جدید دور میں تشویش ناک حد تک پروان چڑھ چکے سماجی مسائل کی بروقت تشخیص کے لیے ان کی فکری بنیادوں سے آشنائی بے حد ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ افکار و نظریات خارج پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کہے میں کسی شک کی گنجائش بھی نہیں۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ انتہائی گہرے اثرات کے حامل افکار و نظریات سے بسا اوقات صرفِ نظر کرلیا جاتا ہے۔ یہ فکری بنیادیں ہمارے شعور کی داغ بیل ڈالتے ہوئے ہماری روزمرہ زندگی کے معمولات کو متعین کرتی ہیں۔ ان کی مدد سے ہم ظہور پزیر ہونے والی اشیاء کے بارے تعینا ت قائم کرتے ہیں اور امکاناتِ زیست کی حد بندی کرتے ہیں۔ ایک نظریہ جتنا زیادہ مؤثر ہوگا اتنا ہی اس کے ادارہ جات‘ روایات اور خیالات میں سرایت کر جانے کے قوی امکان موجود ہوں گے۔ ایسے تمام نہایت اہم افکار و نظریات کی جانچ پڑتا ل کرنا اور ان پر کوئی رائے پیش کرنا ایک دِقت طلب کام ہوتا ہے۔ اگرچہ افکار و نظریات کے خارج پر اثرات تو واضح ہوتے ہیں لیکن ہم عموماً اپنے سماجی اور ثقافتی حالات و واقعات کے پیچھے کار فرما اُن افکار و نظریات کی نشان دہی بہ آسانی نہیں کر پاتے۔
چند تمہیدی باتیں
معاصر جدید دنیا میں گوناگوں مسائل نظر آتے ہیں اور اسے طرح طرح کے امراض لاحق ہیں۔ ان میں سب سے مہلک مرض اخلاقی بحران ہے۔ زیر ِنظر تحریر میں بالخصوص جدید اخلاقی بحران کی فکری بنیادوں کو سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی۔ جو اثرات‘ علامات کی صورت میں نظر آ رہے ہیں‘ ان کی نہ صرف فکری بنیادوں تک رسائی ضروری ہے بلکہ اس تاریخی سیاق و سباق کو سامنے لانا بھی اہم ہے جس میں ان افکار نے جنم لیا اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی نشو و نما کرتے رہے۔ اقبال اجمیری کے شعر میں خوب صورتی سے اس امر کو بیان کیا گیا ہے: ؎
وقت کرتا ہے پرورش برسوں
حادثہ ایک دم نہیں ہوتاجدید افکار نے جہاں ماضی کی روایات‘ نظریات‘ رسومات اور اقدار کو اپنے انداز سے مسخ کیا‘ وہیں ادیان بھی ان کی یلغار سے بچ نہ سکے۔ ایمانیات کے بعد دین کو سب سے بڑا چیلنج اخلاقیات کے شعبے میں درپیش ہے۔ جدید مغرب نے نفسِ انسانی کی تمام سطحوں سے خدا کی بے دخلی کا جو منظم منصوبہ بنایا تھا اس میں ذہن کو ایمان سے نامانوس کر دینا‘ اخلاق کو ارتقائی عمل کا نتیجہ قرار دے کر طبیعت کے اخلاقی جوہر کو غیر مذہبی بنا دینا اور ان دونوں کے نتیجے میں پورے انسانی نصب العین کو بدل کر رکھ دینا تھا۔ یہ اس منصوبے کے خاص الخاص مقاصد تھے۔
یہ بات بجا ہے کہ جدید افکار نے اپنے منفی اثرات سے سابقہ روایت کی اعلیٰ اقدار کی شکست و ریخت میں اہم کردار ادا کیا‘ تاہم اپنے حصے کی کوتاہی سے صرفِ نظر بھی خوش آئند نہیں۔ بقول سلیم احمد: ؎
میں وہ سفاک آنکھیں ڈھونڈتا ہوں
جو خود کو دیکھنے کی تاب لائیںبدقسمتی سے کچھ مدّت ہوگئی ہے کہ ہمارے ہاں مختلف اسباب سے ایمان‘ شعور‘ اخلاق اور طبیعت کے تلازمات پر زیادہ توجہ نہ دی جاسکی۔ ان سب سے آدمی کے اخلاقی وجود کو بھی‘ جو اپنی ساخت میں ظاہردین سے جڑ کر نشو ونما پانے والاہے‘ اپنے مربوط اور تخلیقی اظہار کا موقع نہ مل سکا۔ہماری اجتماعی دانش کی کم از کم دو صدیوں سے یہ عالمگیر کوتاہی اور پس ماندگی ہے کہ اس نے دینی بیانیے کے ایک لازمی کردار یعنی’’ تغیر کی خُو رکھنے والے آدمی‘‘کو سرے سے نظرانداز کیے رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی کا ذہن اور اس کی دنیا اگرچہ تبدیلی کے جبری اورفطری نظام کے تحت بدلتی رہی‘ لیکن تبدیلی کی اس رو کی باگ دین کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ انسانی اجتماعیت کے نئے نئے ادارے بنتے رہے اور ان میں وسعت اور پیچیدگی بھی پیدا ہوتی رہی‘ مگر مذہبی ذہن اور کردار اس سارے عمل سے لاتعلق رہا۔ اسے یہ احساس ہی نہ ہو سکا کہ خاص طور پر اخلاق اگر اجتماعیت کی فعال اساس نہ بنیں تو یہ محض شاعرانہ تصورات بن کر رہ جاتے ہیں‘ جن کی آدمی کو فی الواقع کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ نئے سماجی اور اجتماعی رشتوں نے اپنے جواز اور بقا کے لیے ایک ایسا اخلاقی در و بست ترتیب دیا جس کے نتیجہ خیز طور پر عمل میں آنے کے بعد یہ سوال رفتہ رفتہ زیادہ سنگینی اختیار کرتا چلا گیا کہ ’’آدمی کو اپنی اخلاقی رہنمائی کے لیے آخر مذہب کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ‘‘ جدید مغرب نے اخلاق میں ایک تنظیمی مضبوطی اور قانونی پھیلاؤ پیدا کر کے یہ دکھانے کی کاوش کی کہ اخلاق کے فطری اور آفاقی اصول کسی بھی مابعد الطبیعی سیاق وسباق سے نہ صرف یہ کہ آزاد ہیں‘ بلکہ یہ آزادی ہی آفاقی اخلاقی اقدار کے قیام کا سبب اور ان کے تغیر آشنا تسلسل کی ضامن ہے۔مذہب اپنے structural تحکم کی وجہ سے ذہن اور اخلاق کی حرکت کو روک دیتا ہے جس کے نتیجے میں نئے اصول اور ان کے تازہ اطلاقات کی پیدائش کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔اوپر سے اہلِ مذہب نے مکمل طور پر غیر مؤثر ہو جانے کے بعد انسان اور دنیا پر اپنا تصرف بحال کرنے کے لیے جو علمی اور اخلاقی کوششیں کیں وہ اتنی فرومایہ بلکہ غیرانسانی تھیں کہ انہیں دیکھ کر وہ لوگ بھی مغربی تصوّراتِ علم و اخلاق سے متاثر ہونے پر مجبور ہوگئے جن کا مغربی تہذیب سے تعلق نہ تھا۔موجودہ زمانے میں یہ صورتِ حال غالباً اپنی قبیح ترین شکل میں سامنے آ چکی ہے۔ اب کسی راسخ العقیدہ مخلص مسلمان کے لیے بھی یہ کہنا ممکن نہیں رہا کہ اہل ِاسلام اپنے ہی مسلمہ اخلاقی معیارات پر مغرب کی برابری کر سکتے ہیں۔ یہ اس بحران کا انتہائی درجہ ہے کہ دین سے سنجیدہ اور مخلصانہ وابستگی رکھنے والے خدا ترس لوگ ایک ذہنی اور اخلاقی کم تری کے احساس میں مبتلا ہو چکے ہیں‘ اور اس سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں پاتے۔
ایک طرف دہشت گرد قوتیں دین کے عالمگیر غلبے کے آئیڈیل کی آڑ لے کر سرگرمِ عمل ہیں تو دوسری طرف عالم ِ اسلام کی عمومی بے حسی اپنے عروج پر ہے۔ ان دونوں نے مل کر اسلام کاایسا تشخص بنا دیا ہے جسے قبول کرنا ‘ ذہنی طور پر پس ماندگی ہے اور اخلاقی طور پر سفاکی۔ ایسی ناموافق فضا میں جو عالمگیر ہے‘ یہ لازمی طور پر ایک بڑا چیلنج دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کو ماننے یا مسلمان ہونے کا علمی اور اخلاقی جواز کیا ہے! مغربِ جدید کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان اپنی تمام علمی و اخلاقی ضرورتیں خدا اور مذہب کے بغیر زیادہ کامیابی اور آزادی کے ساتھ پوری کر سکتا ہے۔ اس دعوے کو قیاسی منطق اور idealistic استدلال سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تردید کے لیے جوابی عملی ماڈلز درکار ہیں جن سے عالم ِ اسلام خالی ہے۔ ہم دین اور اخلاق کے لازمی تعلق پر نظری بحث تو یقیناً کر سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی حاصل وصول نہ ہوگا‘ کیونکہ ہمارا عمل ہمارے نظریے سے مطابقت نہیں رکھتا‘ اور یہی ہمارے خلاف سب سے بڑا گواہ ہے۔ اختلاف اس بات پر نہیں ہے کہ دین اخلاق کا ماخذ بن سکتا ہے یا نہیں‘ اصل جھگڑا اس چیز پر ہے کہ اخلاق کے لیے دین ناگزیر ہے بھی یا نہیں! اس پہلو سے ہم خود احتسابی کے جذبے کے ساتھ گفتگو کریں گے جس میں خود کو کوئی رعایت دیے بغیر یہ دیکھنے اور بتانے کی سعی کی جائے گی کہ انسان کا اخلاقی وجود اس کے ایمانی وجود سے منقطع ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا ‘اور یہ صرف مذہبی دعویٰ نہیں بلکہ ایسی مسلّمہ حقیقت ہے جسے استدلال کی ہر قسم سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔
ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مغرب کے اس دعوے کی کیا حقیقت ہے کہ اس نے مذہب سے آزاد ہو کر اخلاقی آدرش حاصل کر دکھایا ہے۔ مغرب کیا واقعی دُنیا کے لیے ایک اخلاقی نمونہ ہے؟ کیا اخلاق کے فطری آئیڈیلز مغرب نے حاصل کر لیے ہیں؟ ہمارا جواب ہے کہ نہیں! مغرب نے یقیناً ایک محکم ترین اجتماعی آرڈر بننے میں کامیابی حاصل کی ہے لیکن اس آرڈر کی اساس اخلاق نہیںبلکہ طاقت ہے۔طاقت کے ڈھانچے کمزور پڑ جائیں تو مغرب وہ تہذیبی اور اخلاقی سکت نہیں رکھتا کہ اپنے اس نظام کو برقرار رکھ سکے‘ جس میں مثال کے طور پر لوگ سچ بولتے ہیں‘ خوراک میں ملاوٹ نہیں کی جاتی‘ قانون پسندی کا دور دورہ ہے۔ مغربی تہذیب ایک آرگنائزیشن یا کارپوریشن کی طرح ہے جس کے ہر کارکن کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دی گئی ہے کہ اگر تم نے طے شدہ ضابطوں اور مقاصد کی پابندی نہ کی تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ زندگی میں جتنی رنگینی اس آرگنائزیشن کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے وہ سراب بن جائے گی۔ اس طرح کی افادیتی تنظیم‘ مفاداتی قانون پسندی اور تاجرانہ دیانت داری سے ‘مبنی بر اخلاق تہذیب نہیں پیدا ہوتی۔ تہذیب کچھ اور شے ہے جبکہ اجتماعی اداروں کی working chain کچھ اور۔ بالکل غیر مذہبی زاویے سے بھی اگر مغربِ جدید کا تہذیبی اور نفسیاتی تجزیہ کیا جا سکے تو یہ بات زیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہے گی کہ مغرب کی نام نہاد اخلاقی برتری کے تمام مظاہر فطری اور اخلاقی نہیں بلکہ مشینی اور افادی ہیں۔ اخلاق کے موضوع کو مذہبی فکر نے سادہ تو رکھا لیکن اسے محدود بھی کر دیا۔ اسی طرح مغرب نے اخلاق میں ذہنی اور نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا کر کے اسے واقعے سے زیادہ تہذیبی اور ارتقائی بنا دیا۔آج ہمیں اپنے تصوّرِ اخلاق کے ایسے فہم اور بیان کی ضرورت ہے جس میں انسان کے اخلاقی وجود ہونے کی مستقل بنیادیں اور دائمی غایات بھی آجائیں اور اس کے ساتھ ان تفصیلات کا بھی قدرے احاطہ ہوجائے‘ جو زمانے کی تبدیلی سے اور وقت کے تقاضوں کے تحت انسان کی اخلاقی تشکیل کے مسلسل عمل میں ایک مؤثر کردار رکھتی ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ فطری سے ہماری اور مغرب کی مراد کیا ہے! مغرب اگر اخلاق کو فطری مانے گا تو اس کے یہاں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اخلاق طبیعی‘ نفسیاتی اور ارتقائی ہوتے ہیں‘ جبکہ ہمارے یہاں فطری کا مفہوم اس سے بالکل مختلف ہے۔ انسان مخلوق ہے اور اس کی تخلیق کا مادہ اور مقصود اپنے خالق کی بندگی ہے۔ اس اصلِ بندگی کی قبولیت اور پوری کی پوری استعداد انسان کو دے کر پیدا کیا گیا ہے۔ اس قبولیت اور استعداد کو فطرت کہتے ہیں اور فطری سے مراد وہ امر ہوتا ہے جو ہماری وجودی ساخت اور بندگی کے تقاضے کے مطابق ہو۔ جب ہم اخلاق کو فطری کہتے ہیں تو ہماری مراد اس کے سوا نہیں ہوتی کہ یہ بندگی کے فضائل ہیں جنہیں انسانیت کے بنیادی مادے کی حیثیت حاصل ہے۔
تصوّرِ اخلاق کا براہِ راست تعلق اس سوال سے ہے کہ :انسان کیا ہے؟ انسان ایک سماجی وجود ہے‘ انسان ایک عقلی وجود ہے یا محض طبعی وجود ہے جس میں شعور اور اجتماعیت وغیرہ اتفاقی طور پر در آئے ہیں؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ انسان بندگی کی اصل پر قائم ایک سماجی وجود ہے‘ یعنی انسان انفرادیت اور اجتماعیت دونوں سطحوں پر ان شرطوں سے خالی نہیں ہوسکتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس حیثیت میں ایک اس کی تنہائی ہے‘ اور ایک معاشرت ۔ اخلاق ان تینوں زاویوں سے انسانی شخصیت کی تشکیل کے اسباب اور نتائج ہیں۔ اسباب کی حیثیت سے یہ فطری‘ تہذیبی اور قانونی ہیں جبکہ نتائج کے اعتبار سے یہ وہ فضائل ہیں جو دنیا کو بھی اچھا بناتے ہیں اور آخرت میں بھی فلاح کا ضامن بنتے ہیں۔ اس تصورِ انسان کی روشنی میں یہ تو ممکن ہے کہ بعض مظاہر اخلاق کسی تہذیبی پیش رفت سے پیدا ہوجائیں‘ لیکن یہ محال ہے کہ اخلاق کا پورا نظام یعنی تعلق باللہ‘ اپنے نفس کے ساتھ تعلق اور دوسرے لوگوں یا چیزوں کے ساتھ تعلق کسی تہذیب کے نتیجے میں پیدا ہو۔ انسان کے معاشرتی اخلاق بھی بندگی کی اصل پر تشکیل پاتے ہیں۔ تعلق باللہ سے تربیت پانے والا اخلاقی وجود ہی سماجی ہونے کے ہر طرح کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ وہ تقاضے مذہبی بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مذہبی بھی‘ یعنی تہذیبی و عرفی وغیرہ بھی۔ مسلم تصوّرِ اخلاق میں انسانوں کے باہمی تعلق کو خیر کے ماحول میں پروان چڑھانے والی تمام قوتیں وہی ہوتی ہیں جو تعلق مع الحق سے حاصل ہوتی ہیں اور اسی حوالے سے اخلاقی اصالت‘ سند اور اہمیت اخذ کرتی ہیں۔ تعلق باللہ کے آداب سے بے بہرہ ہو کر انسانی تعلقات کا نظام اخلاقی پیمانے پر نہیں چلایا جا سکتا‘ چاہے اس نظام میں کتنی ہی خوش حالی‘ سلامتی اور کامیابی نظر آئے۔ یہ ایک آفاقی مسلّمہ ہے کہ اخلاق‘ دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ مسلم تناظرمیں یہ ’’دوسرا‘‘ بلحاظِ اصل اللہ ہے اور عارضی طور پر تعلق کے دائرے میں آنے والی سب چیزیں۔ مغربی تصورِ اخلاق سے ہمارا اصل اختلاف یہی ہے کہ اخلاق کی اساس بننے والا ’’دوسرا‘‘ کون ہے۔ ان کے یہاں یہ ’’دوسرا‘‘ اوّل تو مستقل اور متعین نہیں ہے اور اگراہلِ مغرب کو بتانا ہی پڑے تو وہ کبھی انسان کا نام لیں گے‘ کبھی ریاست کا اور کبھی معاشرے کا‘ جبکہ ہمارے یہاں اس سوال کا ایک ہی جواب ہے۔
جدید تصوّرات پر استوار دنیائے جدید کا تار و پود
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مغرب اپنی تہذیبی برتری کو دنیا سے منوانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کے علمی و اخلاقی زوال کے تقریباً تمام مظاہر مغرب ہی کی سوچی سمجھی تخلیقات ہیں جن کو مسلمان اپنے دینی شعور اور مزاج میں بگاڑ آجانے کی وجہ سے پہلے تو سمجھ نہ سکے اور جب مغرب کا یہ تخریبی کردار سمجھ میں آگیا تو اس کے ازالے کی کوئی مؤثر قوت مسلمانوں کے پاس نہیں تھی۔ چونکہ ہم اخلاقیات کے مخصوص پہلو سے جدید افکارکے مضر اثرات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں‘ اس لیے آئندہ صفحات میں ہم دنیائے جدید کی نقشہ گری کرنے والے ان جدید تصورات کا جائزہ پیش کریں گے جنہوں نے اخلاقیات کے شعبے میں در اندازی کرتے ہوئے اخلاقی بحران کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے۔
سیکولرازم
سیکولرازم کے نقاد اس کے فکر اور اخلاقی انحطاط میں پائے جانے والے ربط کی نشان دہی کرتے ہیں۔ ۱۹۴۸ء میں ایک امریکی مضمون نگار رچرڈ ویور نے لکھا ‘کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جدید آدمی اخلاقی سطح پر خبط کا شکار ہے۔ وِیور کے نزدیک اس کا سبب ماورائی وجود کی حقانیت اور بذاتِ خود سچ اور صداقت کا انکار ہے۔ جدید فکر میں انسان کو ہر معیار بہ شمول اخلاقی معیار طے کرنے کے اختیارات کی دستیابی کے ساتھ ہمہ گیر اخلاقی اقدار کا خاتمہ ہونا شروع ہوا جس کے نتیجے میں معاشرت میں موضوعیت‘ نرگسیت اور انانیت جیسے مہلک انسانی رویوں نے جنم لیا۔ فرد کو آزاد ‘خود مختار متصور کر کے انانیت پسندی کے فلسفے نے جدید اخلاقیات میں اپنے لیے جگہ بنائی۔ اخلاقیات میں انانیت پسندی ایک ایسا فلسفہ ہے جو انفرادی مفادات کو اجتماعی مفاد پر ترجیح دیتے ہوئے فرد کو خودغرضانہ انداز میں محض اپنی بھلائی‘ افادے اور مسرت کے کاموں کو سرانجام دینے کی تلقین کرتا ہے۔ اس نظریے کے تحت فرد کے لیے اولین اخلاقی فریضہ ذاتی خواہشات کی تکمیل ہے۔ اخلاقیات کا یہ نظریہ اجتماعی معاشرے کی اقدار( مثال کے طور پر فلاحِ عامہ‘ عدل وانصاف اور مجموعی معاشرت) کی بہتری کی راہ میں حائل ایک بہت بڑی رکاوٹ کے طور پر سامنے آتا ہے۔ فرد کی مرکزیت پر پُرزور تاکید کی وجہ سے یہ اخلاقی فلسفہ تمام روایتی نظریات سے کٹ جاتا ہے۔ اس نظریے نے فرد کی فطرت کی خود غرضانہ جہت کو تقویت پہنچائی اور اخلاقیات کے تمام شائستہ اصولوں کو تہس نہس کرتے ہوئے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا۔
اپنی کتاب After Virtue میں میک انٹائر نے یہ مقدمہ پیش کیا ہے کہ یورپ اخلاقی سطح پر تباہ و برباد ہو کر نظری اور عملی دونوں حوالوں سے اخلاقیات سے محروم ہو چکا ہے۔ مغربی ثقافت میں اخلاقیات کے ساتھ ہونے والے کھلواڑ کے نتیجے میں اب وہاں کوئی مربوط اخلاقی نظام وضع نہیں کیا جاسکتا۔ جدید اور مابعد جدید پیرائے میں دیکھا جائے تو مغربی معاشرہ ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں ہمہ گیر صداقت‘ اخلاقی اصول اور تقدیس نامی کسی شے کا وجود تک باقی نہیں ہے۔ ہمہ گیریت اور ماورائیت کے انکار کے ساتھ افراد کے رویوں میں پیدا ہونے والے غیر انسانی اوصاف نے سرزمین مغرب کو بحیثیت مجموعی اخلاق باختہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ خدا کے انکار سے پیدا ہونے والےخلا کو انسان دوستی یا انسان مرکزیت کے فلسفہ سے پُر کیا گیا۔ دیکھا جائے تو خدا سے انکاری سماج کے لیے انسان دوستی ہی واحد متبادل نہیں ہے بلکہ ایک راہ Nihilism کی جانب بھی جاتی ہے۔ وجودی Nihilismکی رُوسے انسانی زندگی معنویت سے خالی ہے‘ جبکہ اخلاقی Nihilism کی رُو سے ہمہ گیر اخلاقی ضابطے کا کہیں وجود نہیں۔ یہ محض انسانی معاشروں کی اختراع ہے تاکہ وہ اس بے معنی دنیا میں گزر اوقات کو ممکن بنا سکیں۔ Nihilism اس بات کو سامنے لاتی ہے کہ زندگی سے متعلقہ وجودی نوعیت کے سوالات کا کبھی تشفی بخش جواب فراہم ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ازلی اور ابدی سچائی کا سرے سے وجود ہی نہیں۔ اس فکر کے ماننے والوں کے نزدیک انسان دوستی کا فلسفہ بھی مذہبی اقدار سے اخذ کردہ التباس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو معاصر تہذیب ِمغرب کی درست نمائندگی سیکولر انسان دوستی کی بجائے Nihilism کر رہی ہے جو کسی بھی اخلاقی ضابطے کو کسی بھی صورت تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ تاریخ فلسفہ کے مطالعے سے یہ باور ہوگا کہ Nihilism سائنس پرستی‘ متشدد اضافیت پسندی اور ہمہ گیر سچائیوں کے مابعد جدید انکار کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ ۱۹۷۰ء کی دہائی میں امریکہ میں پھیلی سیریل کلنگ میں ملوث مجرمان کے بیانات سن کر اندارہ ہوتا ہے کہ کیسے اخلاقی اضافیت پسندی اور Nihilism ایک دوسرے میں مدغم ہو چکے ہیں۔
جدید تصوّرِ عقل
جدیدیت کا پہلا نمائندہ فرانسیسی فلسفی رینے ڈیکارٹ کو سمجھا جاتا ہے‘ جس نے قبل از جدید خدا مرکزیت کی حامل بادشاہت اور کلیسا کے اختیارات کو علمیات کی بنیاد پر انسان مرکزیت کی حامل موضوعیت سے بدل دیا۔ مافوق الفطرت الوہی ذات کا تصور خارج از بحث ہوگیا اور اختیارات کی مرکزیت خود مختار انسانی عقل کے ہاں منتقل ہوگئی۔ اگرچہ رینے ڈیکارٹ خدا پر ایمان رکھتا تھا‘ تاہم یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس کی فکر نے تشکیک پسندی‘ لاادریت اور الحاد کے بیج بوئے۔ڈیکارٹ کی علمیات سے عقلیت کو روایتی‘ مذہبی اور الہامی کلام کے اوپر غلبہ حاصل ہوا۔ ذہن اور جسم کی دوئی سے مذہب کو مادی دنیا کے معاملات سے بے دخل کر دیا گیا۔ تاہم‘ اگر عہدِ وسطیٰ کی فکری تاریخ کا بھی جائزہ لیں تو علمیات میں بتدریج تبدیلی نے اُس دور سے اخلاقیات کو اپنے طور پر متاثر کیا ہے۔ تھامس اوقیناس نے دو مابعد الطبیعی حلقوں طبیعی فطرت (nature) اور grace کا ذکر کیا ہے۔ ان کے مطابق طبیعی فطرت کو ہم اپنے حواسِ خمسہ کی معلومات اور معقولات کو تصرف میں لاکر جان سکتے ہیں۔ البتہ اس طبیعی فطرت سے ماوراء ایک حقیقت ہے جسے صرف وحی کی روشنی میں جانا جاسکتا ہے۔ یعنی grace کے زمرے میں الوہی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے جب کہ طبیعی فطرت پر فطری قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ اوقیناس کی قائم کردہ اس دوئی نے بعد کی مغربی فکر میں ایک نیا تصوّر متعارف کروایا۔ الوہی قوانین کے ماتحت grace کو وحی سے جب کہ فطری قوانین کے ماتحت طبیعی فطرت کو حسیات اور عقل سے جانا جاسکتا ہے۔ روزمرہ زندگی کے اخلاقی اعمال میں اوقیناس نے انسانی عقل کے عمل دخل کو بنیادی اہمیت دی ہے۔ وحی کی رہنمائی کی حاجت روزمرہ معمول سے ہٹ کر روحانی سرگرمیوں کی انجام دہی میں پڑتی ہے۔
تحریک روشن خیالی کی فکر میں خود مختار انسانی عقل کا درجہ مذہبی احکامات اور وحی سے بلند قرار پایا۔ انسانی عقل کو معیار بناتے ہوئےایمانیات اور معجزات وغیرہ کو غیر عقلی قرار دے کر ان کا انکار کر دیا گیا۔ ازمنۂ وسطیٰ میں وحی کی رہنمائی کے بغیر عقل کو مہمل کہا گیا‘ جبکہ جدید دور میں عقل کی رہنمائی کے بغیر وحی کو مہمل قرار دیا گیا۔ جدید تصورِ عقل آلاتی عقل یعنی instrumental reason کا داعی ہے۔ مخصوص مقاصد کے حصول کے لیےبطور آلہ مستعمل عقل کو فلسفیانہ اصطلاح میں آلاتی عقل کہا جاتا ہے۔ جہاں یہ تصورِ عقل جدید سائنسی انقلاب اور فنیات کی ترقی کے لیے ممد و معاون ثابت ہوا وہیں اس نے تاریخِ انسانیت کے کئی المناک حادثات کو بھی جنم دیا ہے۔ جدیدیت کا یہ مقدمہ رہا ہے کہ ماضی کی توہم پرستانہ روایات سے آزادی‘ متروکہ خیالات سے قطع تعلقی اور بربریت سے نجات جدید تصورِ عقل یعنی instrumental reason کی رہنمائی میں ممکن ہو پائی۔ جدید دنیا کے معاشیاتی‘ سیاسیاتی اور انتظامی ڈھانچوں میں آلاتی عقل کے تصرف کے منفی رُخ کو مابعد جدید مفکر اور فلسفی فوکو اور ہیبرماس نے اپنی تحاریر میں مفصل انداز سے بیان کیا ہے۔ بحیثیت مجموعی انسانی رویوں اور اخلاقیات پر اس طرزِ ذہنیت کے مہلک اثرات پڑے ہیں۔ آلاتی عقل کی پیروی میں انسان جذبات اور احساسات سے عاری ہوتے ہوئے اپنے گرد و نواح اور فطرت سے قائم زندہ تعلق سے ہاتھ دھو بیٹھا۔
روایت میں عقل ایک جزو تھی لیکن جدید تصورِ عقل کے مطابق یہ جسم‘ جذبات‘ احساسات‘ سماج اور تاریخی سیاق و سباق سے کٹ کر اپنے آپ میں ایک خود مختار اور آزاد کُل بن چکی ہے۔ سرد اور بے مہر خواص کی حامل یہ آلاتی عقل کسی لطیف انسانی قدر کو خاطر میں نہیں لاتی‘ لیکن ساتھ ہی بہترین نتائج کی وجہ سے معاشیاتی اور سیاسیاتی انتظام وانصرام کے اداروں اور عوام الناس کی قبولیت بھی حاصل کر لیتی ہے۔ سیکولر انسان مرکزیت نظریے کے مطابق انسانی صلاحیتوں میں عقل کی مرکزی حیثیت ہونے کی وجہ سے اخلاقی فیصلوں میں اسے بنیادی مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ تاہم‘ روایتی اور اسلامی نظریات کے مطابق عقل کو مرکزیت حاصل نہیں ہے۔ عقل وجودِ باری تعالیٰ کی رہنمائی کی روشنی کے بغیر ناقص ہے۔ دوسری طرف سیکولر طرزِ فکر پر مبنی اخلاقیات میں عقل پرستی کے تحت کیےجانے والے فیصلوں کی زیادہ قدر و منزلت ہے۔ امانوئیل کانٹ‘ جیرمی بینتھم اور جان اسٹویرٹ مِل نے ایسے اخلاقی اصول وضع کیے جن سے کوئی معقول آدمی انکار نہ کر سکے۔ تاہم‘ ان تمام نے اپنی اخلاقیات میں جو نتائج اخذ کیے وہ ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ بغور جائزہ لینے پر معلوم ہوگا کہ اخلاقیات کو عقلی معیارات کے تابع کرنے کی تمام کوششوں میں بالآخر غیر عقلی مفروضوں کو بنیاد بنانا پڑتا ہے۔ اب بہت سے سیکولر مفکرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ محض عقل کو اخلاقیات میں self-justified بنیاد ماننا کافی دشوار ہے۔ مثال کے طور پر ڈیوڈ ہیوم کے نزدیک تمام عقلی سرگرمیاں انسانی جذبات کے تابع ہوتی ہیں‘ جبکہ عقلیت پسندوں نے انسانی جذبات کے پہلو کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔ تاہم مذہب اور جدید نفسیات میں یہ مانا جاتا ہے کہ انسانی فطرت کا ایک پہلو ایسا ہے جو کسی صورت بھی تعقلات کے تابع نہیں رہ سکتا۔ انسانی تعلقات اور مراسم میں احترام اور محبت کے رویوں کو عقل کی بجائے انسانی شائستہ جذبات کے تحت ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روشن خیالی کی بہت سی اخلاقی اقدار مسیحیت کی اقدار ہی سے اخذ شدہ ہیں۔ باوجود اس حقیقت کے جدید سیکولر لبرل معاشروں میں ان مذہبی اور روایتی اقدار کو تضحیک آمیزی کا نشانہ بناتے ہوئے انسانی معاشرے کو ان سے علیحدہ کرنے پر بہت زیادہ زور دیا جاتا رہا ہے۔ میک انٹائرکے مطابق اخلاقیات کو تعقلات پر قائم لبرل اقدار کے تابع کرنے کا مشن بری طرح ناکام ہو کر ثقافتی اضافیت پسندی پر منتج ہوا۔
جب کسی مافوق الفطرت واحد ہستی کو انسانی معاملات سے بے دخل کر کے انسان کے خود ساختہ اصول و ضوابط کو رہنما تسلیم کر لیا گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ متفرق خطوں کے‘ مختلف تاریخی سیاق و سباق اور جدا جدا مکانی و زمانی وابستگیوں کے حامل لوگوں کے مختلف نظریات کی بنیاد پر بنائے جانے والے اصول و ضوابط میں فرق کی وجہ سے کیا کوئی ہمہ گیر اصول بنایا جا سکتا ہے! اضافیت پسندوں کا ماننا ہے کہ سچائی نہ تو ہمہ گیر ہے اور نہ ہی مستقل‘ بلکہ جغرافیائی‘ تاریخی اور ثقافتی حوالوں سے بدلتی رہتی ہے۔ اخلاقیات میں اضافیت پسندی کی ترویج پر بہت سے اخلاقی فلاسفہ نے شدید مخالفت کی لیکن اس کے باوجود اس میں کشش کا ایک ایسا پہلو موجو دہے جس پر کوئی دو رائے نہیں پائی جاتیں۔ وہ پہلو ہے: مختلف ثقافتی اور نظریاتی پس منظر کے لوگوں کے ساتھ احسن سلوک سے پیش آنے کی ترغیب۔ بالخصوص استعماری غلبے کے بعد سے اس فکر کو تقویت پہنچی ہے کہ دنیا میں کسی مخصوص کلچر کو کسی دوسرے کلچر پر برتری قائم کرنے کا کوئی اصولی یا اخلاقی جواز موجود نہیں۔ اضافیت پسندی کے مقدمہ کو بشری علوم کی روشنی میں دیکھا جائے تو انواع و اقسام کے خطوں میں رائج رسوم ورواج کی اہمیت کا اقرار بھی اس کے حق میں جاتا ہے۔ البتہ دوسری طرف دیکھا جائے تو ان ہی خطوں میں رسوم ورواج کے نام پر ایسے ایسے لغو قوانین بنائے گئے ہیں جو کہ صریحاً غیر انسانی اور انسانیت کی تذلیل کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس نکتے پر اضافیت پسندی کے مقدمے میں جھول پیدا ہوجاتا ہے۔ اگر اضافیت پسندی کو درست مانا جائے تو پھر دنیا بھر کی تمام مضحکہ خیز اور غیر انسانی رسومات کو بھی درست ماننا پڑے گا۔ اضافیت پسندی کی وجہ سے اجتماعی سطح پر تو معاشرے میں موضوعیت در آئی ہی ہے‘ ساتھ ساتھ فرد کی انفرادی زندگی میں اسی کے راستے موضوعیت اور نرگسیت بھی در آئی ہے جو انانیت پسندی کی طرف لے جاتی ہے۔
سائنسز سے برآمد تصوّرِ انسان
سیکولر فکر میں موجود ’’ترقی‘‘ اور ’’اخلاقی ترقی‘‘ کے تصوّرات تضادات سے بھرے ہوئے ہیں۔ جدید حیاتیاتی سائنس میں انسان کو محض حیوان تصور کیا جاتا ہے جو کہ اپنی جبلی خواہشات کے تابع ہے اور ساتھ ہی انسان کے عقل کی رہنمائی میں تہذیب یافتہ ہونے کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ ان تمام تناقضات اور تضادات کے باوجود ’’ترقی کے تصور‘‘ کی عام مقبولیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ترقی سے وابستہ ’’ایمان‘‘ غیر عقلی ہے۔ نظریۂ ارتقا کے پیش کردہ تصورِ انسان اور اس پر استوار تصور ہائے حیات کو دیکھا جائے تو انسان اپنی حیوانی جبلتوں کے ہاتھوں بے بس اپنی بقا کی خاطر مقابلے کی دوڑ میں شامل اپنے جینیاتی نظام کے تحت مجبور اور بے بس جانور سے زیادہ کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ اس نظریے کی رُو سے انسانی فطرت نامی کوئی شے نہیں۔ انسانی زندگی کی تمام اخلاقی اقدار اور خواص وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آنے والا موافقت اور مطابقت کا لائحہ عمل ہے جو نیچرل سلیکشن سے ممکن ہوا۔ جینیاتی نظام کے تحت انسانی اوصاف کے متعین اور طے شدہ ہونے کے تصور سے ایک خاص قسم کی جبریت پیدا ہوتی ہے۔ ان نظریات سے مسئلۂ ارادہ و اختیار میں شدت پیداہوتی ہے۔ جب سب کچھ جینیاتی ساخت میں متعین ہےتو پھر انسانی اخلاقی نشو و نما اور وعظ و نصیحت کی تمام سرگرمیاں بھی مہمل اور بے معنی ٹھہرتی ہیں‘ کیونکہ جینیاتی معلومات کو بدلنا ناممکن ہے۔
فرانسس کِرک اور بی ایف اسکینر جیسے مفکرین نے فرد کی آزادی کو بالکل ہی رد کردیا اور خارجی طبیعی ماحول کے جبر کی حمایت میں فکر پیش کی۔ بی ایف اسکینر بنیادی طور پر ایک نفسیات دان تھے۔ انہوں نے نفسیات کو جدید سائنسی طریقہ کار کے مطابق ڈھالا اور اپنی تحاریر میں معاملات انسانی سے بحث کرتے ہوئے سائنس اور سائنسی کے الفاظ کا بے دریغ استعمال کیے رکھا۔ ان کے نزدیکthing in itself کا سرے سے وجود ہی نہیں۔ تمام حقیقت طبیعی اور مادی ہے جسے کِرک کے مطابق طبیعیات اور کیمیا کی اصطلاحات میں بیان کیا جاسکتا ہے جبکہ اسکینر کے مطابق انسان کا خارجی ماحول انسانی صورت حال اور ثقافت وغیرہ کا تعین کرتا ہے۔ ان دونوں کے تصوّرِ اخلاقیات میں انسانی بقا کا مقدّمہ گُندھا ہوا ہے۔
اسکینر کے مکتب فکر یعنی Behaviourism میں انسان کو ایک ایسی مجبور شے کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو اپنے خارجی ماحول کے اتار چڑھاؤ کے ہاتھوں بے بس ہے۔ مزید یہ کہ انسانی رویے کو کسی خارجی تکنیکی قوت سے مَن مرضی کے ساتھ بدل کر کسی بھی رنگ میں رنگا جا سکتا ہے۔ اسکینر کا طبیعی پرستانہ تصورِ اخلاق بھی اس کی اس فکری اپروچ سے جڑا ہوا ہے۔سیکولر فکر سائنسی علوم کو ترجیح دیتی ہے۔ سائنسی علوم کے تحت انسانی خصائص اور عادات و خصائل وراثتی طور پر متعین شدہ ہوتے ہیں‘ جب کہ دوسری طرف یہی سیکولر فکر انسانی آزادی کا بھرپور پرچار بھی کرتی ہے۔ اس سے سیکولرازم میں پائے جانے والی خود تضادی واضح ہوتی ہے۔ اگر جبر کے پہلو کو دیکھاجائے تو عقلیت پسندی کے علوم بھی غیر عقلی قوتوں کے زیر ِ تسلط ہیں۔ جدید سائنسی طریقے سے متاثر جدید نفسیات کو جب جرائم پیشہ افراد کی ذہنیت سمجھنے کے لیے استعمال کیا گیا تو انسان سے سر زد ہونے والے عوامل کو خارجی ماحول اور اس کی دسترس سے باہر موجودغیر شعوری قوتوں کی کارفرمائی قرار دیا جانے لگا۔ مزید برآں جرم اور گناہ‘ بدی کو نفسیاتی معنوں میں دیکھا جانے لگا۔ جرائم پیشہ افراد کو سزا دینے کی بجائے ان کو مناسب علاج معالجہ فراہم کرنے کے لیے کارل راجر نے آواز اٹھائی۔ جرائم مرتکب کرنے والوں کو اس وجہ سے سہولت مل گئی۔ جب جرائم کے ارتکاب کو فرد کے شعوری فعل کی بجائے غیر شعوری قوتوں اور اس کے کنٹرول سے باہر عناصر کا عمل دخل قرار دیاجانے لگا تو مجرموں کی حوصلہ افزائی ہونے لگی۔ محققین کا کہنا ہےاس سے جرائم میں مزید اضافہ ہوا۔ اسی طرح جدید نفسیات میں ایسی اصطلاحات کو متعارف کروایا گیا جو معاشرے کے لیے مہلک رویوں کے اوپر غلاف چڑھانے کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ ان تمام عوامل کا نتیجہ معاشرتی‘ سماجی اور اخلاقی بگاڑ کی صورت میں نکلا۔
نظریۂ ارتقا
سیکولر فکر کے متفرق حامی مکاتب فکر کو اگر ایک مشترک نظریہ متحد کرتا ہے تو وہ ہے ڈارون کا نظریۂ ارتقا۔ یہ نظریہ ایک طرف مذہبی عقائد (بالخصوص نظریۂ تخلیق) کا رد کرتا ہے تو دوسری طرف انسانی ترقی اور بہتر مستقبل کے لیے جدّوجُہد کے تصوّر سے مطابقت بھی رکھتا ہے۔ ڈارون کے حیاتیاتی ارتقا کے افکار نے بعدازاں ہربرٹ اسپنسر کے سماجی ارتقا کو جنم دیا۔ اسپنسر نے جب ان افکار کا سماج پر اطلاق کیا تو بقا کی خاطر جنگ کے لیے ایک نسل کے دوسری نسل پر غلبے اور تسلط کو بھی جواز فراہم ہوگیا۔ اگرچہ ڈارون کو موردِ الزام ٹھہرانا مشکل ہوگا‘ تاہم اسی کے افکار نے دوسری نسلوں پر برطانوی اور امریکیوں کے ظلم و ستم کرنے کی راہیں ہموار کیں اور بعد ازاں ہٹلر کی صورت میں نسلی برتری کے زعم میں دوسری نسل کے افراد کا قتل عام کرنے کو معقول قرار دینے میں معاونت کی۔ اسی طرح نو ڈارون ارتقائی افکار انسان کے بے لوث اور لاغرض اعمال و افعال کو انائیت اور خودغرضی کی پیداوار سمجھتے ہیں‘ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے پیش کی جانے والی انسانی قربانیاں بھی بے محل ٹھہرتی ہیں۔ اس فکر کے تحت جو تصوّرِ اخلاق اخذ ہوتا ہے وہ غصہ‘ لالچ‘ حسد اور ان جیسے متعدد اخلاقی رذائل کو انسانی فطرت کے معمولی خاصے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اب اگر انسانی اعمال اس کے جینز کی ساخت نے متعین کرنے ہیں تو پھر نیک اخلاق اور بد اخلاق کے حامل کردار کا بیان ہی بے محل ٹھہرے گا‘ نہ ہی اخلاقیات کا کوئی معیار یا پیمانہ مقرر ہو سکے گا۔ ان تصوّرات سے عمومی رجحان یہ پیداہوتا ہے کہ جیسے اخلاقیات کا سارا نظام سوائے التباس کے کچھ بھی نہیں‘ جس کا نتیجہ لازماًاخلاقی انحطاط ہی نکلتا ہے۔ نظریۂ ارتقا سے قائم کیے جانے والے تصورِ کائنات کو قبول کرنے میں اس کے حامی مفکرین بھی جھجک محسوس کرتے ہیں کیونکہ اس میں ذات‘ اخلاقیات اور معنویت جیسی مباحث بالکل ہی بے معنی ثابت ہوتی ہیں۔ نظریۂ ارتقا نے انسانی قدر و منزلت کو بہت حد تک گرایا اور اسے محض حیوان کے رتبے پر لاکھڑا کیا۔؎
عوض قرآں کے ہے اب ڈارون کا ذکر یاروں میں
جہاں تھے حضرتِ آدم وہاں بندر اچھلتے ہیں(اکبر)سائنسی‘ مادیت پرستانہ اور بالخصوص نظریہ ارتقا کے بعد انسانی مقام و منزلت کی تذلیل کی صورت میں ردِعمل کے طور پر وجودیت پسندی کی تحریک اٹھی۔ الحادی وجودیت پسندی کے سرخیل ژاں پال سارتر نے اخلاقی معاملات میں فرد کی خود مختاری‘ آزادی کی تحریکی روپ میں حمایت کی۔ انسان کا جوہر ‘ اس کا شعور آزاد ہے اور اس کا آزادانہ استعمال ہی اسے مستند وجود بناتا ہے۔ جب تک وہ اپنی آزادی کا استعمال کرکے فیصلوں کا انتخاب نہیں کرتا‘ وہ غیر مستند وجود کے زمرے میں شامل کیا جائے گا۔ آزادی کے اس تصرف میں اسے کسی وجودِ خدا کی حاجت نہیں جو فیصلوں اور انتخابات کے لیے اخلاقی قوانین و ضوابط لاگو کرے۔ ان اخلاقی نظریات سے جنم لیتی انفرادیت پسندی کے راستے معاشرے میں بڑھتی بے راہ روی کے ضمن میں وجودیت پسندی کو ہدفِ تنقید بنایا گیا لیکن سارتر نے بارہا ان اعتراضات کا رد کیا اور فرد کی آزادی کی پُرزور حمایت جاری رکھی۔ سارتر کے نزدیک فرد اپنے آزاد ارادہ کے ساتھ فیصلہ کرکے جو عمل سرانجام دے گا‘ اس کے نتائج کی ذمہ داری اسی کے کندھوں پر عائد ہوگی۔وجودیت پسند اخلاقیات کانٹ کی اخلاقیات کے خود مختاریت کے مسلّمہ سے اتفاق کے ساتھ اس کی فکر میں موجود طبیعی جبریت کی قائل نہیں۔ (جاری ہے)