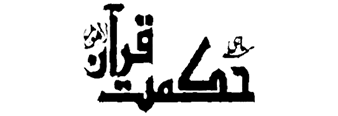(تعلیم و تعلم) تعلیم کے اوّلین اُصول - ڈاکٹر محمد رفیع الدین
9 /تعلیم کے اوّلین اُصول
ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی معروف کتاب First Principles of Education کا اُردو ترجمہ پروفیسرڈاکٹر محمد آصف اعوان نے کیا ہے ۔ڈاکٹر صاحب موصوف اقبالیات میں پی ایچ ڈی ہیں اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں بتدریج چیئرمین شعبہ اردو‘ ڈین فیکلٹی آف اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ اور ڈائریکٹر اقبال چیئر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔۲۰۲۳ءمیں ریٹائرمنٹ کے بعد اس وقت رفاء انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس میں اردو کے پروفیسر اور ڈائریکٹرایڈوانس اسٹڈیز (پی ایچ ڈی پروگرامز) کی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں۔ ان کی بیشتر تصانیف فلسفہ ٔ اقبال اور خصوصاً اقبال کے انگریزی خطبات کے توضیحی مطالعے پر مشتمل ہیں۔ان کا تأثر یہ ہے کہ زیرنظر کتاب عقلی وفکری گہرائی کی حامل ہونے کے ساتھ اخلاقی وروحانی سطح پر بھی انسانی شخصیت کےفکر و کردار کو سنوارنے‘اس میں بالیدگی اور وقار پیدا کرنے کا وسیلہ بن سکتی ہے۔قارئین کی دلچسپی کے لیے اسے قسط وار’’حکمت ِقرآن‘‘ میں شائع کیا جا رہاہے ۔
تعارف
انسان کی تخلیق کچھ یوں ہوئی ہے کہ اس کے پاس ہر عمل کی انجام دہی سے پہلے ایک فلسفے کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا فلسفہ جس قدر زیادہ واضح اور درست ہوگا اُسی نسبت سے اُس کا عمل ثمر آور ہوگا۔ چنانچہ جب بھی کوئی ذہین شخص کوئی کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں حسبِ ذیل سوالات کا ایک واضح جواب رکھتا ہے:
(ا) دراصل وہ کیا چیز ہے جو میں اپنی سرگرمی کے نتیجے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں؟
(ب) میں اِسے کیوں حاصل کرنا چاہتا ہوں؟
(ج) کس طرح میں اِسے بہترین طریقے سے حاصل کرسکتا ہوں؟
یہ بات ایک فرد کی ایسی سیدھی سادھی سرگرمیوں پر بھی صادق آتی ہے جن سے اُسے صرف اپنی ذاتی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے جیسے کہ ٹیلی فون کرنا‘ اپنے لیے چینی ملانا یا خط لکھنا۔ نیز یہ بات اُس کی اُن پیچیدہ سرگرمیوں کے حوالے سے بھی درست ہے جن کے سلسلے میں وہ ایک بڑی تعداد میں دیگر لوگوں کے تعاون اور مدد کا طلب گار ہوتا ہے اور جن کا تعلق پورے سماجی طبقے کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اِن بعد والی سرگرمیوں میں سے ایک سرگرمی معلّم (educator) کی ہے۔ ایک سماجی طبقے کو تعلیم دینے کے کٹھن کام کی ذمہ داری اپنے سرلینے والے معلّم کے ذہن میں بھی حسب ِ ذیل سوالات کا ایک واضح اور درست جواب ہوگا:
(ا ) حقیقتاً وہ کیا ہے جو میں اپنی تعلیمی سرگرمی کے نتیجے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں؟
(ب) میں اِسے کیوں حاصل کرنا چاہتا ہوں؟
(ج) میں اِسے کس طرح بہترین طریقے سے حاصل کرسکتا ہوں؟
دوسرے لفظوں میں ایک معلّم کی سرگرمی اُس وقت تک دانش مندانہ اور مثبت نتیجے کی حامل نہیں ہوسکتی جب تک وہ تعلیم کے بارے میں ایک واضح اور درست فلسفے سے آغاز نہ کرے۔
تاہم تعلیم جیسی پیچیدہ سرگرمی کا فلسفہ اتنا سیدھا سادہ نہ ہوگا جتنا کہ ٹیلی فون کرنے‘ چائے بنانے یا خط لکھنے کا فلسفہ ہے۔ جب معلّم اُوپر والے تین سوالات کے واضح اور درست جواب تلاش کرنے کی مخلصانہ کوشش کرے گا تو اُس کے سامنے مندرجہ ذیل نوعیت کے دیگر سوالات ہوں گے:
٭ تعلیم کا وہ مقصد کیا ہے جو لازماً ایک معلّم کے پیشِ نظر ہوگا؟
٭ اگر تعلیم کا مقصد ایک خاص قسم کے فرد کو وجود میں لانا ہے تو وہ قسم کیا ہے؟
٭ وہ کیا شے ہے جو ایک قسم کے فرد کو دوسری قسم (کے فرد) سے مختلف بناتی ہے؟
٭ وہ کیا شے ہے جو ایک قسم کے فرد کو دوسری قسم (کے فرد) کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ بنا دیتی ہے؟
٭ اَچھی اور بری اِقسام کے افراد کے مابین امتیاز کرنے کے لیے معیار کیا ہے؟
٭ وہ بہترین قسم کا فرد کیا ہوتا ہے جو ایک معلّم ممکنہ طور پر وجود میں لا سکتا ہے؟
٭ اِس قسم کے فرد کو کیسے پہچانا جاسکتا ہے؟
٭ اُس کے علم‘ مہارتوں‘ عادات‘ رویوں‘ پسند و ناپسند‘ خیالات و آراء‘ عقائد و تصورات‘ اغراض و مقاصد‘ محرکات و معیارات‘ توقعات اور خواہشات کی خوبی کیا ہوتی ہے؟
٭ ایک معلّم اِس قسم کے فرد کو وجود میں لانے کے لیے کیا اقدام لازماً کرے گا؟
تعلیم افراد کو اُس (حالت) سے مختلف بنا دیتی ہے کہ جس (حالت) میں وہ تعلیم کے بغیر ہوتے ہیں۔ تا ہم کیا یہ فرق خارجی سطح پر فرد کی تشکیل و تغیر کے نتیجے میں رونما ہوتا ہے یا باطنی سطح پر فطری نشوونما اور ترقی کے نتیجے میں واقع ہوتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں کیا تعلیم کی بنیاد فطری محاسن پر ہے یا یہ مصنوعی لوازمات پر انحصار کرتی ہے؟ کیا یہ فطری میلانات کی اعانت کرنے کا عمل ہے یا اُن پر غالب آنے اور خارجی دبائو کے تحت حاصل شدہ عادات و اطوار کو اُن کی جگہ دینے کا عمل ہے؟ اگر تعلیم کی بنیاد فطری محاسن پر ہے اور اِس کا قصد فطری میلانات کی اعانت کرنا ہے تو اُن سے تعلیم کیسے ممکن ہوتی ہے اور معلّم اُن کی اعانت کیسے کر سکتا ہے؟ اگر تعلیم باطنی سطح پر فطری نشوونما کا عمل ہے تو انسان میں وہ ذات کون سی ہے جو تعلیم کے نتیجے میں نشوونما پاتی ہے؟ اِس ذات کے تشکیلی عناصر اور اوصاف و خصوصیات کیا ہیں؟ اِس کی بھرپور نشوونما کی شرائط کیا ہیں؟ تعلیمی نشوونما کا عمل کس طرح واقع ہوتاہے؟ کیا اِس نشوونما کا کوئی فطری رخ یا کوئی فطری حد یا منزل ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا اِس نشوونما کے غلط اہداف کی جانب گمراہ ہوجانے کا کوئی خطرہ ہے؟ وہ اسباب و حالات کیا ہوتے ہیں جو ایک فرد کی تعلیمی نشوونما کو غلط راستے پر لگا دیتے ہیں؟ کیا تعلیمی نشوونما کے راہِ راست سے ہٹنے کے باعث کسی فرد کی درست تعلیمی نشوونما پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا اِس سے اُس کے علم‘ مہارتوں‘ عادات‘ رویوں‘ پسند و ناپسند‘ عقائد و آراء‘ اغراض و مقاصد‘ توقعات و خواہشات میں کوئی فرق آتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اِس فرق کی نوعیت کیا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک فرد کی درست تعلیمی نشوونما کے لیے کون سے حالات سازگار ہوتے ہیں؟ ہم ایسے حالات کیسے پیدا کرسکتے ہیں؟
قوموں کے نظام ہائے تعلیم ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ کیا یہ تمام نظام ہائے تعلیم‘ تعلیم دینے کی ایک جیسی استعداد رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو کچھ تعلیمی نظاموں میں دوسروں کی نسبت تعلیم دینے کی استعداد کم کیوں ہوتی ہے؟ ہم اُن کے نقائص کیسے دور کرسکتے ہیں اور اُنہیں مکمل طور پر تعلیمی بنا سکتے ہیں؟ ہم کیسے ایک مکمل طور پر تعلیم دینے کی استعداد رکھنے والا نظام یا مثالی تعلیمی نظام وجود میں لا سکتے ہیں؟ عصرِ حاضر میں مختلف اسالیب ِ تعلیم کی قدر و اہمیت کیا ہے؟ ایک مکمل طور پر تعلیم دینے کی استعداد رکھنے والے نظامِ تعلیم میں درسی کتاب‘ اُستاد‘ کھیلوں‘ اسکول کے عمومی ماحول نیز اسکول سے باہر موجود حالات کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ایک فرد کو اُس کی تعلیمی نشوونما کی مختلف سطحوں پر کون سے مضامین اور مہارتیں سکھائی جانا چاہئیں اور کیوں؟
تعلیم کا روز مرہ کے تجربے سے کیا تعلق ہے؟ اگر تعلیمی نشوونما تجربے کا نتیجہ ہے تو خود تجربے کی ماہیت کیا ہے؟ نیز تجربہ کیوں اور کیسے تعلیمی نشوونما پر منتج ہوتا ہے؟ اِس سوال کے جواب کو ایک معلّم کے اُس انتخاب پر کس طرح اثر انداز ہونا چاہیے جو (انتخاب ایک معلم) اپنے شاگردوں کے لیے سماجی ماحول‘ موادِ تدریس اور درسی طریقوں کا کرتا ہے۔ اگر اِس بات پر یقین کرنا درست ہے کہ تعلیم کی اچھائی کا انحصار تجربے کی اَچھائی پر ہے تو تعلیمی قدر و قیمت کے لیے تجربے کا معیار کیا ہے؟
تعلیم کا کردار سے کیا تعلق ہے؟ انسانی فطرت کے کون سے قوانین کردار کی نشوونما کرتے ہیں؟ کیوں ایک فرد یا قوم کا کردار دوسرے فرد یا قوم کے کردار سے مختلف ہوتا ہے؟ درست کردار کی کیا نشانیاں ہیں؟ معلّم اس امر کو یقینی بنانے کے لیے کیا کر سکتا ہے کہ اُس کے شاگرد نے ایک درست کردار اختیار کر لیں ؟ وغیرہ وغیرہ۔
ایک معلّم جو اِن سوالات کے جواب نہیں دیتا اور اپنی تعلیمی سعی شروع کرنے سے پہلے اِس اَمر کو یقینی نہیں بناتا کہ اِن سوالات کے حوالے سے اُس کے جواب حتی الوسع درست ہوں‘ وہ تعلیم کے اولین اصولوں کو نظر انداز کرتا ہے اور اِس طرح اپنی سعی میں کبھی کامیاب ہونے کی اُمید نہیں کرسکتا۔ ایک سماجی طبقے کی تعلیم پر مزید خرچ کرنے سے ‘ اِس کے اسکولوں اور کالجوں کی تعداد میں اضافہ کرنے سے‘ ہر کلاس میں مضامین اور درسی کتابوں کی تعداد میں اضافہ کرنے سے اور تعلیم میں توسیع و شہرت کو ہدف بنانے والے اِس نوع کے اقدامات سے جو اِس وقت پوری دنیا میں معلّم کے حق میں سازگار معلوم ہوتے ہیں‘ معلّم کے اُس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی جس کا باعث اِن اُصولوں سے اُس کی ناواقفیت بنتی ہے۔ ایک موٹر چلانے والا جو سفر پر روانہ ہوتا ہے‘ اُسے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے لازماً اپنی منزل کا اور اُس راستے کا علم ہونا چاہیے جو اس (منزل) تک رہنمائی کرتا ہے۔ اگر وہ غلط راستے پر سفر کررہا ہے تو اپنی رفتار دوگنا یا تین گنا بھی کرلے تو وہ اپنی منزل سے ذرا بھی قریب نہ ہوگا بلکہ یقیناً اور بھی زیادہ تیزی سے اِس سے مزید دور ہٹتا جائے گا۔
بدقسمتی سے اِن میں سے کچھ سوالات پر اَب تک کسی بھی جدید تعلیمی فلسفی نے قطعاً توجہ نہیں دی ہے۔ مثال کے طور پر وہ (سوالات) جن کا تعلق مختلف ممالک اور قوموں کے تعلیمی نظاموں میں بنیادی اختلافات کے اسباب سے اور ایک مثالی نظام یا ایک مکمل نظامِ تعلیم کے اوصاف و خصوصیات سے ہے۔ اوپر والی فہرست میں کچھ اور سوالات ہیں کہ جن پر بلاشبہ بہت سے تعلیمی فلسفیوں نے توجہ دی ہے مگر (جیسے کہ میں نے اِس کتاب میں وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے) اُن کے جوابات علمی و عقلی لحاظ سے بے جوڑ اور بے ربط ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جوابات جن کا تعلق مقاصد ِتعلیم سے ہے۔ یہ بات بالعموم تسلیم کی جاتی ہے کہ جہاں تک مقصد ِتعلیم کا تعلق ہے جدید تعلیمی فلسفی مخمصے کی صورتِ حال میں ہیں۔ چنانچہ ٹی وی جیفریز (T.V.Jaffrays) اپنی کتاب
An Inquiry into The Aims of Education میں لکھتا ہے: ’’جدید تعلیم کی سب سے زیادہ خطرناک کمزوری اِس کے مقاصد کے متعلق بے یقینی ہے‘‘۔ (پٹ مین‘ لندن‘ ۱۹۵۰ء)
تاہم اِس فہرست میں اَور بھی سوالات ہیں جن کے بِلا استثنا تمام جدید تعلیمی فلسفیوں نے درست جوابات دیئے ہیں مگر اِن میں سے کسی نے بھی اپنے نظریات کی تشکیل کرتے ہوئے اِن (سوالات) کے جوابات کے مکمل مضمرات کی نہ تو تفصیلات طے کی ہیں اور نہ (اُنہیں) مدّ ِنظر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اِس طرح کا سوال کہ آیا تعلیم انسان کو بدلنے کا عمل ہے یا اُس کی نشوونما کا عمل ہے؟ اگرچہ اِن میں سے سب اِس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ تعلیم نشوونما کا عمل ہے‘ پھر بھی بدقسمتی سے اِن میں سے سب اِس سادہ سی حقیقت کو نظر انداز کردیتے ہیں کہ کسی ذی حیات وجود میں نشوونما کے باطنی ہیجان کے بغیر کوئی بھی نشوونما چاہے حیاتیاتی ہو یا نفسیاتی‘ ممکن نہیں ہے۔ اگرچہ بے شک اُنہوں نے اِ س اَمرِ واقعہ پر زور دیا ہے کہ تعلیم نشوونما کا عمل ہے تاہم اُنہوں نے فطری تقاضے (urge) کو مکمل طور پر نظر انداز کردیا جو اِس نشوونما کا (اصل )سبب ہے۔ نتیجتاً وہ اِس ہیجان کو اَپنے مطالعے کا ہدف بنانے میں ناکام ہو گئے اور یوں وہ اِس ہیجان کی خوبیوں‘ خصوصیات اور مقاصد کو جاننے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ وہ یہ جاننے میں بھی ناکام رہے ہیں کہ فطرت میں اِس ہیجان کا اظہار کس انداز اور سمت میں ہوتا ہے! اِس کی تاریخ کیا ہے؟ ارتقا میں اِس کا کردار کیا ہے ؟کس صورت میں اِسے بالعموم لوگوں کی علمی‘ اخلاقی‘ روحانی اور جمالیاتی سرگرمیوں اور تصورات سے مربوط سمجھا جاتا ہے؟ نیز وہ کون سے حالات ہوتے ہیں جب اِس کے راستے میں رکاوٹ حائل ہوتی ہے یا یہ غلط راہ اختیار کر سکتا ہے اور کن حالات میں اِس کے زیادہ سے زیادہ اظہار اور تشفی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں تعلیمی فلسفے کی ترقی کا راستہ بری طرح سے روکا گیا اور اِسے غلط راہ پر ڈالا گیا‘ یہاں تک کہ آج تعلیمی فلسفہ تعلیم کے متعلق پوچھے جانے والے اِس انتہائی بنیادی سوال کا جواب دینے کے بھی اہل نہیں ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے! قدرتی بات ہے کہ ایسے تعلیمی نظام جو اِس اَدھورے فلسفہ ٔ تعلیم کی بنیادوں پر تشکیل پائے وہ ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی شخصیتوں کو مسلسل اور ہمہ جہت نشوونما فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ اِس طرح کی جانے والی غفلت کا ارتکاب ایک ایسا عالم گیر مسئلہ ہے جس کے حجم میں قریباً روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔
میں نے اِس کتاب میں کوشش کی ہے کہ مذکورہ بالا تمام سوالوں کے ممکنہ حد تک اطمینان بخش جواب دوں اور مجھے پتا چل گیا ہے کہ تمام ممکنہ جوابات میں سے سب سے زیادہ اطمینان بخش جواب وہی ہے جو ازروئے دانش اِس حقیقت سے اَخذ ہو سکتا ہے کہ جسے تمام جدید ماہرین ِ تعلیم پہلے ہی سے قبول کرتے ہیں‘ یعنی تعلیم ایک نشوونمائی عمل ہے۔ چنانچہ یہی حقیقت (جو اَپنے بنیادی تعلیمی سچائی کے ہونے کے حق میں بے پناہ شہادت رکھتی ہے) اِس کتاب کا مرکزی خیال ہے اَور اِس کے تمام دیگر تصوّرات اِس ایک خیال ہی کے ضمنی مفاہیم یا نتائج ہیں۔ اِن ضمنی مفاہیم اور نتائج میں سے ایک نمایاں ترین اور اہم ترین ضمنی مفہوم یا نتیجہ یہ ہے کہ اِنسان تعلیمی نشوونما کا فطری طورپر تقاضا رکھتا ہے‘ اور یہ کہ کوئی فرد تعلیمی اعتبار سے بھرپور حد تک نشوونما پا سکا ہے یا نہیں اِس اَمر کا انحصار اِس حقیقت پر ہے کہ وہ اِس فطری تقاضے کا بھرپور حد تک اظہار اور اِس کی تشفی کر سکا ہے یا نہیں۔ لہٰذا ایک کوشش کی گئی ہے کہ اِس فطری تقاضے کی صفات و خصوصیات کا بالتفصیل مطالعہ کیا جائے اَور اِن (صفات و خصوصیات) کی روشنی میں جس حد تک ممکن ہو سکے انسانی شخصیت کی نشوونما میں حائل نفسیاتی عمل کا جائزہ لیا جائے۔ اِس فطری تقاضے کی نمایاں ترین خصوصیات یہ ہیں کہ یہ کسی نصب العین کی محبت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اِسے صرف کامل اور اعلیٰ حسن کے نصب العین کی محبت ہی سے مستقل طور پر اور مکمل طور پر مطمئن کیا جا سکتا ہے اور یہ فطرتِ اِنسانی کا ایک ایسا خود مختار تقاضا ہے جو نہ تو انسان کی بنیادی معاشی ضرورتوں یا حیوانی جبلتوں کا خادم ہے اور نہ ہی (اُن کی) پیداوار ہے بلکہ جو اِس کے برعکس خود اَپنے اظہار اور تشفی کے لیے اپنی بنیادی معاشی ضرورتوں اور حیوانی جبلتوں پر حکمرانی کرتا اور (اُنہیں) قابو میں رکھتا ہے۔
جدید ماہر تعلیم پہلے ہی سے اِس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ تعلیم کے بہترین اور درست ترین طریقہ ہائے کار کے علم کے لیے صرف انسانی فطرت ہی قابلِ اعتبار رہنما ہے۔ چنانچہ سر جیمز راس (Sir James Ross) لکھتا ہے:
’’ یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ تعلیمی طریقۂ کار میں تمام تر حالیہ ترقی‘ یعنی یہ بات کہ درحقیقت درست طریقۂ کار کا خاص مثالی نمونہ بچے کی فطرت کے حقائق پر مبنی ہوتا ہے‘ فطرت پسندی (Naturalism) کے تصور کی دین ہے۔ جب تعلیم کے وسائل اور طریقے زیرِ غور ہوں تو یہی نقطۂ نظر درست معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی فطرت معلوم کی جائے اور ابتداً جیسا کہ وہ ہے ویسے ہی اُس کے ساتھ چلا جائے۔‘‘
یہ نتیجہ واضح طور پر اِس اَمر پر دلالت کرتا ہے کہ تعلیم مکمل طور پر ایک فطری عمل (natural process) ہے۔ تاہم کسی عمل کو اُس کے اُس ہدف یا مقصد سے جدا نہیں کیا جاسکتا کہ جس طرف یہ بہر صورت گامزن ہوتا ہے۔ ایک فطری عمل ایک ہی فطری ہدف کا حامل ہوتا ہے اور وہ فطری ہدف (جس حد تک کہ یہ عمل کا درست فطری ہدف ہے) لازماً صرف ایک ہی ہوگا نہ کہ متعدد‘ گو اِس کے اجزائے ترکیبی یا عناصر کے طور پر بہت سے اہداف ہوسکتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہمیں اِس اگلے نتیجے تک پہنچنے کے قابل بنا دیتا ہے کہ انسانی فطرت ہی یقیناً تعلیم کے بہترین اور زیادہ سے زیادہ درست ہدف یا مقصد کے علم کے لیے قابلِ اعتماد رہبر ہے اور تعلیم کے اِس ہدف یا مقصد کو پانے کے لیے ہم لازماًویسے ہی اَپنے کام کی ابتدا کریں گے جیسے کہ انسان ہے نہ کہ اِس طور کہ جس طور کوئی خاص فرد یا طبقہ اُسے چاہتا ہے کہ (وہ) ہو۔ یوں انسانی فطرت میں لازماًکوئی ایسی شے ہوگی گویا شعورِ انسانی کی کوئی فطری استعداد جو ایک فطری عمل کے طور پر‘ اندر سے قدرتی نشوونما کی ایک روش کے طور پر‘ تعلیم کے ہدف یا مقصد کا تعین کرتی ہے۔ میں نے اِس کتاب میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یقینا ًانسانی شعور میں اِس قسم کی استعداد فی الواقع موجود ہے اور یہ کہ اعلیٰ و اکمل حسن کے حامل نصب العین سے محبت کرنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے‘ایک ایسا فطری تقاضا جو بالآخر اُس کی تمام خواہشات اور سرگرمیوں کو قابو میں رکھتا اور (اُن پر) حاوی ہوتا ہے۔ چوںکہ یہ نقطۂ نظر مکڈوگل (McDougall) ‘ فرائڈ (Freud)‘ ایڈلر (Adler) اور مارکس (Marx) کے اُن نفسیاتی نظریوں سے متصادم ہے جو اِس وقت دنیا کے ایک یا دوسرے علمی حلقے میں بہت مقبول ہیں اِس لیے یہ بات ضروری محسوس ہوتی ہے کہ اِن نظریوں کی بنیادی کمزوریوں اور بے ربطیوں کو واضح کرنے سے اِس (نقطۂ نظر) کو حق بجانب ثابت کیا جائے۔
وہ ماہرِ تعلیم جو اِس نقطۂ نظر سے اتفاق کرتا ہے کہ تعلیم اندر سے قدرتی نشوونما کا عمل ہے اُسے بلاشبہ اِس کے نتائج سے مکمل طور پر اتفاق کرنا پڑتا ہے بشرطیکہ اِس اَمر پر یقین کرنے کی معقول دلیل ہو کہ اُن (نتائج) کا صحیح طور پر استخراج کیا گیا ہے۔ جہاں تک اِس نقطۂ نظر کے نتائج کا تعلق ہے جن کا استخراج کیا گیا ہے‘ اِس اَمر کا ذکر کیا جاسکتا ہے کہ وہ (نتائج) ایک خاندان یا ایسے باہم مربوط حقائق کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو ایک دوسرے سے اور مجموعی طور پر تمام دیگر (حقائق) سے منطقی تائید و تقویت حاصل کرتے ہیں۔ اِس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اِن حقائق میں سے کسی ایک کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں دیگر تمام حقائق کو بھی قبول کرنا پڑے گا اَور یہ اَمر اُن کے درست ہونے کا ثبوت بن جاتا ہے کہ وہ ہم آہنگ ہیں اور نشوونمائی عمل کے طور پر نہ صرف تعلیم کے رائج اور مسلّمہ اَمرِ واقعہ بلکہ تعلیم کے رائج اور مسلمہ طریقوں کی اساسی عقلی بنیاد کی توضیح کرتے ہیں یعنی اُن طریقوں کی جنھیں جدید ماہرین ِ تعلیم نے آزمایا ہے اور اطمینان بخش پایا ہے۔
یہ کتاب کسی خاص قوم‘ مذہب‘ ملک یا نظریہ کی خواہشات اور ضرورتوں کو مدّ ِ نظر رکھ کر نہیں لکھی گئی ہے۔ (اصل) مقصد یہ ہے کہ انسانی فطرت کے قوانین کے تحت انسانی شخصیت کی نشوونما جس انداز میں ہوگی اور جس انداز میں ہوتی ہے‘ اُس کا مطالعہ غیر جذباتی اور غیر جانب دارانہ انداز میں کیا جائے۔ انسانی فطرت ہر کہیں ایک جیسی ہی ہے۔ چنانچہ ایک فرد جو اِس اَمر کی خواہش رکھتا ہے کہ تعلیمی لحاظ سے بھرپور حد تک اَور درست سمت میں نشوونما پائے ‘ اُس کے لیے ایک ہی طرح کی تعلیمی ضروریات اور تقاضے ہوں گے اَور اُس کی ایک ہی انداز میں تعلیم ہوگی۔ اِس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آیا وہ اَمریکہ‘ روس یا برطانیہ سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اَور ملک سے یا آیا وہ ایک عیسائی ہے‘ ایک ہندو ہے یا ایک مسلمان یا کسی اَور مذہب کا پیروکار۔
محمد رفیع الدین
باب اول
جدید ماہرین تعلیم کی اُلجھن
دراصل کسی بھی انسانی سرگرمی کی طرح ایک صحیح نظریۂ تعلیم کی بنیاد انسانی فطرت کے درست نظریہ ہی پر رکھی جا سکتی ہے۔ بدقسمتی سے جدید دانشوروں کا ‘ خود اُن کے اَپنے اعتراف کے مطابق، انسانی فطرت سے متعلق علم بہت پس ماندہ ہے ۔ایک ممتاز ماہرِ نفسیات سکنر (Skinner) اپنی کتابScience and Human Behaviourمیں رقم طراز ہے:
’’سائنس میں بے ربط انداز میں ارتقا پایا جاتا ہے۔ اِس نے بعد میں پیش آنے والے معاشرتی مسائل کے حوالے سے تیاری کیے بغیر بے جان فطرت پر ہمارے اختیار کو توسیع دی ہے… فطرت سے متعلق علم کو بڑھاتے جانے میں کوئی حکمت نہیں ہے تاوقتیکہ اِ س میں انسانی فطرت کے علم کا اَچھا خاصا حصہ شامل نہ ہو کیوں کہ اِسی صورت میں نتائج سمجھ داری کے ساتھ کام میں لائے جائیں گے۔‘‘
نوبل انعام یافتہ الیکسز کیرل (Alexis Carrol) اپنی کتاب Man: The Unknownمیں رقم طراز ہے:
’’ایسے اِداروں کا قیام تعمیر ِ انسانیت کا تقاضا ہے جن میں تعلیم کے مختلف مکاتیب ِ فکر کے تعصبات کے بجائے ذہن و بدن کی صورت پزیری قوانین ِ قدرت کے مطابق ہو سکے۔ سچ یہ ہے کہ ہمارے تمدن نے زندگی بسر کرنے کے حالات کچھ ایسے بنا دیئے ہیں جو حیات کو ناممکن بنا دیتے ہیں۔ آج کے شہر کے باسیوں کی فکر اور پریشانیاں سیاسی ‘ معاشی اور سماجی اِداروں کی پیداوار ہیں۔ تاہم سب سے بڑھ کر یہ خود اپنی کمزوریوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اِس برائی کا واحد ممکنہ علاج اَپنے نفوس کا بہت زیادہ گہرا علم ہے۔‘‘
ایک اور ممتاز ماہر نفسیات میکڈوگل(McDougall) اپنی کتابWorld Chaosمیں رقم طراز ہیں:
’’انسانی فطرت سے ہماری عدم واقفیت نے تمام سماجی علوم کی ترقی کی راہ روکی ہے اَور اب بھی (اِس راہ میں) مزاحم ہے۔ اس طرح کے علوم ہمارے زمانے کی اشد ضرورت ہیں۔ اِن کی کمی کے باعث ہمارے تمدن کو زوال اَور غالباً مکمل انہدام جیسے سنگین نوعیت کے خطرات ہیں۔‘‘
’’ہم نفسیات ‘ معاشیات ‘ سیاسیات ‘ اُصولِ قانون ‘ سوشیالوجی اَور بہت سے دیگر من گھڑت علوم کی بات کرتے ہیں تاہم سیدھی سادھی حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام خوش نما نام محض ہمارے علم میں واقع بڑے بڑے خلائوں کی نشان دہی کرتے ہیں … وہ خلا مبہم انداز میں ایسے وسیع اُجاڑ خطوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو اَبھی دریافت ہی نہیں ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے تمدن کو قائم و برقرار رہنا ہے تو ایسے خطوں کو لازمی طور پر ضابطے میں لانا ہوگا۔‘‘
’’میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اَپنے تمدن کے توازن کو بحال کرنے کے لیے ہمیں انسانی فطرت اَور سماجی زندگی کا اِس سے کہیں زیادہ (ایک قاعدے کے تحت ترتیب پایا ہوا یا سائنسی) علم رکھنے کی ضرورت ہے جتنا کہ اَبھی ہم رکھتے ہیں۔‘‘
’’اِس وقت اَپنے تمدن کی خوف ناک اور ہر لحظہ بڑھتی ہوئی خطرناک صورتِ حال کے علاج کی یہی ایک سبیل ہے۔ ہمیں یقینی طور پر موثر انداز میں اَپنے سماجی علوم کو انسانی فطرت اَور اِس کی سرگرمیوں کے حقیقی علوم کی صورت میں نشوونما دینا ہوگی۔ سماجی علوم کے لیے اساس کی کھوج لگانا اَور ایک طریقۂ کار مہیا کرنے کے مشکل کام کو انجام دینے کی جتنی آج اشد ضرورت ہے اتنی پہلے کبھی نہیں تھی۔‘‘
’’تو پھر عملی صورت میں علاج کیا ہے؟ میں مختصر ترین انداز میں اپنا جواب اِس رائے کو پیش کرتے ہوئے دے سکتا ہوں کہ اگر میں ایک آمر ہوتا تو کیا کرتا … میں ہر طرح سے کوشش کرتا کہ اَپنے تمام انتہائی مقتدر دانشوروں کا رخ طبیعی علوم سے انسانی اَور سماجی علوم کی تحقیق کی جانب موڑ دیتا۔‘‘
موجودہ علمی دنیا کی انسانی فطرت سے متعلق جس بے خبری پر یہ مصنّفین تاسف کا اظہار کرتے ہیں ‘ اُس کی واضح جھلک جدید ماہرین ِ تعلیم کے تعلیمی نظریات میں پائی جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سچائی ہمیشہ فی نفسہٖ اَور دیگر تمام سچائیوں سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ یہ سچ ہی ہے جو دوسرے سچ کا دفاع اور تائید کر سکتا ہے‘ اَور ہر صداقت کی تائید و دفاع دوسری صداقتیں کرتی ہیں۔ اُسی فلسفے کو فلسفے کا نام دیا جاسکتا ہے جو ایک دوسرے کی طرف داری کرنے والی صداقتوں کا نظام یا کنبہ ہو۔ وہ تمام صداقتیں جو اِس کنبے سے باہر ہوتی ہیں‘ اِس (کنبے) سے ایک رشتہ رکھتی ہیں اَور یہ کنبہ اُن سے ایک رشتہ رکھتا ہے کیوں کہ وہ اِس سے میل کھاتی ہیں۔ جب ایک نئی صداقت کا انکشاف ہوتا ہے تو اِس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اَورکنبہ اِسے اپنے اندر سمو لیتا ہے کیوں کہ اِس کی اصل جگہ اِسی میں ہوتی ہے۔ اِس کے برعکس جب کوئی جھوٹ اِس میں داخل ہوتا ہے تو وہاں موجود تمام صداقتیں اِسے پیچھے دھکیلتی ہیں اور اِس طرح (وہ) اپنے قدم نہیں جما پاتا۔ اگر ہم کسی جھوٹ کا ------- جو بے شک ہمیشہ کسی سچائی کی آمیزش کے ساتھ پایا جاتا ہے ------- دفاع صداقتوں کے نظام کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں تو صداقتیں ہمارا حکم بجا لانے سے انکار کر دیتی ہیں۔ نیز نظام کے کئی ایک مقامات کے ربط و ہم آہنگی میں خرابی پیدا ہوتی ہے جس سے منطقی تناقضات اور تضادات جنم لیتے ہیں۔ تعلیم کا درست فلسفہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو باطنی طور پر مربوط اور (ظاہری) وجود کے تمام مسلمہ حقائق سے انتہائی مناسبت رکھتا ہو۔ اگر یہ اِس شرط پر پورا نہیں اُترتا تو ہم اِس کے کسی بھی حصے کی معقولیت کے بارے میں پُر اعتماد نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ بروبیکر (Brubacher) اپنی کتاب Modern Philosophies of Education میں لکھتا ہے:
’’خاص طور پر کسی کلّی ہم آہنگی کی روشنی ہی میں کسی انفرادی موقف کو یقینی بنایا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی موقف دیگر (مواقِف) سے ٹکراتا ہے تو پھر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہیں موجود کمزوری کے مقابل اَپنے آپ کو چوکس رکھے۔‘‘
زمانۂ حال میں کوئی فلسفہ ٔ تعلیم ایسا نہیں ہے جو درست فلسفہ ٔ تعلیم کے اِس بیانیہ کا مکمل طور پر جواب دیتا ہو۔ جدید ماہرین ِ تعلیم بدحواس اور ابہام کا شکار ہیں اَور اُنہوں نے جو تعلیمی فلسفے دیے ہیں وہ خطرناک علمی رخنوں اور تناقضات سے پُر ہیں۔ اِن فلسفوں کا تنقیدی جائزہ لینے والا کوئی بھی شخص محسوس کرسکے گا کہ یہ بیان کس قدر درست ہے۔ آئیے مثال کے طور پر سرپرسی نن (Sir Percy Nunn) ‘ ڈاکٹر جان ڈیوی (Dr. John Dewey) ‘ اور سرجیمز راس (Sir James Ross) کے تعلیمی فلسفوں کا جائزہ لیں‘ (یہ وہ لوگ ہیں) جو دورِ حاضر کے بااثر اَور ممتاز ترین ماہرین ِ تعلیم میں شمار ہوتے ہیں۔
پرسی نن کا تعلیمی فلسفہ (Educational Philosophy of Percy Nunn)
سر پرسی نن اپنی بات کا آغاز اُن ماہرین ِ تعلیم کے خیالات پر تنقید سے کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد ’’کردار سازی‘‘ یا’’ مکمل زندگی کے لیے تیار کرنا‘‘ یا ’’ایک صحت مند جسم میں صحت مند دماغ پیدا کرنا‘‘ ہے۔ وہ بجا طور پر نشان دہی کرتا ہے کہ گو تعلیم کے مقصد کے حوالے سے اِن بیانات میں سے ہر بیان اپنی جگہ پر درست ہے تاہم مبہم ہے اور بہت سی توضیحات کے لائق ہے۔ وہ لکھتا ہے:
’’یہ سب باتیں اُس وقت تک ہی تسلی بخش معلوم ہوتی ہیں جب تک اِس معاملے کی مزید چھان بین نہ کریں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ (تعلیم) کس قسم کی کردار سازی کی خواہش مند ہے ‘ مکمل زندگی (کے تصور) میں کون سی سرگرمیاں شامل ہیں اور ایک صحت مند دماغ کی کیا علامتیں ہیں۔ پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ تعلیم کا ایک آفاقی مقصد بیان کرنے کے حوالے سے اِن کوششوں کی کامیابی بڑی حد تک فریب آمیز ہے۔ خاص طور پر اِس حقیقت کے باعث کہ ہر شخص اُن کی توضیح جس طرح چاہتا ہے‘ وسیع حدود میں رکھ کر کرتا ہے۔ Aکے لیے جو تصور شائستہ کردار کا ہے‘ B کے لیے مضحکہ خیز یا صاف گوئی سے کام لیں تو تو ہین آمیز ہونے میں بدل جاتا ہے۔ جسے C ایک مکمل زندگی سمجھتا ہے‘ D کے لیے روحانی موت ہوگی۔ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ‘ جس وقت کہ E (اِس نصب العین کا) احترام کرتا ہے F (اِس سے) ایسے ہی نفرت کرتا ہے جیسے کہ ایک وحشی شخص کے جسم میں مقیم مہذب انسان کی روح اُس سے نفرت کرتی ہے۔‘‘
اس کے بعد مصنف کوشش کرتا ہے کہ اَپنے آپ کو مقصد ِتعلیم کی ایسی تعریفوں سے بالاتر رکھتے ہوئے ہمیں یہ بتائے کہ تعلیمی منصوبہ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو اِس مقصد سے جڑے ہوئے ہوں اَور قابل ہوں تعلیم اُنہیں انفرادی امتیاز کے بلند ترین مقام تک پہنچائے۔مگر یہ بیان گو اِس میں شک نہیں کہ اپنی جگہ اتنا ہی درست ہے جتنا کہ مذکورہ بالا بیانات میں سے کوئی بھی بیان ‘ تاہم مبہم اور گوناگوں توضیحات کے اہل بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ اُن میں سے کوئی بیان ہو سکتا ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ :
(۱) انفرادی امتیاز کے کیا معنی ہیں؟ اِس کو اِس کی ضد سے کیسے الگ کیا جا سکتا ہے؟
(۲) انفرادی امتیاز کی وہ بلند ترین سطح کیا ہے جس کا کہ ایک شخص اہل ہو سکتا ہے؟
(۳) کس طرح کوئی جان سکتا ہے کہ کوئی انفرادی امتیاز کی اُس سطح کی تحصیل کی جانب جانے والی راہ پر ہے یا نہیں؟
مصنف نے دوسروں کی مقصد ِ تعلیم کی تعریف پر جو تنقیدکی ہے اُس (تنقید) کا اتنا ہی اطلاق خود اُس کی اپنی تعریف پر ہوتا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ لوگوں کے انفرادی امتیاز کے بارے میں خیالات جتنے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اُتنے ہی اُن کے خیالات کردار سازی ‘ مکمل زندگی یا صحت مند جسم میں صحت مند دماغ کے حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔وہ مقصد ِ تعلیم پر مزید بحث کرتے ہوئے رقم طراز ہے:
’’ہر تعلیمی منصوبہ لازماً ہر قدم پر حیات سے مربوط ہوتا ہے۔ چنانچہ کوئی بھی تعلیمی مقاصد جو اتنے ٹھوس ہوں کہ واضح راہنمائی فراہم کرسکیں ‘ حیات کے نصب العینوں کے ساتھ ہم رشتہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یونانی تصورِ حیات اور پیور ٹین اصلاح پسندوں (Puritan Reformers) کے تصوّرِ حیات کے مابین موافقت پیدا نہ ہو سکے تو اُن سے جنم لینے والے تصوراتِ تعلیم کے مابین ہم آہنگی تلاش کرنا بے سود ہے۔‘‘
اِس کا مطلب یہ ہوا کہ سرپرسی نن اَچھی طرح سمجھتا ہے کہ :
(ا) مقصد ِ تعلیم کو بجائے خود زندگی کا نصب العین بننا پڑتا ہے۔
(ب) جب تک ہمارا مقصد ِ تعلیم اَچھا خاصا ٹھوس نہ ہو اُس وقت تک یہ ہمیں کوئی متعین راہنمائی مہیا کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا۔
(ج) زندگی کے (مختلف) نصب العینوں کی بنا پر مقاصد اَور تصورات ِ تعلیم (بھی) مختلف ہوسکتے ہیں۔
(د) ہر تصور ِ تعلیم زندگی کے کسی نصب العین کی پیداوار ہوتا ہے اور زندگی کے ہر نصب العین کا اپنا تصور ِ تعلیم ہوتاہے۔
(ھ) ہمارا مقصد یا تصور ِ تعلیم اُس وقت تک درست نہیں ہو گا جب تک زندگی میں ہمارا نصب العین درست نہیں ہے۔
چنانچہ کوئی یہ توقع کرسکتا ہے کہ وہ (مصنف) زندگی کا ایک ایسا ٹھوس نصب العین تجویز کرے جو معلّم کو واضح راہنمائی فراہم کرنے والا ہو اور اُس سمت کی نشان دہی کرنے والا ہو کہ جس سمت ہی میں صرف بلند ترین انفرادی امتیاز کی نشوونما ہو سکے‘ مگر بدقسمتی سے ایسی صورتِ حال نہیں ہے۔ مصنف کااِس اَمر پر یقین ہے کہ تعلیم کو انفرادی امتیاز کی نشوونما کو مقصد بنانا چاہیے مگر اِس کا حیات کے کسی مخصوص یا متعین نصب العین سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے‘ اَور فرد کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ زندگی کے جس کسی نصب العین کو بہتر سمجھتا ہے اختیار کرے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے:
’’تعلیم کا ایسا کوئی مقصد آفاقی مقصد نہیں ہو سکتا اگر وہ زندگی کے کسی مخصوص نصب العین کے دعوے پر مشتمل ہو کیوں کہ (دنیا میں) جتنے افراد ہیں اُتنے ہی نصب العین ہیں۔‘‘
یہاں سر پرسی نن خود اَپنے آپ کو رد کررہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کیا اُس نے اوپر زندگی کے دو مختلف نصب العینوں -- یونانی اور پیورٹین -- کی طرف یہ کہتے ہوئے اشارہ نہیں کیا تھا کہ اِن میں سے ہر ایک لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے مشترک ہے؟ یہ سچ ہے کہ افراد کے گروہ میں سے ہر کوئی یکساں نصب العین مثلاً کمیونزم ‘ جمہوریت ‘ عیسائیت ‘ خدا ‘ انگریزی قومیت وغیرہ سے محبت کرتے ہوئے اپنی مخصوص تحدیدات اَور صلاحیتوں کے تحت اَپنے انداز میں گروہ کے مشترکہ نصب العین کے لیے جدوجہد کرے گا ‘تاہم اِس سے یہ کہنا تو نہیں بنتا کہ اُن میں سے ہر کوئی مختلف نصب العین رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سو شاعروں میں سے ہر کوئی ایک ہی موضوع مثلاً انگلینڈ کی محبت پر نظم لکھ لے۔ اِس میں کوئی شک نہیں کہ اِن نظموں میں سے ہر نظم دوسری نظم سے مختلف ہو گی‘ تاہم اِس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نظم کا موضوع بھی دوسری نظم کے موضوع سے مختلف ہوگا۔
دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص مصنف سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا انفرادی امتیاز یکساں طور پر ایک ایسے شخص میں جو زندگی کے یونانی نصب العین کا پیروکار ہے اور ایک دوسرے شخص میں جو زندگی کے پیورٹین نصب العین پر یقین رکھتا ہے ‘ بھرپور حد تک نشوونما پا سکتا ہے! اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ کیسے (ممکن) ہے کہ اُن کی تعلیم کے باوجود فرض اَور اخلاق سے متعلق اُن کےتصورات ایک دوسرے سے یکسر مختلف رہتے ہیں؟ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کون سے عوامل اِن کی نشوونما میں دوسرے کی نسبت ایک کے معاملے میں زیادہ دخل اندازی کرتے ہیں اَور وہ کون سا نصب العین ہے جو انتہائی حد تک انفرادی امتیاز کی نشوونما کو یقینی بنا سکتا ہے؟سر پرسی نن رقم طراز ہے:
ـ’’حقیقت یہ ہے کہ آزادی اگر تمام اعلیٰ اَچھائیوں کا سرچشمہ نہیں تو شرط (ضرور) ہے۔ اِس سے ہٹ کر فرض کوئی معنی نہیں رکھتا ‘ ایثارِ نفس کی کوئی قدروقیمت نہیں ‘ حاکمیت کا کوئی جواز نہیں۔‘‘
مگر وہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ آزادی کی کیا شرائط ہیں جن کی وہ تائید کرتا ہے۔ کیا آزادی یہ ہے کہ کسی مقصد کے لیے استعمال ہو یا یہ ایسی بے مہار آزادی ہے کہ جو لاقانونیت کی حد تک چلے جانے والی ہو؟ اگر یہ بے مہار آزادی نہیں ہے اَور زندگی کے عطا کردہ دائرہ عمل میں کام کرنا پڑتا ہے تو وہ دائرۂ عمل کیا ہے؟ کیا اِسے تخلیق کرنے اَور قائم رکھنے والے کسی نصب العین کے بغیر زندگی کا کوئی متعین دائرہ عمل ہو سکتا ہے؟ سر پرسی نن ایک اشارہ دیتا ہے کہ آزادی بے مہار نہیں ہو سکتی اور یہ کہ کسی فرد کو اپنا فرض اَدا کرنے کے لیے ‘ ایثار ِ نفس کرنے کا اہل ہونے کے لیے اَور حاکم کی اطاعت کے لیے لازمی طور پر آزاد ہونا ضروری ہے۔ با ایں ہمہ کیا ہم زندگی کا کوئی نصب العین رکھے بغیر فرض کا کوئی تصور رکھ سکتے ہیں ‘ کیا ہم اَپنے آپ کو کسی ایثارِ نفس کے لیے تیار کر سکتے ہیں اور کیا ہم کسی حاکم کی اطاعت کرسکتے ہیں؟
وہ زندگی کے کسی خاص نصب العین پر اصرار کرنے کے خلاف ہے۔ گویا وہ تعلیمی لائحہ عمل کو اِس کے مطابق بنانے کے خلاف ہے کیوں کہ اُس کا اعتقاد ہے کہ یہ بات فرد کی آزادی میں دخل اندازی کرنے اور یوں اُس کے شخصی امتیاز کی نشوونما میں دخل اندازی کرنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ وہ رقم طراز ہے:
’’ہم اَوّل تا آخر اِس موقف پر کھڑے رہیں گے کہ دنیا میں اگر کوئی اَچھائی راہ پاتی ہے تو وہ صرف اور صرف انفرادی سطح پر مرد و خواتین کی آزاد سرگرمیوں کے ذریعے ہی آتی ہے ‘اور یہ کہ تعلیمی عمل کو لازمی طور پر اِس سچائی کے مطابق تشکیل دیا جانا چاہیے۔‘‘
با ایں ہمہ کوئی شخص یہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تعلیمی نظام کو ہر نصب العین کے بیان سے آزاد رکھا جائے۔ اِس سوال کا واضح جواب یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے ۔متعلّم کو ہمیشہ کسی نہ کسی نصب العین کی براہِ راست یا بالواسطہ تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے۔ معلّم کی طرف سے اَپنے تعلیمی نظام کی بنیاد کے طور پر قصداً منتخب کردہ کسی مخصوص نصب العین کی غیر موجودگی میں بھی اُسے اِس اَمر کا یقین ہو سکتا ہے کہ اُس کے شاگرد کی انفرادیت کی نشوونما تمام نصب العینوں کے اَثر سے آزاد نہیں رہی ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ اسکول کی فضا میں ایک خاص نصب العین کا اثر شدّت سے سمایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ نصب العین قوم اَور ریاست کا نصب العین ہے۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ برطانوی قومیت (British Nationalism) ‘ فرانسیسی قومیت (French Nationalism) ‘ امریکیت (Americanism) ‘ قومی اشتراکیت (National Socialism) ‘ فسطائیت (Fascism) یا اشتمالیت (Communism) ہو۔ قومی نصب العین کا اَثر اسکول کی فضا میں سرایت کر جاتا ہے کیوں کہ یہ اُن لوگوں کا نصب العین ہے جو وسیع تناظر کی حامل تعلیمی پالیسی مرتب کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اِس کی تفصیلات تیار کرتے ہیں ‘ وہ لوگ جو حقیقت میں تعلیمی لائحۂ عمل تجویز کرتے ہیں ‘ وہ لوگ جو اِسے عملی جامہ پہناتے ہیں ‘ وہ لوگ جو تعلیمی اداروں کا نظم و نسق چلاتے اور نظم و ضبط قائم کرتے ہیں ‘ وہ لوگ جو درسی کتابیں لکھتے ہیں اَور وہ لوگ جو اُنہیں پڑھاتے ہیں۔ یوں اِس (سارے عمل) کا زندگی اَور اِس کی اقدار کے حوالے سے متعلّم کے کلی رویے پر ‘ گو تدریجی اَور نامحسوس انداز میں ‘ تاہم یقینی اور گہرا اَثر ہوتا ہے۔ یہ متعلّم پر ایک خوب صورت اَور درپردہ جبریا قہر کی صورت میں اَپنے آپ کو مسلط کیے رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ متعلّمین جو کسی ایسے تعلیمی لائحہ عمل کو اپنا لیتے ہیں جو ایک مخصوص قومی نصب العین کی پیداوار ہوتا ہے ‘ وہ اپنی اِس تعلیم کے نتیجے میں اَپنے دل میں دیگر تمام نصب العینوں کی محبت کو نکالتے ہوئے اِس (مخصوص قومی) نصب العین کی ایک زبردست محبت پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ سراسر قدرتی بات ہے۔سر پرسی نن خود تسلیم کرتا ہے:
’’ہر شخص (اِس اَمر کا) میلان رکھتا ہے کہ دوسروں کی تحریک سے اپنی زندگی کا نصب العین حاصل کرے۔‘‘
اِس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب تک ایک معلّم کسی ایسے تعلیمی نظام کو استعمال میں نہیں لا پاتا جو ایسے افراد کے ہاتھوں میں چلتا اَور اُن کا تخلیق کردہ ہو جو زندگی کا کوئی نصب العین نہیں رکھتے‘ اُس وقت تک وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اُس کا تعلیمی لائحۂ عمل کسی مخصوص نصب العین کے نمایاں اثر سے آزاد ہے یا یہ کہ اُس نے اَپنے متعلّمین کو آزادی دے رکھی ہے کہ وہ جس نصب العین کو پسند کرتے ہیں منتخب کرلیں۔ مگر وہ اِس نوع کا تعلیمی نظام کہاں حاصل کر سکتا ہے؟ جہاں کہیں کوئی قوم بستی ہے یا ریاست کی صورت میں منظم افراد کا ایک معاشرہ ہوتا ہے ‘اُسے اُس صورت میں منظم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی زندگی کا نصب العین لازماً ہو گا اور اُس کا تعلیمی نظام یقینی طور پر اُس نصب العین کی پیداوار ہو گا۔ نیز اِس نصب العین پر حق جتانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ (تعلیمی لائحۂ عمل) اُن لوگوں کو دیا جائے جو اِس (نصب العین) کے سامنے سرِ تسلیم خم کرتے ہوں۔ تاہم اگر متعلّمین کسی صورت اپنی تعلیم کے نتیجے میں زندگی کے کسی نصب العین سے یقینی طور پر محبت کرنے لگ جائیں تو بلاشبہ معلّم کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ اِس بات کا خیال رکھے کہ نصب العین مکمل طور پر اَچھا ہو اَور اس کی شمولیت شعوری اَور سائنسی طور پر منصوبہ بندی سے ہوئی ہو۔ اگر ‘ جیسے کہ سر پرسی نن یقین رکھتا ہے ‘ یہ ایک حقیقت ہے کہ ـ:
’’ہر شخص (اِس اَمر کا) میلان رکھتا ہے کہ دوسروں کی تحریک سے اپنی زندگی کا نصب العین حاصل کرے‘‘
تو کیا یہ دیکھنا معلّم کا فرض نہیں ہے کہ وہ دوسرے کون ہیں اور اُن کا نصب العین کیا ہے؟
پروفیسر نن کا بیان کہ کسی مخصوص نصب العین کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اَپنے آپ کو تعلیمی لائحۂ عمل کا زبردستی حصہ بنائے ‘ اِس اَمر پر دلالت کرتا ہے کہ تمام نصب العین شخصیت کی ترقی اور انفرادی امتیاز کی بلند ترین سطحوں تک نشوونما میں یکساں طور پر معاون ہیں۔ اِس نقطۂ نظر کی حمایت نہیں کی جا سکتی اَور خوش قسمتی سے پروفیسر نن اِس کی کمزوری اَچھی طرح سمجھتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے:
’’ایسے محسوس ہو سکتا ہے کہ اوپر بے ڈھنگے انداز میں بیان ہونے والا ہمارا نظریہ زندگی کے اَچھے اور برے نصب العینوں میں (اَور) حوصلہ افزائی کے لائق انفرادیت کی صورتوں اور دبا دیے جانے کے لائق انفرادیت کی صورتوں کے مابین امتیاز کی اجازت نہیں دیتا۔‘‘
چنانچہ وہ ایک سوال پیش کرتا ہے:
’’یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا اسکول کے معلّم کا کام یہ ہے کہ کسی بھی کردار سازی کے عمل کو اُس کی اخلاقی قدروقیمت سے قطع نظر ‘ غیر جانب دارانہ ہمدردی کے ساتھ پروان چڑھائے؟‘‘
پھر وہ خود اِس سوال کا جواب دینا شروع کرتا ہے:
’’اخلاقی میدانِ عمل میں والدین اَور اساتذہ کا سب سے اہم فرض یہ دیکھنا ہے کہ وہ چھوٹی سی دنیا جس میں بچہ نشوونما پاتا ہے ‘اُن عناصر سے حتی المقدور بھری ہو کہ جن سے انفرادیت کے بہتر نمونوں کی تشکیل ہوتی ہے اَور دیگر عناصر (اُس سے) نکال دیئے گئے ہوں۔‘‘
اگر والدین اَور اساتذہ شخصیت کی اَچھی اَور بُری اقسام سے متعلق اور اِس اَمر سے متعلق اَپنے فیصلے کو کہ بچے کی زندگی میں کون سے عناصر لازماً شامل اَور کون سے خارج ہونے چاہیے ‘ بچے پر جبراً مسلط کریں گے تو انفرادیت کی آزاد نشوونما سے متعلق سر پرسی نن کے عظیم اُصول کا کیا بنے گا؟ کیا تعلیم کے معاملے میں زندگی کے ایک مخصوص نصب العین کا عمل دخل نہیں ہے؟ اَور پھر سر پرسی نن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ انفرادیت کے بہتر نمونوں سے وہ کیا مراد لیتا ہے؟ بچے کی چھوٹی سی دنیا کے وہ کون سے عناصر ہیں جو حقیقتاً اُن (نمونوں) کی تشکیل کرتے ہیں؟ دیگر عناصر کون سے ہیں جو اِس چھوٹی سی دنیا سے خارج ہونے چاہئیں اَور یہ کہ اُنہیں کیسے خارج کیا جا سکتا ہے؟ کیا اُس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ والدین اَور اَساتذہ اِس اَمر کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہیں کہ انفرادیت کے بہتر نمونے کون سے ہیں ؟کیا وہ اُمید کرتا ہے کہ تمام والدین اَور اَساتذہ کی رائے ایک ہی ہوگی؟
کوئی بھی شخص سر پرسی نن کے قبل ازیں حوالہ دیئے جانے والے اِس زور دار بیان کہ ’’ وہ شروع سے آخر تک اِس دعوے پر قائم رہے گا کہ انسانی دنیا میں کوئی اَچھائی انفرادی سطح پر مردوں اور خواتین کی آزاد سرگرمیوں کے وسیلے کے سوا راہ نہیں پاتی‘‘ کے حق میں یہ کہتے ہوئے دلیل دے سکتا ہے کہ چوں کہ مردو خواتین فطری لحاظ سے اَچھے ہوتے ہیں اس لیے وہ یقینا ‘ اگر اُنہیں اُن کے حال پر چھوڑ دیا جائے ‘ اَچھائی تلاش کریں گے اور لازماً اِسے پالیں گے اس لیے کسی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ تاہم پروفیسر نن خود اِس دلیل کی تردید کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اِس بات کو مکمل طور پر فراموش کردیتا ہے کہ اس طرح وہ خود اپنے اُس نقطۂ نظر کے تضاد پر زور دے رہا ہے جس پر اُس نے مسلسل قائم رہنے کا عہد کیا ہے۔ چنانچہ وہ رقم طراز ہے:
’’اُس وقت کہ جب بچپن کی فطری تحریکیں ممکن ہے کہ خیر کی جانب حیاتیاتی میلان رکھتی ہوں‘ اُن سے یہ توقع کرنا غیر مناسب ہے کہ وہ بغیر کسی اعانت کے زندگی کے اُن مسائل کو حل کردیں گی جنھوں نے بہترین سوچ رکھنے والے دماغوں اور انتہائی بلند درجہ خداداد صلاحیتوں کی حامل انسانی نسلوں کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ چنانچہ وہ ہستیاں جن کی فطرت کی شدید ضرورت تخلیقی وسعت ہوتی ہے‘ لازماً بحیثیت ِ مجموعی خیر ہی کی تلاش کریں گی اَور وہ اِسے پائے بغیر مطمئن نہیں ہو سکتیں۔ تاہم انسانی شعور کی درد ناک تاریخ اَور انسان کی انسان کے ہاتھوں بننے والی گت کی افسوس ناک کہانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تلاش کس قدر مشکوک رہی ہے اور کس قدر بارہا اِس کا انجام تباہی پر ہوا ہے۔‘‘
مگر مصنف کو یقین ہے کہ فرد کو اخلاقی تعلیم کے معاملے میں بیرونی معاونت کی ضرورت ہے اور یہ کہ معلّم یقیناً وہ مدد فراہم کرے گا۔ تو کیا اِس کا مطلب یہ نہیں کہ انفرادی سطح پر مرد و خواتین کی آزاد سرگرمیوں میں مداخلت بنیادی طور پر تعلیم کے لیے ضروری ہے؟ اِس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقیات کے بغیر تعلیم کا کیا فائدہ ہے! تو پھر کیا مصنف کو اَپنے ابتدائی نقطۂ نظر میں تبدیلی نہیں کرنا چاہیے اَور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ’’انسانی دنیا میں کوئی اَچھائی معلّم کی بیرونی معاونت کے وسیلے کے بغیر داخل نہیں ہوتی؟‘‘ علاوہ ازیں فرد کو لازماً معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بیرونی معاونت کس رخ پر دی جائے گی۔ مختلف افراد کے لیےفرض کا مفہوم مختلف ہے۔ اخلاقیات ایک اضافی اصطلاح (relative term) ہے اَور یہ اُس نصب العین سے اپنا مفہوم اَخذ کرتی ہے جس کی یہ غرض پوری کرتی ہے۔ اِس کا مختلف نصب العینوں اور نظریات رکھنے والے اشخاص کے لیے مفہوم مختلف ہوتاہے۔ ہمیں بچے کو کس نوع کی اخلاقی تعلیم دینا چاہیے؟ ہم اُستاد کے نظریہ اَور اخلاقیات کے ہمیشہ اطمینان بخش ہونے پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ اخلاقی تعلیم کے لیے بیرونی معاونت جو کوئی بھی رُخ اختیار کرتی ہے اُس کا اطلاق یقیناً تعلیم میں ایک مخصوص نصب العین کے دعوے پر ہوگا۔ وہ دوبارہ رقم طراز ہے:
’’اگر ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھنا جائز ہے جس میں سب کی بھلائی موجود ہ صورتِ حال کی نسبت تقریباً ہر ایک کی بھلائی سے کہیں زیادہ ہو تو اِس خواب کو حقیقت بنانے میں جو کچھ بھی معاون ہو سکتا ہو ‘ کرنا جائز ہے۔ انفرادیت صرف ایک ایسے خاص ماحول میں ترقی کرتی ہے جہاں اِس کی مشترکہ مفادات اَور مشترکہ سرگرمیوں سے پرورش ہو سکتی ہو۔‘‘
اِس کا مطلب یہ ہوا کہ سر پرسی نن کے مطابق نہ صرف اساتذہ اَور والدین بلکہ معاشرے کو بھی یا زیادہ صحیح طور پر (بیان کیا جائے تو) ریاست کو حق حاصل ہے کہ فرد کی آزادی پر قدغن لگائے۔ اِس آزادی پر قدغن لگانے کا مقصد کیا ہے؟ ( مقصد یہ ہے کہ ) زندگی کے ایک مخصوص نصب العین کو جس کی والدین ‘ اَساتذہ اَور معاشرہ بحیثیت ِ مجموعی یکساں طور پر پیروی کرتے ہیں ‘ اِس قابل بنایا دیا جائے کہ اپنا حق جتلا سکے۔ سرپرسی نن انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا میں تعلیم (کے موضوع) پر چھپنے والے اَپنے ایک مضمون میں اِس نقطۂ نظر کو مزید واضح کرتے ہیں۔ دراصل اِس مضمون میں وہ یہاں تک کہہ جاتا ہے کہ تعلیم کا سارا عمل اپنی نئی پود کے ذہن و قلب پر ایک معاشرے کے نصب العینوں کو نقش کردینے کے عمل کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے:
’’لفظ تعلیم کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں مگر اُن سب کی تہ میں یہی تصور ہے کہ یہ انسانی معاشرے کے ذی شعور ارکان کی طرف سے نئی نسل کی اَپنے حیاتی نصب العینوں کے مطابق نشوونما کرنے کی کوشش کی طرف اشارہ کرتی ہے۔‘‘
’’یہ اسکول کا کام ہے کہ متعلّم (کے ذہن و قلب) پر اُن روحانی قوتوں کے اثرات مرتب کرے جو قومی مزاج کے مخصوص رجحان کے مطابق ہیں اور سماجی زندگی کی بقا اور نشوونما میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اُس کی تربیت کرتے ہیں۔‘‘
’’تعلیم اَچھی یا بری ہو سکتی ہے تاہم ......اس کی اَچھائی یا برائی معلّم کی اَچھائی ‘ دانائی اَور ذہانت کے تناسب سے ہوگی۔‘‘
اگر ہم اِس اقتباس کی وضاحت دو ابتدائی اقتباسات میں شامل اُس کے خیالات کی روشنی میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک قوم کی تعلیم (اِسی صورت) اَچھی ہوگی اگر اُس کا نصب العین یا قومی مزاج اَچھا ہوگا‘ اور اگر معاملہ اِس کے برعکس ہے تو یہ بری ہوگی ۔نیز یہ کہ بہترین قسم کی تعلیم صرف ایک ایسے معاشرے میں ممکن ہے جس کی بنا سب نصب العینوں میں سے بہترین نصب العین پر ہے۔
یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ مصنف کے اِس قسم کے خیالات کو اُس زبردست مخالفت کے ساتھ کیسے مربوط کیا جا سکتا ہے جو وہ اِس بات پر کرتا ہے کہ تعلیم میں کوئی مخصوص نصب العین حیات ہونا چاہیے۔
چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقصد ِ تعلیم کے حوالے سے پروفیسر نن کا بیان انتہائی مبہم اَور غیر واضح ہے۔
(جاری ہے)