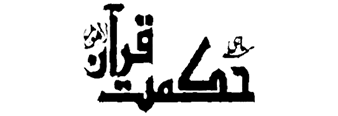(تذکارِ رفتگاں) ’’گاہے گاہے باز خواں ........‘‘ - ڈاکٹر ابصار احمد
9 /’’گاہے گاہے باز خواں ........‘‘ڈاکٹر ابصار احمد
من آنم کہ من دانم ۔ واقعہ یہ ہے کہ راقم بہت زیادہ پُرقلم نہیں ہے‘ یعنی ایسا انشاء پرداز نہیں ہے کہ قلم اٹھایا اور صفحے کے صفحے لکھتا گیا۔ اردو کا ادیب ہوں اور نہ انگریزی کا‘ ہاں پڑھنے کا عادی ہوں اور اچھی اور پُرمغز تحریریں دلچسپی سے اور بالاستیعاب پڑھتا ہوں۔ بہت سارا پڑھ لینے کے بعد تھوڑا سا لکھ بھی لیتا ہوں مگر جو کچھ لکھتا ہوں وہ زبان کے اعتبار سے خواہ بلند نہ ہو‘لیکن توقع ہے کہ نقد و تحقیق کے معیار پر‘ ان شاءاللہ‘ ضرور پورا اُترے گا۔ البتہ اس کبرسنی میں بھی یہ خیال ضرور ہے کہ اگر سکون کے ساتھ علمی خدمت کا موقع مل سکے تو اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی حتی الوسع کوشش ضرورکرتا رہوں گا۔ زبان و لفظیات کے شکوہ کے بجائے زیادہ فوکس معقول دینی معنویت‘ تاریخی صداقت اور مدلل علمی فکر پر ہوگا۔
گزشتہ ڈیڑھ دو ماہ کے دوران پچھلی صدی کے اہم اور معروف اسلامی سکالر محمد اسدؒ (لیوپولڈ ویس) کے بارے میں دستیاب کتابیں پڑھنے کی تحریک پروفیسر خورشید احمد مرحوم کی محمد اسدؒ پر ایک مختصر تحریر سے ملی جو انہوں نے اپنی کتاب ’’یادیں ان کی‘ باتیں ہماری ‘‘میں شائع کی۔ تین اہل ِعلم حضرات ------- رفیع الدین ہاشمی مرحوم‘ ظفر حسین ظفر اور سید ندیم فرحت ------- نے مسلم قائدین کے ساتھ ان کی یادوں کی ترتیب و تدوین کے بعد کتاب کو انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سےحال ہی میں شائع کیا ہے۔کتاب کا سرورق ‘ کاغذ کی کوالٹی اور طباعت اعلیٰ جمالیاتی ذوق کے مظہر ہیں۔ مسلم دنیا کے قائدین کو انتہائی سلیقے کے ساتھ تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا سے تعلق رکھنے والی۱۵ شخصیات‘ عالم ِعرب اور مشرقِ وسطیٰ کی ۱۰ جبکہ آخری تین شخصیات کے لیے جغرافیائی لحاظ سے ایک اچھوتا عنوان ’’ہر ملک ملک ِماست‘‘ قائم کیا گیا ہے۔ ان میں اسماعیل راجی الفاروقی‘ محمد اسد اور محمد حمید اللہ شامل ہیں۔
لیوپولڈ ویس ۲ جولائی ۱۹۰۰ء میں آسٹرو ہنگیرین ایمپائر کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے نوعمر صحافی کی حیثیت سے عرب دنیا میں تین سال گزارے اور عرب تہذیب سے متاثر ہو کر ستمبر۱۹۲۶ء میں اسلام قبول کر لیا۔ یہ عمل اس وقت جرمنی میں موجود مشہور خیری برادران میں سے بڑے بھائی عبدالجبار خیری کے دست شفقت پر قبولِ اسلام کی بیعت سے ہوا اور پھر تادمِ واپسیں اللہ سے وفا کا رشتہ نبھاتے ہوئے اسلامی ایمان و فکر کی دعوت میں ۶۶ سال صرف کر کے ۱۹۹۲ء میں ربّ حقیقی کے حضور پیش ہو گئے۔پروفیسر خورشید صاحب نے بیسویں صدی کے نصف اوّل میں اسلام کے اخلاقی و روحانی پیغام کو قبول کرنے اور پھیلانے والوں میں محمد اسد کو’’یورپ کے روحانی قبرستان کی زندہ آواز‘‘ لکھا ہے۔ راقم اس فہرست میں دو یورپین سکالرز کے ناموں کا اضافہ کرنا چاہے گا جنہوں نے اپنا آبائی مذہب یہودیت یا عیسائیت ترک کر کے اسلام دل و جان سے قبول کیا۔ مارما ڈیوک پکتھال (۱۸۷۵ء۔۱۹۳۶ء) اسلام کی ثقافت و کلچر پر علمی مضامین کے مصنف ہونے کے ساتھ مترجم قرآن بھی ہیں۔ان کا انگریزی میں ترجمہ The Glorius Quran صرف برصغیر پاک و ہند میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلا۔برٹش انڈیا میں قیام کے دوران حیدر آباد دکن سے انگریزی میں علمی جریدہ Islamic Culture کی اشاعت کا آغاز کیا۔ قدرے بعد میں دوسری اہم نومسلم شخصیت میرے محدود علم کی حد تک چارلس گائی ایٹن (حسن عبدالحکیم ؛ ۱۹۲۱ء ۔۲۰۱۰ء) ہیں‘ جن کی متعدد تصنیفات میں بالخصوص Islam and the Destiny of Man قابل ذکر ہے۔اس میںقرآنی مفاہیم کو جدید ذہن کے لیے انتہائی مؤثر اور دلکش انداز میں پیش کیا گیاہے۔ موصوف برادر محترم ڈاکٹر اسرار احمدؒ کی دعوت پر محاضراتِ قرآنی کے لیے ۱۹۹۲ء میں خاص طو رپر لاہور تشریف لائے‘ اور مرکزی انجمن خدام القرآن نے میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ محاضرات میں پیش کیے گئے انگریزی مضامین (جو انتہائی فکر انگیز موضوعات پر تھے) انجمن کے سہ ماہی جریدے The Quranic Horizons (۱۹۹۸ء۔۱۹۹۹ء) میں شائع کیے گئے تھے۔ حسن عبدالحکیم زندگی کے آخری کئی عشرے لندن کی سنٹرل مسجد اور کلچرل سنٹر کے ڈائریکٹر اور وہاں سے شائع ہونے والے علمی دینی جریدے کے ایڈیٹر رہے۔
محمد اسد نے عنفوانِ شباب (صرف بائیس سال کی عمر) میں شرقِ اوسط‘ شمالی افریقہ ‘مصر‘ لیبیا اور پھر دوبارہ تین سال بعد پورے عالم ِعرب‘ افغانستان‘ روسی ترکستان اور بالشویک روس (ـماسکو) تک سفر کر کے عالمی حالات کابچشم ِسرمشاہدہ کیا۔ ان اسفار کے مشاہدات پر مبنی سیاسی و ثقافتی رپورٹیں وہ فرینکفرٹ (جرمنی) کے مؤقر پرچے کو بھیجتے رہے ۔ چنانچہ بہت جلد چھوٹی عمر ہی میں جرنلسٹ کی حیثیت سے شہرت حاصل کر لی۔ بلادِ عربیہ کے دوسرے سفر کے بعد یورپ جا کر انہوں نے برلن میں کلمہ شہادت ادا کر کے اسلام قبول کر لیا‘ کیونکہ ان کے خیال میں کلام الٰہی قرآن مجید اور رسول اللہ حضرت محمدﷺ کی تعلیمات ہی میں انسانیت کے جملہ مسائل اور الجھنوں کا حل ہے۔ خود محمد اسد کے بلیغ و مصور قلم سے اس دنیا کی تصویر ملاحظہ کیجیے:
’’ایک دنیا جہاں اضطراب اور ابال ہو‘ یہ تھی ہماری دنیا‘ حد درجہ تباہی و خون ریزی‘ جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اجتماعی روایات میں رسہ کشی‘ فکری مذاہب میں تصادم‘ زندگی کے نئے نئے طریقوں اور فیشن کے لیے ہر جگہ ایک سخت کشمکش‘ یہ ہیں ہمارے دور کے خصائص اور اوصاف۔ جنگ عظیم (پہلی عالمی جنگ) کے دھوئیں کے ہول ناک بادلوں اور تباہ کاریوں سے لے کر چھوٹی چھوٹی جنگوں تک جن کا کوئی شمار ہی نہیں‘ انقلابات اور جوابی انقلابات‘ اقتصادی اور معاشی پریشانیاں جو اس زمانہ کی تمام دشواریوں اورپریشانیوں سے بڑھ چڑھ کر تھیں‘ ان تمام ہول ناک واقعات نے یہ حقیقت ظاہر کر دی تھی کہ فنی‘ صنعتی اور مادی ترقیات کی ساری زور آزمائی موجودہ انتشار اور بدنظمی میں ذرا بھی کمی نہ کر سکی۔‘‘
دوسری جگہ مغرب کے روحانی خلا اور مشینی‘ بے جان زندگی کی کرختگی و افسردگی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’بیسویں صدی کے ابتدائی سال اس لحاظ سے خاص امتیاز رکھتے ہیں کہ ان میں نمایاں طور ر ایک روحانی خلا (spiritual vacuum) پایا جاتا ہے ۔ وہ ساری اخلاقی اور روحانی قدریں جن سے یورپ صدیوں سے آشنا تھا‘ اب کسی خاص اور متعین شکل میں باقی نہیں رہ گئی ہیں۔ یہ ان ہول ناک واقعات کا نتیجہ ہیں جو ۱۹۱۴ء اور ۱۹۱۸ء کے درمیان پیش آئے۔ بظاہر اس کی کوئی توقع بھی معلوم نہیں ہوتی کہ اقدار کا کوئی نیا مجموعہ ان قدروں اور تصورِ حیات کی جگہ لے سکے گا۔ ہاں خطرہ اور خوف کا ایک احساس تھا؛ وہ احساس جو عقلی اور سماجی اُبال سے پہلے پیدا ہوا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے جدید انسان اس شبہ میں پڑ گیا تھا کہ آیا اس کی کوشش اور افکار کسی ایک مستقر پر رکیں گے یا نہیں۔ وسطی یورپ کے لیے اس صدی کی تیسری دہائی کے یہ چند سال عجیب و غریب تھے ۔ اجتماعی اور اخلاقی انتشار و بدامنی کی فضا ہر طرف چھائی ہوئی تھی اور اس نے انسان میں ایک خطرناک روحانی خلا اور شدید ذہنی کرب کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ انسان کے مستقبل کی طرف سے بڑھتی ہوئی مایوسی کی وجہ سے اس میں ایک مبہم کلبی اضافیت (cynical relativism) پیدا ہو گئی تھی۔‘‘
محمد اسد کی ذات من جانب اللہ کچھ ایسی تھی جو فلسفہ و مذہب کی کتابوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے مسحور ہو کر اسلام کی متلاشی اور پھر اس کی گرویدہ ہوئی۔ انہوں نے ۱۹۲۲ء میں بیت المقدس کا سفر کیا اور پہلی مرتبہ صحرائے سینا میں ٹرین میں سفر کرتے ہوئے اس عرب قوم اور عرب مسلم تہذیب کی جھلک دیکھی جس کو اسلام نے تہذیب و اخلاق کے ایک نئے سانچے میں ڈھالا تھا۔ انہوں نے ایک ذہین و حساس نوجوان کی حیثیت سے جس کو قدرت نے اعلیٰ درجہ کی قوتِ مشاہدہ عطا کی ہو اور وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھ رہا ہو‘ ہر چیز کو غور سے دیکھا اور اپنی مغربی دنیا سے مقابلہ کیا۔ان کو ایک بدوی کا اپنی روٹی کے دو ٹکڑے کر کے یہ کہتے ہوئے ان کی طرف پیش کرنا بھی ایک انوکھا واقعہ معلوم ہوا کہ ’’آپ بھی مسافر ہیں اور میں بھی مسافر ہوں اور ہم دونوں کا راستہ ایک ہے۔‘‘ خود پسند اوراپنی ذات کے خول میں گم مغربی دنیا کے اس نوجوان کے لیے یہ بڑا عجیب تجربہ تھا۔ یہ انسانیت کی ایک ایسی تصویر اور جھلک تھی جو ہر تصنع اور تکلف سے پاک تھی۔ یہ وہ معاشرہ ہے جو مسافر کی قدر کرتا ہے اور مہمان داری کو سعادت سمجھتا ہے۔ انہوں نے اس بدوی اور بالعموم عرب مسلمانوں کے ہاں باطنی اطمینان اور یقین کی وہ کیفیت دیکھی جس سے یورپ کے مرفہ الحال طبقات اور کامیاب تاجر تک محروم ہیں۔ وہ جنّت ارضی میں رہنے کے باوجود جہنم کی سی اذیتوں اور روحانی کرب میں مبتلا ہیں اور حقیقی اخلاقی اقدار سے کوسوں دُور ہیں۔ چنانچہ محمد اسد نے مسلمانوں کے ذہنی و باطنی ایمان اور یقین کا حقیقی سبب اور اس بلند و لطیف تر انسانیت کا سرچشمہ معلوم کرنے کے لیے اس قوم کے دین و عقیدہ اور اس کی تہذیب کی بنیادوں کا مطالعہ انتہائی دقت ِنظر سے کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حجاز (بعدازاں سعودی عرب) میں چھ سال طویل قیام کے دوران انہوں نے عربی زبان پر خوب دسترس حاصل کر لی۔ قرآن مجید اور دینیات کے اصل مراجع کا مطالعہ انتہائی محنت اور ذوق و شوق سے کیا۔
عرب میں قیام کے دوران محمد اسد کو سلطان ابن سعود اور بعد ازاں شاہی خانوادے کے متعدد شہزادوں اور اہم شخصیات سے رابطے کے مواقع ملے‘ جو کئی دہائیوں تک برقرار رہے۔ اس دوران انہوں نے کئی بار حج‘ حرمین اور مقدس تاریخی مقامات کی سیر اور صحرا میں اپنے عرب ساتھی زید کے ساتھ اونٹوں پر لمبے سفر کرکے بدویانہ سلیم الفطرت اندازِزندگی کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا۔ اس طرح وہ عربی اسلامی تہذیب کی روح اور اس کی داخلی صلاحیتوں سے آشنا ہوئے۔ انہیں اسلامی زندگی کا نظام‘ عبادات کا شیڈول اور جسم و روح کا خوش گوار اجتماع بہت بھایا۔ اسلامی دنیا انہیں مغرب کی بے چین اور محرومِ یقین دنیا سے یکسر مختلف نظر آئی۔ یہاں راقم کو محمد اسد کے افکارِ دینی کے حوالے سے پروفیسر خورشید صاحب کے ہاںکچھ ابہام اور خوش خیالی نظر آتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: ’’مغرب کے تصور کائنات‘ انسان‘ تاریخ اورمعاشرے پر ان کی گہری نظر تھی اور اسلام سے اس کے تصادم کا انہیں پورا پورا شعور و ادراک تھا۔ وہ کسی تہذیبی تصادم کے قائل نہ تھے ‘ مگر تہذیبوں کے اساسی فرق کے بارے میں انہوں نے کبھی سمجھوتانہ کیا۔‘‘ راقم متعدد کتابوں کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ محمد اسد نے اگرچہ سعودی عرب میں قیام کے دوران تیل کی دولت آنے سے پہلے سعودی مملکت میں محمد بن عبدالوہابؒ کی توحید پر مبنی اسلامی تحریک کی باقیاتِ صالحات کی شکل میں آرتھوڈوکس مائنڈ سیٹ اور اسلامی قوانین و عبادات کی سختی سے پابندی دیکھی ہو گی لیکن شاید مغربی یورپین کلچر میں اوائل عمر کے سماجی تجربات اور احساسات نے ان کے اعماقِ دل میں گھر کر لیا تھا۔ مزید برآں ‘وہ عرب ممالک خصوصاً مصر میں سفر اور مختصر قیام کے دوران شیخ مصطفیٰ المراغی (چند سال بعد جامعہ ازہر کے شیخ) سے ملاقات اور تبادلہ خیال سے اسلام میں نئی فکری لہر وں سے آشنا ہوئے ہوں گے‘کیونکہ شیخ المراغی مشہور جدیدیت گزیدہ اور روشن خیال مصری مصلح محمد عبدہ کی شاگردی ‘ علامہ رشید رضا اور جمال الدین افغانی جیسے شعلہ جوالا سے بچپن اور نوجوانی میں قربت کی وجہ سے خود مفکر‘ ناقد اور صاحب رائے شخص تھے۔ ان اساتذہ نے تواتر سے آنے والی دینی علمی روایات کے خلاف شیخ المراغی میں ذہنی اپچ پیدا کر دی تھی۔ فرانسیسی اور برٹش سامراجی تسلط کے اثرات اور لارڈ کرومر کی تعلیمی وثقافتی میدان میں افکار اور پالیسیوں سے مصر اور شمالی افریقہ کے دوسرے اسلامی عرب ممالک متاثر ہوئے تھے‘ بالکل اسی طرح جیسا کہ برصغیر میں اسلامیانِ ہند میکالے کے تعلیمی نصاب‘ زبان اور دینی درسیات میں کولونیل strategy کی بنا پراپنے اسلاف سے چلی روایات سے بڑے پیمانے پر کاٹ دیے گئے ۔ یہاں تک کہ سرسید احمدخان اور ان کے رفقاء کی تحریروں سے اہل ِسُنّت کے متفقہ عقائد بھی متاثر ہوئے اور علمائے حقہ نے سرسیدکو ان کے جدید افکار کی بنیاد پر ’’نیچری‘‘ بھی قرار دیا۔
سطور بالا کی روشنی میں پروفیسر خورشید صاحب کا یہ خیال کہ تہذیبوں کے اساسی فرق کے بارے میں محمد اسد نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا‘ محل نظر لگتا ہے۔ یورپ میں اٹھارھویں صدی سے شروع ہونے والی تحریک تنویر (Enlightenment) کے اثرات تمام مذہبی تہذیبوں کی طرح عالم اسلام پر بھی ہوئے اور اس سے صرف راسخ العقیدہ ومتدین(Orthodox) مسلمان ہی محفوظ رہے ہیں۔ چنانچہ بعض معاملات بالخصوص معاشرے میں خواتین کے کردار کے حوالے سے محمد اسد نے کئی جگہ سوالات اٹھا کر یہ ظاہر کیاکہ ان کی پوزیشن قدامت پسند دینی فکر و مزاج رکھنے والے مسلمانوں سے مختلف ہے‘ اور اس طرح وہ مغرب کی مخلوط لبرل معاشرت کو غیر اسلامی نہیں سمجھتے۔یہاں ان کے فکر کی دو جذبیت (ambivalence) بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ ایک طرف وہ ایمانی سطح پر شرم و حیا کو مانتے بھی ہیں لیکن دوسری جانب خواتین کے حجاب اور صنفی انفصال کے حوالے سے ان کی پوزیشن بڑی حد تک کمپرومائزڈ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اہم ترین علمی کام جس پر انہوںنے دو دہائیاں صرف کیں اور تحقیق و تنقید میں سخت محنت کی‘ یعنی ان کا انگریزی ترجمہ قرآن اور تفسیری و تجزیاتی و توضیحی نوٹس بعنوان The Message of the Quran کو خود پندرھویں صدی ہجری کے آغاز (۱۹۸۰ء) میں جبرالٹر سے شائع کیا۔ آٹھ صفحات پر مبنی مقدمہ میں فٹ نوٹ ۴ میں اپنے عرب (مصری) فکری اساتذہ اور مراجع کا کھل کر اظہار کرتے ہیں اور انہیں اسلاف و متقدمین مفسرین اور رجالِ علم و عرفان کے مقابلے میں جدید تناظر میں زیادہ اہم سمجھتے ہیں:
" The reader will find in my explanatory notes frequent references to views held by Muhammad 'Abduh (1849-1905). His importance in the context of the modern world of Islam can never be sufficiently stressed. It may be stated without exaggeration that every single trend in contemporary Islamic thought can be traced back to the influence, direct or indirect, of this most outstanding of all modern Islamic thinkers. The Qur'an-commentary planned and begun by him was interrupted by his death in 1905; it was continued (but unfortunately also left incomplete) by his pupil Rashid Rida under the title Tafsir Al-Manar, and has been extensively used by me. See also Rashid Rida, Ta'rikh al-Ustadh al-Imam ash-Shaykh Muhammad 'Abduh (Cairo 1350-1367 H.) "
محمد اسد کے مشرق وسطیٰ اور دوسری اسلامی ریاستوں میں سفر‘ کہیں مختصر اور بعض مقامات پر نسبتاً طویل ‘ بالخصوص عرب ممالک میں قیام کے دوران عربی لباس کا اختیار کرنا اور پھر اسلام کو بطور دین اختیار کرنا بہت سے نہ صرف مغربی بلکہ ہندوستانی سکالرز کے لیے بھی دلچسپی کا باعث بنا۔ چنانچہ مشرف بہ اسلام ہونے کی پوری داستان The Road to Mecca کا جرمنی کے علاوہ کئی دوسری یورپین زبانوں میں ترجمہ ہوا‘ اور اس کی علمی حلقوں میں بہت پزیرائی ہوئی۔ ہندوستان کے عظیم ذی علم و قلم اور مفکر ِاسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ نے اس کا اردو ترجمہ برادر زادہ مولوی محمد الحسنیٰ (مدیر البعث الاسلامی) کے سپرد کیا اور خود تیس صفحات پر مشتمل نہایت وقیع پیش لفظ و تعارف لکھا۔ کتاب کا ٹائٹل’’ طوفان سے ساحل تک‘‘ رکھا گیا‘ یعنی یورپی زندگی کے اس طوفان کی تصویر جس سے ہجرت کر کے محمد اسد قلبی اور روحانی سکون کے ساحل تک پہنچے اور ایمان سے بہرہ یاب ہوئے۔ کتاب کے اردو ترجمہ کا خیال مولانا ابوالحسن ندویؒ کو خاص طور پر اس کا عربی ایڈیشن الطریق الی المکۃ کے مطالعہ کے بعد آیا‘کیونکہ اس میں ایک غیر مسلم یورپین کی اپنی ثقافت ‘ تہذیبی فکر اور لائف سٹائل کو ترک کر کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی تفصیلات بہت دلچسپ اور سبق آموز ومفید معلوم ہوئیں۔ محمد اسد نے اپنی تیسری اہلیہ پولا حمیدہ اسد اور کچھ دوسرے احباب کے اصرار پر ’’روڈ ٹو مکہ ‘‘کی دوسری قسط کے لیے یادداشتیں اور واقعات کی تفصیلات قلم بند کیں اور اس کے لیےعنوان (1932-1992) Home coming of the Heart تجویز کیا تھا۔ حرمین (سعودی عرب) اور اسلام کی حقانیت سے فیض یاب ہونے کو انہوں نے اپنے حقیقی روحانی گھر کی طرف مراجعت سے تعبیر کیا‘ جس کا عربی ورژن عودۃ القلب الٰی وطنہ ہے۔خود مصنف تو اس کی طباعت سے بہت پہلے ۱۹۹۲ء میں غرناطہ (سپین) میں انتقال کر گئے تھے۔ شومیٔ قسمت سے پولاحمیدہ بھی ۲۰۰۶ء میں اس دارفانی سے کوچ کر گئیں اور مسودہ معروف پاکستانی سکالر ایم اکرام چغتائی مرحوم نے نہایت محنت اور دقت نظر سے مرتب اور تدوین کر کے ۲۰۱۵ء میں لاہور سے شائع کیا۔ راقم نے اس کا نسخہ حاصل کیا‘ اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے مشمولات اور فٹ نوٹس کو معلومات کا ایک انتہائی قیمتی خزینہ پایا۔ اکرام چغتائی متعدد مرتبہ یورپ گئے اور وہاں کئی کئی ماہ قیام بھی کیا۔ جرمن اور آسٹرین زبانوں پر عبور حاصل کیا۔چنانچہ پولا حمیدہ نے اعتماد کے ساتھ تمام مسودات ان کے سپرد کر دیے۔ یہ خود بھی محمد اسد کی شخصیت اور علمی و تصنیفی کاموں کے مداح تھے۔ چنانچہ انہوں نے ’’روڈ ٹو مکہ‘‘ کا اردو ترجمہ ’’محمد اسد: بندئہ صحرائی‘‘ کے عنوان سے کر کے شائع کیا۔ علاوہ ازیں‘ دو جلدوں میں اپنی انگریزی کتاب Muhammad Asad: Europe's Gift to Islam بھی شائع کی۔ ان میں پاکستان کی سفارتی ذمہ داری سے استعفا اور یہاں سے نقل مکانی اور تادمِ واپسیں مختلف ممالک میں قیام اور علمی و ثقافتی رابطوں کی روئیداد بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ محمد اسد کے تعلقات عالمی سطح پر مسلم اور غیر مسلم مشاہیر سے تھے‘ جن سے وہ مذہب کے لیے جدید چیلنجز کے حوالے سے گفتگو میں ہمیشہ اسلامی تعلیمات کی علمی فوقیت ثابت کرتے تھے۔ ان کی دلچسپ داستانِ حیات پر ایک آسٹرین فلم ڈائریکٹر نے دستاویزی فلم بھی بنائی جو ۲۰۰۸ء میں ریلیز ہوئی۔ اکرام چغتائی مرحوم نے ’’روڈ ٹو مکہ‘‘ کی دوسری جلد جس کا تذکرہ قبل ازیں ہوا‘ کو اسد سے تعلق رکھنے والے بے شمار احبابِ سعودی عربAsadians (یعنی ’’رجالِ اسد‘‘) کے نام منتسب کیا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اسد کا تعلق ایمان و اسلام کی طرف آنے میں اور پھر سال ہا سال کی گرم جوش رفاقت میں ان اصحابِ علم و اقتدار احباب کا بہت حصہ تھا۔
برٹش کولونیل بھارت میں آمد (۱۹۳۲ء۔۱۹۴۷ء)
محمد اسد کی پہلی شریک ِحیات Elsa (قبول اسلام کے بعد نام: ’’عزیزہ‘‘) جو عمر میں شوہر سے بیس بائیس سال بڑی تھیں‘ کا ۱۹۳۰ء میں حج بیت اللہ کے بعد مختصر علالت کے باعث مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا اور وہ وہیں دفن ہوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب ہی میں ایک معروف نجدی خاندان کی خاصی کم عمر خاتون منیرہ سے شادی کی جس کے بطن سے اپریل ۱۹۳۲ء میں بیٹے طلال
[طلال نے اپنے بچپن اور لڑکپن میں والدین کے ساتھ لاہور‘ پٹھان کوٹ (دار الاسلام)‘ ڈلہوزی اور کئی دوسرے شہروں میں قیام کیا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انگلستان اور امریکہ میں پڑھا اور سوشل Anthropology میں پروفیسر کی حیثیت سے تدریس کی۔ کئی اہم کتابیں اور ریسرچ مضامین لکھ کرعمرانیات میں عالمی شہرت حاصل کی۔ تادمِ تحریر نیویارک (امریکہ) میں مقیم ہیں۔ ان کا ’’روایت‘ ‘ کا تازہ ترین تصور Discursive tradition راقم کے لیے ایک عسیر الفھم معمہ ہے۔]
کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ محمد اسد کی ملاقات اور تعارف شاہی مہمان خانے میں مقیم ہندوستان سے آئے ہوئے قصوری خاندان کے دو بزرگ بھائیوں [جن میں بڑے مولانا عبدالقادر قصوریؒ (م:۱۸۴۲ء) اور برادر اصغر عبداللہ قصوریؒ] سے ہوا‘ جنہوں نے اسد کو ہندوستان آنے کی دعوت دی۔ گفتگوئوں میں ان حضرات کا اہل حدیث مسلک اور ہند اسلامی فکر وتہذیب کی صورت حال اور برطانوی استعمار سے استخلاص کی مساعی پر بھی روشنی ڈالی گئی ہو گی۔ اسی طرح برصغیر کے دینی اکابر‘ زعماء اور فلسفی شاعر علامہ اقبال کا تذکرہ بھی ہوا ہوگا۔ ان کی تحریک پر محمد اسد اپنی اہلیہ اور چند ماہ کے شیر خوار طلال کے ساتھ سمندری جہاز سے کراچی اور پھر ریل کے ذریعے لاہور وارد ہوئے۔ اتفاق سے لاہور میں قصوری خاندان کی اقامت گاہ والڈ سٹی کے شیراںوالا دروازہ کے عین بالمقابل تھی ۔ یہ قصوری فیملی کے ہاں مہمان کی حیثیت سے فروکش ہو گئے۔
راقم اپنے مطالعے کی روشنی میں علیٰ وجہ البصیرت یہ سمجھتا ہے کہ محمد اسد کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی سکیم اور فضل کے تحت ہندوستان میں دو حقیقی اہل اللہ کی شناسائی میسر آئی: اولاً مولانا احمد علی لاہوریؒ (ثقہ عالم و عارفِ دین ‘مؤسس مدرسہ اور انجمن خدام الدین) اور ثانیاً چودھری نیاز علی خاںؒ (بانی دار الاسلام پٹھان کوٹ بعدہٗ جوہر آباد)۔ قارئین ’’حکمت قرآن‘‘ اور دینی ذوق کے ساتھ پابند صوم و صلوٰۃ حضرات مولانا احمد علی لاہوریؒ (۱۸۸۷ء۔۱۹۶۲ء) کے بارے میں تو اتنا کچھ جانتے ہوں گے کہ مزید کچھ لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ چودھری نیاز علی خان مرحوم اور ان کے ’’دار الاسلام‘‘ پراجیکٹ کے بارے میں لوگوں کو زیادہ علم نہیں ہے۔ بھلا ہو چودھری صاحب کے چھوٹے صاحب زادے کے ایم اعظم مرحوم کا کہ انہوں نے نہ صرف اپنے والد کے حالاتِ زندگی اور تقسیم سے قبل اور بعد کے زمانے میں احیائے اسلام کے سلسلہ میں زعمائے ملت سے جو مراسلت ہوئی‘ ان تمام چیزوںکو اپنی ضخیم تصنیف ’’حیاتِ سدید‘‘ میں جمع کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بلاشبہ اسلام کے سچے خادم‘ ایک پاک طینت انسان تھے۔ انجینئرنگ کی تعلیم کے بعد محکمہ انہار میں سینئر عہدے پر ملازمت کے ساتھ پوری زندگی قرآن کریم سے تعلق اور احیائے دین و ملت کے لیے پیہم سعی و جُہد میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور صاحب ِفہم و فراست نیک بندوں کے لیے بڑی الفت اور للہیت کا جذبہ ان میں ودیعت فرمایا تھا۔ جوہر آباد میں ۱۹۷۶ء میں ان کے انتقال پر چودھری صاحب کے ہمدمِ دیرینہ محمد اسد مراکش سے اپنے تعزیتی خط محررہ ۲ مارچ ۱۹۷۶ء میں رقم طراز ہیں:
’’چودھری نیاز علی خاں کی وفات سے پاک و ہند میں اسلامی جدو جہد کا ایک اہم باب اختتام پزیر ہوا ہے۔ نظریۂ پاکستان کے لیے ان کی بے پناہ محبت اور اس نظریہ کے بانی ڈاکٹر محمد اقبال سے ان کی دیرینہ دوستی اور ان کے مشورہ پر اپنی زمینوں پر ادارہ ’’دار الاسلام‘‘ کا قیام احیائے اسلام کے فدائین کے لیے امیدوں کا مرکز بن گیا تھا۔ مگر ان ظاہری نتائج کے علاوہ ان کی لمبی اور کامیاب زندگی جو کہ اسلام کی خدمت کے لیے وقف تھی‘ اور ان کی درخشاں اچھائی اور یقین محکم اور لوگوں کی مدد کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہماری چہل سالہ دوستی کے دوران مجھے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملا ‘جو اُن کی طرح پُر خلوص‘ بے غرض ہو اور اسلام کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے ہر وقت پابہ رکاب ہو۔ یہ ان کی ذاتی مثال ہے جو کہ انسانی تاریخ میں ان لوگوں کے لیے جو اسلام سے محبت کرتے ہیں اور اس کی ترویج کے لیے بے قرار رہتے ہیں‘ اُمید کا پیغام ہے۔‘‘
سید اسعد گیلانی چودھری صاحب کے احوال میں لکھتے ہیں :
’’افراد کے اعلیٰ و بلند خیالات اور زندگی میں ان کی عمدہ اور نمایاں عملی خدمات کے حوالے ہی سے ان کا مقام و مرتبہ متعین ہوتا ہے۔ کسی آدمی کی ذاتی خوبیاں اور شخصی امتیازات اس کے علاوہ ہوتے ہیں۔ چودھری صاحب مرحوم ایک غیر معمولی انسان تھے۔ وہ اپنی روزمرہ زندگی ایک نپے تلے نظام الاوقات کے تحت بسر کرنے کے عادی تھے اور اپنے مخصوص انداز میں روزمرہ ڈسپلن کے سختی سے پابند رہتے بلکہ دوسروں سے بھی ایسی ہی توقع کیا کرتے تھے۔ دراصل وہ بڑی محنت اور دھیان سے اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو کار آمد اور مفید تر بنانے کی تگ و دو میں شب و روز متوجہ رہتے تھے۔ وقت کی پابندی کے ساتھ سوتے اور جاگتے تھے۔ متعین وقت ہی پر کھاتے اور پیتے تھے۔ وہ روزمرہ عبادات و معمولات میں باقاعدگی کی قابلِ رشک مثال تھے۔ وہ کافی حد تک ذاتی رعب داب قائم رکھنے والی شخصیت کے حامل تھے۔ انہوں نے گھریلو زندگی گزارنے میں عام معمول کا مزاج رکھنے والے آدمی کی طرح عورتوں اور بچوں میں گھلے ملے رہنے والی طبیعت نہ پائی تھی۔ ذراسخت گیر قسم کے اور فاصلے پر رہنے والے بزرگ سمجھے جاتے تھے۔ تا ہم موصوف اپنے اعزہ واقارب اور قریبی تعلقات رکھنے والے افراد نیز اپنی اولاد و عیال کے معاملہ میں بہت شفیق اور ان کے حقوق کا خصوصی خیال و فکر کرنے والی قدیم طرز کی ایک وضع دار و با اصول ہستی بھی تھے۔
چودھری صاحب ضابطہ کے سخت پابند انسان تھے۔ ان کا پورا گھر ان کے ضابطوں کے گرد گھومتا تھا ۔ ہر چیز کے لیے ایک مخصوص جگہ مقررتھی‘ ہر کام کا ایک وقت مقرر تھا اور ہر ایک کا مقام متعین تھا جس کی وجہ سے ان کا گھر تمام معاملات میں پابندیٔ اوقات کا بہترین نمونہ تھا۔ اس ضابطہ بندی اور سختی کے باوجود چودھری صاحب اپنے افراد خانہ کے لیے بہترین نمونہ تھے۔ ان کے حقوق ادا کرنے میں وہ نہایت درجہ فیاض تھے۔ اپنے دونوں بیٹوں چودھری محمد اسلم خاں اور چودھری اعظم خاں کی تعلیم و تربیت کے علاوہ اپنے بھائیوں کی تعلیم کی طرف بھی پوری دل سوزی سے ہمیشہ متوجہ رہے۔ چودھری صاحب نے آخری دم تک اپنے اہل خانہ اور بچوں کی تربیت‘ تعلیم‘ ذہنی اور فکری اصلاح کا کام مکمل اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔‘‘
(سید اسعد گیلانی؛ اقبال ‘دار الاسلام اور مودودی - ص ۲۷۶‘ ۲۷۷)
چودھری نیاز علی خاں اپنی تبلیغی و دینی اور عملی خدمات‘ایثار و جدوجہد‘ اپنے دینی مزاج اور وسعت نظر جیسی عمدہ صفات کی بنا پر دینی و علمی حلقوں میں ایک جانی پہچانی اور معروف شخصیت تھے۔ دار الاسلام (پٹھان کوٹ) اپنے آغاز (۱۹۳۶ء) ہی سے بہت جلد برصغیر کا ایک ممتاز اور نمایاں تعلیمی‘ علمی‘ اصلاحی اور تربیتی مرکز سمجھا جانے لگا۔ قرآنی و ملّی انقلابی احیائی خدمت کے لحاظ سے یہ اپنی علیحدہ شان اور امتیازی حیثیت و شہرت رکھتا تھا‘ کیونکہ علامہ اقبال ‘ علامہ سید سلیمان ندویؒ‘ مولانا اشرف علی تھانویؒ‘ مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ‘ مولانا مودودیؒ اور مولانا عبدالماجد دریابادی ؒ جیسے اکابر علماء اور اہل فکر و نظر حضرات کی اشیرباد اسے حاصل تھی۔ چودھری نیاز علی صاحب کا حلقہ ارادت بہت وسیع اسی طرح تھا کہ وہ ایک جانب تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاسؒ سے تعلق رکھتے تھے‘ جنہوں نے ان کے بارے میں اپنے تاثر میں یہ فرمایا: ’’میں نے چودھری نیاز علی خاں سے زیادہ عقل مند انسان عمر بھر نہیں دیکھا۔‘‘دوسری جانب ان کا روحانی و قلبی تعلق تھانہ بھون کی خانقاہ اور علمی ذوق مولانا ابوالحسن علی ندوی (علی میاں) سے بھی تھا جنہوں نے دین اسلام اور قرآنی علوم و معارف کے حوالے سے چودھری صاحب کے آتش بجاں ہونے کی اس طرح تعریف کی: ’’آپ کی صحت‘ خیالات کی وضاحت اور استقامت اگر نوجوانوں کو ملے تو بڑاکام ہو جائے۔ مجھے اپنا ایک مخلص دعا گو‘ قدر دان اور خرد و نیاز مند تصور فرمائیں۔‘‘ حافظ نذر احمدؒ نے اپنی تحریر میں لکھا کہ چودھری صاحب کی ذات ہی بہت بڑی تحریک تھی۔ سب سے اہم اور حقیقت کی ترجمان مولانا عبدالماجد دریابادی کی یہ تحریر ہے جو وہ چودھری صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں:
’’پہلا دارالاسلام (پٹھان کوٹ) تو ان کے صرف دینی جذبہ اور اخلاص کی ایک یادگار تھا‘ لیکن یہ دارالاسلام (جوہر آباد) ان کے دینی جذبہ کے ساتھ ساتھ ان کے غیر متزلزل عزم‘ ان کی ناقابلِ شکست ہمت اور ان کی انتھک محنت کی بھی ایک غیر فانی یادگار ہے۔ اس عمر میں ان کی اس ہمت کو دیکھ کر فی الواقع رشک آتا ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اگر ہماری قوم باہمت نوجوانوں سے خالی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بوڑھے ہی قوم میں پیدا کر دے جن کی مثال سے ہم سبق حاصل کرسکیں۔‘‘ (’’صدق جدید‘‘ لکھنو‘ اپریل ۱۹۶۵ء)
علامہ اقبال کی راہنمائی اور مشورے سے چودھری نیاز علی نےادارہ دارالاسلام ٹرسٹ قائم کیا تھا۔چنانچہ دارالاسلام کی تعلیمی اسکیم علامہ اقبال کے نظریات ہی کی مرہونِ منت تھی۔ علامہ اقبال مسلمانوں کے لیے (بالخصوص نوجوانوں کے لیے) کسی جدید دار العلم کی تلاش میں تھے۔ اسی کے ساتھ ان کے خیال میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ نظریاتی وطن کی ضرورت بھی تھی‘ جس کا نقشہ انہوں نے مسٹر جناح (قائد اعظم) کے سامنے رکھا اور چاہتے تھے کہ مسلم لیگ ایک علیحدہ اسلامی ریاست کے تصور کو اپنے قومی نصب العین کے طور پر قبول کر لے۔ پھر اس جدید اسلامی ریاست کے لیے جدید فقہ اسلامی کا کام بھی ان کے نزدیک بہت اہم تھا۔ اس دور کے دینی زعماء و صلحاء کا خیال ایسے ہوسٹل قائم کرنے کا بھی تھا جن میں مسلمان طلبہ کو اقامتی درس گاہ میں رکھ کر دینی علم کے ازدیاد کے ساتھ اسلامی آداب آشنا زندگی سے گزار کر عملی مسلمان بننے کی تربیت دی جائے تاکہ کالج اور سکول کی لادینی تعلیم کے اثرات ان کے ذہن و کردار سے صاف ہو سکیں۔ دوسری جانب محمد اسد لاہور میں قیام پزیر ہو کر اپنے مطالعہ اور لیکچرز میں مصروف ہو گئے۔ لاہور کی کئی اہم سیاسی‘ سماجی اور علمی شخصیات سے نہ صرف تعارف بلکہ تبادلہ خیال اور بحث مباحثہ بھی ہونے لگا تھا۔ انجمن حمایت ِاسلام کے پلیٹ فارم پر اور دوسرے تعلیمی اداروں مثلاً اسلامیہ کالج کے حبیبہ ہال میں یورپ اور اسلام کے افکار و ثقافت پر ان کےتقابلی جائزے کو سامعین نے بہت سراہا اور وہ لیکچرز کے لیے دہلی‘ علی گڑھ اور کئی دوسرے شہروں میں بھی بلائے گئے۔ چنانچہ انہوںنے اپنے خیالات ۱۹۳۳ء میں لاہور اور دہلی سے بیک وقت شائع ہونےو الی کتاب Islam at The Crossroads میں پیش کیے۔ اس کی تعریف نہ صرف مولانا مودودی نے حیدر آباد دکن میں کی بلکہ علامہ اقبال نے بھی اس کتاب کے مندرجات کو ان الفاظ میں سراہا:
" This book is extremely interesting. I have no doubt that coming as it does from a highly cultured European convert to Islam, it will prove an eye-opener to our younger generation."
علامہ اقبال کے ساتھ ایک ملاقات کے موقع پر محمد اسد نے حدیث کے حوالے سے کچھ ایسے جملے بولے جن سے استخفافِ حدیث و سُنّت کا پہلو نکلتا تھا اور اجتہاد پر زور دیتے ہوئے تقلیدی ذہن کی مذمت کی۔ علامہ نے اس کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے مغرب سے مرعوبیت اور اخلاقی و ایمانی زوال کے scenario میں اپنے اس شعر کے مطالب کو بیان کرتے ہوئے تمسک بالقرآن و سُنّت ِرسولﷺ کی اہمیت محمد اسد پر واضح کی: ؎
زِاجتہادِ عالمانِ کم نظر
اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر
یعنی جو لوگ دین میں کتربیونت کر کے اسے مادیت پسند و ملحد مغرب کی مراد پر ڈھالنا چاہتے ہیں وہ عالمانِ کم نظر ہیں‘ ان کے اجتہاد سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے اسلاف کی اقتدا کی جائے اور دین کو اس کی کلاسیکی صلابت (purity)کے ساتھ مانا جائے۔ یہ احوط ہے‘ اسلم ہے‘ زیادہ سلامتی والا راستہ ہے ۔ علامہ نے اسی نشست میں انہیں حدیث کے مجموعے صحیح بخاری کے انگریزی میں ترجمے کا مشورہ تاکیداً دیا جسے محمد اسد نے نہ صرف فوری طور پر قبول کیا بلکہ اس پر عمل شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں مولانا عبدالقادر قصوری کےوسیع کتب خانے سے انہیں متعدد کتابیں بسہولت مل گئیں۔ چنانچہ انہوں نے چند اجزاء کا ترجمہ کر کے شائع کروا دیا‘ جس کی Islam at the Crossroads کی طرح ہندوستان کے اعلیٰ اسلامی حلقوںمیں تحسین کی گئی۔ محمد اسد نے علامہ اقبال کی اس فرمائش کا اتنا پاس کیا کہ انہوں نے ہندوستان سے باہر مشرقِ بعید کے ممالک مثلاً چین‘ انڈونیشیا اور ملایا وغیرہ کے دورے کا پروگرام ختم کر کے یہیں رہ کر قرآن کریم اور صحیح بخاری کے ترجمے پر اپنی تمام صلاحیت اور اوقات صرف کرنے کا تہیہ کر لیا۔
محمد اسد پر لکھی گئی کتابوں کے مصنف محمد اکرام چغتائی کی رائے ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں جس ہستی سے اسد سب سے زیادہ دلی تعلق رکھتے تھے‘ وہ تھے چودھری نیاز علی خاں۔ ان سے محبت و قربت کا اندازہ محمد اسد کے مندر جہ ذیل اقتباس سے لگایا جا سکتا ہے :
’’ایک سال قبل یعنی ۱۹۳۵ء میں میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو میرے محبوب ترین دوستوں میں شمار ہوتا ہے‘ اور یہ پُرخلوص دوستی اس کی وفات تک جوں کی توں قائم رہی۔ اس عزیز دوست کا نام چودھری نیاز علی خاں تھا‘ جنہوں نے چھیانوے سال کی عمر میں داعیٔ اجل کو لبیک کہا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے محکمہ آبپاشی میں سینئر انجینئر تھے۔ اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے علاوہ انہیں تبلیغ اسلام اور قرآن و سنت کے پیغام کی نشر و اشاعت سے شیفتگی کے ساتھ خصوصی دلچسپی تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ’’دارالاسلام‘‘ کے نام سے ایک اقامتی تعلیمی اور ریسرچ ادارہ بھی قائم کیا اور اپنی جاگیر کی متعدد عمارتیں اس ادارے کو وقف کر دیں۔ ان وقف عمارتوں کے قریب ان کی اپنی وسیع و عریض قلعہ نما رہائش تھی جسے ’’قلعہ جمال پور‘‘ کہا جاتا تھا۔‘‘
اسد کو ستمبر ۱۹۳۹ء کے اوائل میں دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے پر آسٹرین پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے ’’غیر ملکی دشمن‘‘ کی حیثیت سے نظربند کر دیا گیا۔ ان کی مدّتِ اسارت یکم ستمبر۱۹۳۹ء تا دسمبر۱۹۴۵ء ہے۔ کے ایم اعظم لکھتے ہیں کہ اس نظربندی کے عرصہ میں ان کی بیوی منیرہ اور بیٹا طلال ہمارے ہاں قلعہ جمال پور میں مقیم رہے۔ طلال اور کے ایم اعظم بالکل ہم عمر تھے اور دونوں میں خوب دوستانہ تھا۔ اسد کی رہائی کے لیے نیاز علی خاںم تواتر کوشش کرتے رہے۔ رہائی کے بعد جمال پور میں چودھری صاحب کے ہاں قیام کے دوران اسد نے ایک ماہنامہ پرچہ ’’عرفات‘‘ نکالنے کا ارادہ کیا۔ ’’عرفات‘‘ دیگر رسائل سے اس اعتبار سے مختلف تھا کہ مروجہ جرائد میں کئی مصنّفین کی نگارشات شائع کی جاتی ہیں‘ لیکن یہ رسالہ ’’خود کلامی‘‘ تھی یعنی یہ صرف اسد کے خیالات کا ذریعہ اظہار تھا۔ خیال تھا کہ اس کے توسط سے مجوزہ پاکستان کے نظریاتی مسائل کو بالصراحت پیش کرنے میں مدد ملے گی۔ طویل نظر بندی کے دوران محمد اسد کے ذہن میں دوبارہ وہ فکر عود کر آئی جسے چند برس قبل علامہ اقبال کی وضاحت اور نصیحت کے بعد انہوں نے دبا کر حدیث کے مجموعہ صحیح بخاری کا ترجمہ شروع کیا تھا۔ راقم آثم نے اسی پس منظر میں اسد کے ہاں ذہنی سطح پر دو جذبیت کا ذکر کیا تھا۔ اب ان کا خیال یہ بنا کہ حقیقی شریعت ہمارے علمائے دین کی سابقہ نسلوں کے موضوعی قیاسی استدلال اور استخراجات کے بوجھ تلے دب گئی ہے۔ مسلمانوں کے احیائے نو کے لیے یہ شرط ناگزیر ہے کہ شریعت کی حقیقی سادگی اور اختیارات کو منظر عام پر لایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ’’صحیح بخاری‘‘ کے ترجمہ و تشریح کو ڈیڑھ دو سال مؤخر کر کے ’’عرفات‘‘ کی اشاعت کو ترجیح دی‘ جو آزادی کے متوالوں کو ابھارنے والی آواز بنے اور نئی ریاست کے بننے پر اسلامی قانونی معاملات پر بھی فکری مواد فراہم کرے۔ اس کے پہلے چند شمارے ڈلہوزی اور بعد ازاں لاہور سے شائع ہوئے‘ جن کا ذکر پروفیسر خورشید احمد مرحوم نے بھی اپنی تحریر میں کیا۔
اب ہم ان واقعات اور تفصیلی مراسلت پر نظر ڈالتے ہیں جن کے بعد مولانا مودودی نے حیدر آباد دکن سے ہجرت کر کے شمالی ہندوستان میں پٹھان کوٹ کے قریب جمال پور میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ مولانا کی اوّلین تصنیف ’’الجہاد فی الاسلام‘‘ سے علامہ اقبال بھی متاثر ہوئے تھے اور انہوں نے بھی چودھری صاحب کو مولانا مودودی کو اپنے ہاں دعوت دینےکی تجویز دی تھی۔ وہاں تعلیم و تدریس کا سلسلہ قبل ازیں شروع کر لیا گیا تھا۔
چودھری نیاز علی خاں اور مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے درمیان کچھ عرصہ خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا جس کا آغاز دفتر ’’ترجمان القرآن‘‘ دکن سے ستمبر ۱۹۳۵ء میں تحریر شدہ خط سے ہوا۔ چودھری صاحب کے مولانا سے استفسارات مجوزہ دینی ادارے کے نام کے تعین ‘ درس و تدریس کے پروگرام‘ اور بزرگ عالم دین و مربی (جو قابل اور صاحب ِبصیرت ہو) کے انتخاب کے حوالےسے تھے جو اس کے ’’شیخ اتالیق‘‘ اور منصرم مقرر ہوں۔ مولانا مودودی اپنے خط محررہ ۴ دسمبر ۱۹۳۶ء بنام چودھری نیاز علی خاں میں حیدر آباد میں جناب محمد اسد سے ملنے کا ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں: ’’ان کی کتاب Islam at the Crossroads اور ترجمہ صحیح بخاری دونوں میری نظر سے گزرے ہیں۔ میراخیال یہ ہے کہ دورِ جدید میں اسلام کو جتنے غنائم یورپ سے ملے ہیں ان میں یہ سب سے زیادہ قیمتی ہیرا ہے۔ اسلام کی سپرٹ اس میں پوری طرح حلول کر گئی ہے‘ اور اسلام کو اس نے علماء سے زیادہ اچھی طرح سمجھا ہے جو پچاس پچاس برس سے درس و تدریس میں مشغول ہیں۔‘‘ مولانا نے خیال ظاہر کیا کہ جدید نیم خود مختار کونسلوں میں مسلمانوں کے پرسنل لاء کے مسخ کیے جانے کا خدشہ ہو گا جس کا تدارک صرف ’’جدید علماء‘‘ (Modern Ulema) ہی کر سکیں گے جو اس زمانہ کی زبان اور حالات میں اسلامی قوانین کی صحیح تعبیر پیش کرنے کے قابل ہوں گے۔ اسی مکتوب میں مولانا نے نہایت دِقت نظر سے کام لیتے ہوئے مجوزہ تعلیمی و تربیتی ادارے (جس کا نام دارالاسلام طے پا گیا تھا) میں درس و تدریس کے قواعد و ضوابط اور نظریاتی تفاصیل کی وضاحت دس نکات کی شکل میں کی جن میں سے چار نکات قارئین کی دلچسپی اور معلومات کے لیے درج کیے جاتے ہیں جو مولانا کے ذہن کی عکاسی بھی کرتے ہیں:
’’(۱) ادارہ میں سردست صرف اتنے آدمیوں کو شریک کیا جائے جن کو آپ کی جائیداد موقوفہ بآسانی support کر سکتی ہو‘ خواہ ان کا پورا بار وقف پر ہو یا کسی حد تک وہ اپنا بار آپ سنبھالنے والے ہوں۔ دو تین سال کی تعلیم و تربیت کے بعد ایسا انتظام کیا جائے کہ ادارہ کے ارکان باہم مل کر تجارتی اصول پر کوئی پریس اور دارالاشاعت چلائیں اور نہ صرف اپنا بار خود سنبھالنے کے قابل ہو جائیں بلکہ اپنے ادارہ میں دوسرے لوگوں کو شریک کرنے اور اسی طریقہ پر ان کی تربیت کرنے کے بھی قابل ہو جائیں۔
(۲) اگر کوئی شخص برضا ورغبت ادارہ کی مالی مدد کرے تو اس کو قبول کر لیا جائے لیکن کبھی خود کسی سے مدد نہ مانگی جائے اور نہ عطایا وصول کرنے کو ادارہ کے پروگرام کا ایک شعبہ بنایا جائے۔
(۳) ادارہ کے تمام ارکان ایسے لوگ ہوں جو انگریزی یا عربی درس گاہوں کی تعلیم سے فارغ ہو چکے ہوں یا جن کی علمی استعداد اعلیٰ درجہ کی ہو ۔ نیز ان میں کوئی ذہانت ‘کوئی اپج‘ کوئی جوہر مخفی پایا جاتا ہو۔ ان امور کی تحقیق کے لیے امیدواروں کو ادارہ کا باقاعدہ رکن بنانے سے پہلے دو مہینہ کے لیے ادارہ میں بلا کر رکھا جائے اور غیر محسوس طریقہ پر ان کو خوب جانچ کر دیکھا جائے۔ ’’مولویت‘‘ اور ’’فرنگیت‘‘ سے پرہیز خصوصاً ضروری ہے۔
(۴) ادارہ میں باقاعدہ درس و تدریس کی ضرورت نہیں۔ عربی جاننے والے ارکان فرداً فرداً انگریزی جاننے والوں کو عربی اور علومِ اسلامیہ پڑھائیں اور اسی طرح انگریزی تعلیم یافتہ حضرات عربی والوں کو انگریزی زبان اور علومِ جدیدہ کی تعلیم دیں۔ ایک وقت ایسا ہو جس میں شیخ قرآن کا درس دے۔ یہ درس اس انداز میں ہونا چاہیے کہ شیخ سمیت ہر شخص معلم بھی ہو اور متعلّم بھی۔ ہر شخص پہلے سے زیر درس آیت یا آیات کی تفسیر میں کافی غور و خوض اورتحقیق و مطالعہ کر کے شریک درس ہو‘ اور درس کے موضوع پر اپنی تحقیق بیان کرے اور دوسروں سے استفادہ کرے۔ یہ ایسا جامع درس ہونا چاہیے کہ اس کے ضمن میں حدیث‘ فقہ‘ حکمت اسلامیہ‘ اصولِ شرع‘ فلسفہ‘ تاریخ اسلامی‘ غرض دنیا بھر کے مباحث و مسائل آ سکتے ہوں۔
درسِ قرآن کے بعدتمام ارکان کو مطالعہ اور تحقیق میں مشغول ہوجانا چاہیے۔ یہ کام سب سے زیادہ اہم اور نازک ہے اور شیخ کی حکمت کا سب سے بڑا صرف یہی ہے۔ اولاً اس کو یہ طے کرنا چاہیے کہ سردست کن کن شعبوں میں تحقیق کا کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ ثانیاً یہ کہ کون کون سے ارکان کس کس شعبہ کے لیے موزوں ہیں۔ ثالثاً یہ کہ ان کی رہنمائی کس ڈھنگ سے کی جائے اور ہر شعبہ میں تحقیق کا نصب العین کیا ہو۔‘‘
دار الاسلام میں مولانا مودودی کی آمد وسط مارچ ۱۹۳۸ء میں ہوئی۔اسکیم کی جزئیات کی ترتیب آہستہ آہستہ عملی شکل اختیار کرنے لگیں۔ اس اثنا میں علامہ اقبال فانی دنیا سے دار البقا تشریف لے جا چکے تھے جن کی غیرموجودگی میں اب یہ ادارہ پورے طور پر مولانا مودودی کے زیرانتظام تھا۔ بورڈ آف ٹرسٹیز میں اگرچہ محمد اسد صاحب بھی تھے لیکن وہ نظر بندی کی وجہ سے معاملات میں دخیل نہ ہو سکتے تھے۔ شومی ٔ قسمت کہ چند ماہ بعد ہی بانی ادارہ اور دوسری جانب منتظم اعلیٰ یعنی مولانا مودودی کے افکار و خیالات میں ٹکرائو ظاہر ہونے لگا۔ چودھری نیاز علی اپنے ذہن میں ایک ادارے کے لیے درس گاہ و خانقاہ کا تصوراور دینی منہج کے حوالے سے مولانا ابوالحسن علی ندوی کے صلاح و اصلاح کے پیراڈائم پر افراد میں اسلامی روح کے نفوذ کو ترجیح دیتے تھے جبکہ مولانا مودودی جدید دنیا میں سیاسی و ثقافتی تبدیلیوں سے متاثر ہو کر تحریکی اور انقلابی اسلام کو مسلمانوں کی نکبت و ادبار سے نکالنے کا متبادل ماڈل پیش کر رہے تھے اور سمجھتے تھے کہ صرف اسی منہج پر محنت کرنے سے اسلام کو عالمی سطح پر غالب قوت بنایا جا سکتا ہے۔ ثانیاً چودھری صاحب کو علامہ اقبالؒ اور قائد اعظم کے افکارِ آزادی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کے مطالبے سے نہ صرف پورا اتفاق تھا بلکہ وہ اپنی کبرسنی کے باوجود پٹھان کوٹ اور اس کے اردگرد آبادیوں میں رائے عامہ ہموار کرنےکے لیے عملاً سعی وجُہد کرتے تھے۔ مولانا مودودی اس پورے سیاسی موقف ہی سے متفق نہیں تھے۔ تصوّرو منہج ِدین اور ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی جدّوجُہد کے حوالے سے اختلاف خلیج کی صورت اختیار کر گیا۔ چنانچہ صرف نوماہ بعد یکم جنوری ۱۹۳۹ء کو مولانا مودودی لاہور منتقل ہو گئے‘ جہاں انہوں نے ۱۹۴۱ء میں جماعت اسلامی کی تأسیس کی۔ تقریباً ساڑھے تین سال بعد۱۵ جون ۱۹۴۲ء کو دوبارہ دارالاسلام تشریف لائے۔ حقیقت یہ ہے کہ چودھری نیاز علی خاں نے باوجود اختلافات کے مولانا مودودی کو بارِ دگر دارالاسلام میں خوش آمدید کہا اور یہ ان کی عالی ظرفی اور بلند حوصلگی کی نمایاں دلیل تھی۔ اگرچہ بظاہر معمولی اختلافات کے پس پردہ جو کلامی مباحث میں جھول اور حکمت عملی کے ضمن میں لی گئی رخصتوں کا معاملہ ہے ان پر متعدد ثقہ علماء کے علاوہ برادر محترم ڈاکٹر اسرار احمدؒ نے بھی مبسوط کتاب تصنیف کی جس کے مطابق تعبیر دین میں خامیوں کے ساتھ حکمت عملی کی ایک بڑی غلطی یہ کی کہ انہوں نے اسلام کے ظاہری پہلو‘ اس کے نظام پر اتنا زور دیا کہ اس کا باطنی پہلو ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جماعت کے ارکان کی تربیت میں ایک بہت بڑی کمی رہ گئی۔(تفصیل کے لیے دیکھیے : ڈاکٹر اسرار احمد ’’تحریک جماعت اسلامی: ایک تحقیقی مطالعہ‘‘ص ۲۲)
آخر میں محمد اسد کا انتہائی قابلِ ستائش اور اخلاقی و انسانی اعتبار سے ازحد دلیرانہ عمل قارئین کے علم میں لانا چاہوں گا۔ تقسیم ِہند کے وقت جو قتل و خون اور فسادات ہوئے وہ اب تاریخ کا حصہ ہیں اور سب کے علم میں ہیں۔ اگست ۱۹۴۷ء میں محمد اسد اپنی فیملی کے ساتھ ڈلہوزی میں تھے اور وہ گورکھا سپاہیوں کے دستے کی حفاظت میں ایک بدرقہ (convoy) کے ساتھ انتہائی خوف اور خطرات سے گزرتے ہوئے تائید ایزدی سے بخیریت لاہور پہنچ گئے۔ انہوں نےنیاز علی خان اور ان کے احباب بارے معلومات بصد دقت حاصل کیں تو معلوم ہوا کہ وہ ابھی جمال پور میں گھرے ہوئے ہیں اور وہ علاقہ بہت غیر متوقع طور پر مشرقی پنجاب کا حصہ بن چکا ہے۔ ان سنگین حالات میں محمد اسد نے واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑا مجاہدانہ فیصلہ کیا اور علامہ اقبال کے بے تکلف احباب میں سے ایک اعلیٰ افسر(جن سے ان کے بھی گہرے دوستانہ مراسم تھے) خواجہ عبد الرحیم(لاہور کی سیاسی شخصیت‘ مرکزی وزیر اور سابق گورنر پنجاب خواجہ طارق رحیم کے والد خواجہ عبدالرحیم (۱۹۰۹ء۔۱۹۷۴ء)۔ ظاہر ہے لاہور میں اولین آمد کے بعد شہر کے عمائدین اور تعلیم یافتہ حضرات میں نومسلم محمد اسد بالعموم ایک کشش رکھتے تھے۔ علامہ اقبال کی وساطت سے بھی ان کا حلقہ تعارف وسیع ہوا۔)سے ایک سرکاری دفتر میں مشتعل لوگوں کے ہجوم میں ملنے میں کامیاب ہو گئے اور ان سےتین لاریوں اور فوجی حفاظتی دستے کی درخواست کی۔ ان کے اصرار پر انتظام ہو گیا اور وہ اگلے روز صبح سویرے شدید خطرات کے علی الرغم جمال پور گئے اور چودھری صاحب‘ ان کے خاندان اور مولانا مودودی اور ان کے متعلقین حضرات کو بحفاظت بارڈر کے اس پار لاہور لائے اور اس طرح نوزائیدہ آزاد مسلم مملکت پاکستان میں نئے عزائم کے ساتھ زندگی کا آغاز کیا۔
محمد اسد اپنے پرچے ’’عرفات‘‘ میں اسلامی نظریاتی کونسل کے خدوخال اور انتظامی ڈھانچے پر اپنے خیالات لکھ کر شائع کرتے رہے تھے۔ چنانچہ قائد اعظم اور پنجاب (مغربی پنجاب) کے چیف منسٹر نواب افتخار حسین ممدوٹ کی خواہش پر انہیں لاہور میں ’’Department of Islamic Reconstruction‘‘ قائم کرنے اور ڈائریکٹر کی حیثیت سے مختلف معاملات بالخصوص آئینی‘ اقتصادی‘ تعلیمی اور ایڈمنسٹریشن کے ضمن میں وضاحت سے قابلِ عمل اسٹریٹجی سامنے لانے کا ٹاسک دیا گیا۔ دوسری جانب کراچی میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ملک کی وزارت خارجہ میں مشرق وسطیٰ اور دوسرے اسلامی ممالک میں سفارت کاری اور یو این او میں اچھی انگریزی زبان کے ساتھ عربی زبان پر دسترس رکھنے والے کسی اہم شخص کی ضرورت تھی‘ اور اس حوالے سے ان کی نظر محمد اسد پر پڑی۔ چنانچہ انہیں لاہور سے کراچی بلا کر فارن آفس کے مڈل ایسٹ ڈویژن میں سیکرٹری کا اہم عہدہ دیا گیا۔ لاہور کے اسلامک ری کنسٹرکشن اور بعد ازاں فارن سروس اور یو این او کے نیویارک اور پیرس سیشن کے دوران قادیانی وزیرخارجہ سر ظفر اللہ اور مستقل مندوب احمد شاہ بخاری کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اواخر ۱۹۵۱ء میں پاکستان سے ہجرت کر کے مراکش (تنجا) میں نقل مکانی کر لی تاکہ وہ صحیح بخاری اور قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ اور حواشی سکون اور دلجمعی کے ساتھ کر سکیں۔۵۸ / ۱۹۵۷ء میں مختصر قیام کےلیے وہ لاہور تشریف لائے اور پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام عالمی اسلامک کلوکیم کوآرگنائز کرنے میں مدد دی اور تمام شرکاء سے ملاقات کی۔ اس سفر میں انہوں نے جوہر آباد جا کر اپنے پرانے ممدوح اور محسن چودھری نیاز علی خاں سے ملاقات بھی کی اور ان کے حال احوال دریافت کیے۔ دوسری بار وہ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کی خصوصی دعوت پر اسلام آباد آئے۔ جنرل صاحب کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے ’’شوریٰ‘‘ میں نامزدگی کی بنیاد hand-picked ممبران کی مخالفت کی جو نوٹ کر لی گئی۔ صدر ضیاء الحق کی حادثاتی موت پر انہیں بہت افسوس ہوا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ محمد اسد نے اپنی آخری کتاب The Laws of Quran and other Essays میں اسلامی شریعت کے متعلق انتہائی اہم مباحث اٹھائے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں سے درگزر کریں اور انہیں اپنے مقربین میں جگہ دیں۔ آمین!