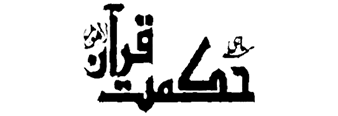(تذکر و تدبر) مِلاکُ التأوِیل (۴۲) - ابو جعفر احمد بن ابراہیم الغرناطی
9 /مِلاکُ التأوِیل (۴۲)تالیف : ابوجعفر احمد بن ابراہیم بن الزبیرالغرناطی
تلخیص و ترجمانی : ڈاکٹر صہیب بن عبدالغفار حسنسُورۃُ النُّوْر
(۲۶۹) آیت ۱۰
{وَلَوْ لَا فَضْلُ اللہِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُہٗ وَاَنَّ اللہَ تَوَّابٌ حَکِیْمٌ(۱۰)}
’’اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔‘‘
اور اس کے بعد آیت۲۰ میں ارشاد فرمایا:
{وَلَوْلَا فَضْلُ اللہِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُہٗ وَاَنَّ اللہَ رَئُ وْفٌ رَّحِیْمٌ(۲۰)}
’’اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت والا اور مہربان ہے۔‘‘
سوال یہ ہے کہ دونوں آیتوں کا مضمون ایک جیسا ہے لیکن دونوں آیتوں کا اختتام مختلف ہے۔ بایں طور کہ دونوں میں اللہ تعالیٰ کی الگ الگ صفات بیان کی گئی ہیں۔
اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت لِعان کے بارے میں ہے‘ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زناکاری کی تہمت لگائے لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو اُسےقاضی کے سامنے چار دفعہ قسم اٹھانا ہو گی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اور پانچویں دفعہ یہ الفاظ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد اس کی بیوی سے بھی یہی مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ ایسے ہی چار قسمیں کھائے کہ آدمی جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ الفاظ کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو اس (عورت) پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اگر وہ یہ قسم اٹھا لیتی ہے تو پھر دونوں پر کوئی حد نافذ نہیں ہو گی۔
لِعان کے اس قاعدے کے ذریعے ایسے مسلمانوں پر پردہ ڈالا گیا ہے جو اس قسم کی مصیبت میں مبتلا ہوجائیں۔ ان کے جرم کی تشہیر نہیں کی جاتی‘ اور یہ ایسا حکم ہے کہ جس کی حکمت کا ادراک بہت کم لوگ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ مناسب تھا کہ آیت کااختتام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات تواب اور حکیم پر ہو (یعنی ایک طرف توبہ کی تلقین کی گئی اور دوسری طرف اس قاعدے کی حکمت کی جانب اشارہ ہو گیا)۔
اب رہی دوسری آیت تو اس سے قبل ارشاد فرمایا تھا:
{اِنَّ الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِیْعَ الْفَاحِشَۃُ فِی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ لا فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَۃِط} (آیت۱۹)
’’جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ‘ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔‘‘
اس آیت میں عَذَابٌ اَلِیْم کی جو وعید بتائی گئی ہے وہ دل دہلانے کے لیے کافی ہے لیکن اہل ایمان کے لیے امید کی ایک کرن باقی رکھی گئی ہے‘ یعنی اللہ تعالیٰ رئوف اوررحیم ہے۔ اُس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے اور جو صدقِ دل سے توبہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ضرور جوش میں آئے گی۔ اور جو توبہ نہیں کرتا تو اُسے دنیاوآخرت میں دردناک عذاب ہو گا‘ لیکن وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ‘اِلّا یہ کہ وہ شخص اس بات کا اعتقاد رکھتا ہو کہ ایسا کرنا اس کے لیے حلال ہے ‘ یا وہ اس وعید ہی کا انکار کرتا ہو‘ یا پھر اس عمل (یعنی بے حیائی) کی آڑ میں کسی کفر کا ارتکاب کر رہا ہو۔ اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ ہر دو آیات کا اختتام اپنی اپنی جگہ پر عین مناسبت رکھتا ہے۔
اب یہاں اس بات کی بھی وضاحت ہو جائے (جس کا موضوعِ بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے) کہ دونوں آیتیں جملہ شرطیہ ہیں کہ ’’اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا‘‘تو پھر کیا ہوتا! یعنی دونوں آیتوں میں شرط کا تو ذکر ہے لیکن جوابِ شرط مذکور نہیں۔ دراصل بعض دفعہ طولِ کلام کی بنا پر جوابِ شرط حذف کر دیا جاتا ہے‘ اس لیے کہ سیاق و سباق سے اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اگر اُسے ظاہر کیا جاتا تو اسے پہلی آیت میں یوں بتایا جاتا کہ ’’پھر تمہیں فضیحت کا سامنا کرنا پڑتا یا تم مشقت میں جا پڑتے‘‘ اور دوسری آیت میں یہ کہا جاتا کہ ’’پھر تمہیں عذاب آلیتا‘‘ ۔بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہاں کیا مراد لیا جائے۔
(۲۷۰) آیت۵۸
{کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللہُ لَکُمُ الْاٰیٰتِ ط وَاللہُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ(۵۸)}
’’اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح کرتا ہے۔ اور اللہ جاننے والا ‘ حکمت والا ہے۔‘‘
اور پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا:
{وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَاْذِنُوْا کَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہِمْ ط کَذٰلِکَ یُبَیِّنُ اللہُ لَکُمْ اٰیٰتِہٖ ط وَاللہُ عَلِیْمٌ حَکِیْمٌ(۵۹)}
’’اور جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ اسی طرح اجازت لیں جیسے ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے‘ اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔‘‘
سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ پہلی آیت کے آخر میں صرف ’’الْاٰیٰتِ‘‘ کہا گیا اور دوسری آیت میں ’’اٰیٰتِہٖ‘‘(ضمیر کے ساتھ)کہا گیا تو اس فرق کی وجہ کیا ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عبارت ایک ہی ہو اور اس میں ایک لفظ دوبارہ لایا جائے تو بعینہٖ وہی لفظ نہیں لایا جاتا تاکہ سامع کو بوجھ نہ محسوس ہو۔ شعر و شاعری میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے ‘ ہاں اگر لفظ کو مکرر لانے کا کوئی اور سبب ہو تو پھر ایسا کرنا جائز ہے۔
یہاں پہلی آیت میں لفظ’’الْاٰیٰتِ‘‘الف لام کے ساتھ لایا گیا‘ اسے ’’الف لام بغرضِ عہد‘‘کہا جاتا ہے‘ یعنی کلام میں اتنے اشارات موجود ہیں جن سے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ’’آیات‘‘ سے کیا مراد ہے>؟ [جیسے آغاز سورۃ البقرۃ میں ارشاد فرمایا: {الٓـمّ(۱) ذٰلِکَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ ج فِیْہِ ج } الْکِتٰب کا الف لام ‘عہد کے لیے ہے کہ ہر شخص جونہی یہ آیت پڑھے گا‘ اس کے ذہن میں کتاب سے مراد قرآن مجید ہی ہو گا۔ (اضافہ از مترجم)]
دوسری آیت میں ’’اٰیٰتِہٖ‘‘ کہہ کر اس کی نسبت بتا دی کہ پچھلی آیت میں جن ’’آیات‘‘ کا بیان ہوا تھا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔گویا جو بات پہلے سے معلوم تھی اس کی مزید تاکید ہو گئی۔ واللہ اعلم!
اس کی ایک مثال سورۃ البقرۃ میں بھی گزر چکی ہے۔ آیت۲۱۹ میں ارشاد فرمایا:
{کَذٰلِکَ یُـبَـیِّنُ اللہُ لَـکُمُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّـکُمْ تَتَفَکَّرُوْنَ(۲۱۹)}
اور آیت ۲۲۱ میں ارشاد فرمایا:
{وَیُـبَـیِّنُ اٰیٰـتِہٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّہُمْ یَتَذَکَّرُوْنَ(۲۲۱)}
اور یہاں بھی یہی اسلوبِ بیان اختیار کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم!
سُورۃُ الفُرْقان
(۲۷۱) آیت۳
{وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِہٖٓ اٰلِہَۃً لَّا یَخْلُقُوْنَ شَیْئًا وَّہُمْ یُخْلَقُوْنَ }
’’اور انہوں نے اُس(اللہ) کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنالیے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے
گئے ہیں۔‘‘
اور سورئہ یٰسٓ میں ارشاد فرمایا:
{وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللہِ اٰلِہَۃً لَّعَلَّہُمْ یُنْصَرُوْنَ(۷۸) }
’’اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنائے‘ شاید کہ ان کی مدد ہو سکے ۔‘‘
سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ پہلی آیت میں ’’دُوْنِہٖ‘‘ کہہ کر صرف ضمیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے اور دوسری آیت میں ’’دُوْنِ اللہِ‘‘ کہہ کر اللہ کے نام کو ظاہر کیا گیا‘ تو اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ الفرقان کی آیت سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر بطور کنایہ آٹھ دفعہ آیا ہے۔ ارشاد فرمایا:
{تَبٰرَکَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی عَبْدِہٖ لِیَکُوْنَ لِلْعٰلَمِیْنَ نَذِیْرَنِا(۱)}
’’برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کو اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کو خبر دار کرنے والا بن جائے۔‘‘
{الَّذِیْ لَہٗ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَکُنْ لَّہٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَخَلَقَ کُلَّ شَیْ ئٍ فَقَدَّرَہٗ تَقْدِیْرًا(۲)}
’’جس کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے اور جس نے ہرچیز کو پیدا کیاتو پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا۔‘‘
آٹھ دفعہ (اللہ تعالیٰ کا) ذکر آنے کی تفصیل اس طرح ہے :
الَّذِیْ : اسم موصول جو ’’تَبَارَکَ‘‘سے متعلق ہے۔
نَزَّلَ : یہاں ضمیر (وہ) سے اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔
عَبْدِہٖ : یہاں بھی ’’ہ ‘‘کی ضمیر متصل سے اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔
الَّذِیْ لَہٗ : اسم موصول اور پھر ’’لَہٗ‘‘ کی ضمیر ‘ دونوں اللہ کی بابت ہیں۔
لَمْ یَتَّخِذْ : یہاں بھی ’’نَزَّلَ‘‘ کی طرح ضمیر مستتر ہے‘ یعنی فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔
لَہٗ : ضمیر جو اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔
خَلَقَ : ضمیر مستتر‘ جو کہ فاعل ہے اور جس سے مراد اللہ ہے۔
[بلکہ ’’فَقَدَّرَہٗ‘‘ میں بھی ضمیر مستتر ’’خَلَقَ‘‘ کی طرح موجود ہے: از مترجم ]
جب اللہ تعالیٰ کا بطور کنایہ آٹھ مرتبہ ذکر آ گیا تو اگلی آیت میں بھی ’’مِنْ دُوْنِہٖ‘‘ کہہ کر اسی اسلوب میں ضمیر لائی گئی کہ جس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
جہاں تک سورئہ یٰسٓ کی آیت کا تعلق ہے تو اس سے قبل ارشاد فرمایا:
{ اَلَمْ اَعْہَدْ اِلَیْکُمْ یٰــبَنِیْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّیْطٰنَ ج اِنَّہٗ لَـکُمْ عَدُوٌّ مُّبِیْنٌ(۶۰)}
’’اے بنی آدم! کیا میں نے تم سے یہ قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا‘ بے شک وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔‘‘
یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ضمیر کا لانا غیر مناسب تھا‘ کہ مذکورہ آیت میں شیطان اور اس کی عبادت نہ کرنے کا ذکر تھا۔ اگر ضمیر لائی جاتی تو پھر آیت میں التباس (غلط فہمی) پیدا ہو سکتا تھا۔اس لیے ہر دو آیات اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک مناسبت رکھتی ہیں۔
سُورۃُ الشُّعْرَاء
(۲۷۲) آیت۵۰
{قَالُوْا لَا ضَیْرَ ز اِنَّآ اِلٰی رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ(۵۰)}
’’انہوںنے کہا: کوئی حرج نہیں! بے شک ہم اپنے ربّ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔‘‘
اور سورۃ الزخرف میں ارشاد فرمایا:
{وَمَا کُنَّا لَہٗ مُقْرِنِیْنَ(۱۳) وَاِنَّآ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ(۱۴)}
’’اور ہمیں اسے قابو میں لانے کی طاقت نہیں تھی‘ اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔‘‘
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں صرف ’’مُنْقَلِبُوْنَ‘‘ کہا گیا اور دوسری آیت میں لامِ تاکید کے اضافے کے ساتھ’’ لَمُنْقَلِبُوْنَ ‘‘کہا گیا تو اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں جادوگر فرعون کو جواب دیتے نظر آتے ہیں۔ فرعون کے یہ الفاظ قرآن میں نقل کیے گئے ہیں:
{لَاُقَطِّعَنَّ اَیْدِیَکُمْ وَاَرْجُلَکُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّکُمْ اَجْمَعِیْنَ(۴۹) } (الشُّعراء)
’’میں تمہارے ہاتھ پائوں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔‘‘
اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا : ’’ لَا ضَیْرَ‘‘ کوئی پرواہ نہیں! ’’اِنَّآ اِلٰی رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ‘‘ یعنی اگر تم نے ایسا کیا تو ہم اپنے ربّ کی طرف لوٹنے والے ہیں جو ہمارے صبر کا بدلہ ہمیں عطا کرے گا۔ گویا وہ اس امید کے ساتھ جواب دے رہے تھے کہ جس میں تسلی بھی ہے‘ ثواب کی امید بھی ہے‘ اور یہ بھی کہ اگر ان کے ربّ نے ان کا امتحان لینا ہی ہے تو وہ صابر وشاکر رہیں گے۔ چنانچہ یہاں نہ قسم کا موقع ہے اور نہ ہی تاکید کا‘ بلکہ اُمید کا دامن تھامے رکھنے کا عندیہ ہے۔
اس کے مقابلے میں سورۃ الزخرف کا سیاق و سباق بالکل مختلف ہے‘ وہاں عرب کے مشرکین کے بارے میں یہ الفا ظ آئے:
{وَلَئِنْ سَاَلْتَہُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَیَقُوْلُنَّ خَلَقَہُنَّ الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ(۹)}
’’اور اگر تم ان سے سوال کرو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ یقیناً کہیں گے: انہیں تو عزیز و علیم (غالب اور علم والی) ہستی نے پیدا کیا ہے۔‘‘
اور ان کے اس اقرار سے انہی پر حُجّت قائم کرنا مقصود ہے کہ پھر تم دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کیوں کرتے ہو؟
یہ تو مشرکین کا طرزِعمل تھا کہ وہ تاکیدی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خالق ارض و سماء ہونے کا اقرار تو کررہے ہیں لیکن دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر بھی ہیں۔ اس کے تقابل کے طور پر اہل ایمان کا طرزِعمل بتایا گیا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ بجا لاتے ہیں اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے سواری اور باربرداری کے لیے جن حیوانات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے‘ تو ان پر سوار ہوتے وقت وہ اسی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ آیت کا آغاز یوں ہوتا ہے :
{ لِتَسْتَوٗا عَلٰی ظُہُوْرِہٖ ثُمَّ تَذْکُرُوْا نِعْمَۃَ رَبِّکُمْ اِذَا اسْتَوَیْتُمْ عَلَیْہِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا ہٰذَا وَمَا کُنَّا لَہٗ مُقْرِنِیْنَ(۱۳) وَاِنَّآ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ(۱۴)}
’’تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو‘ پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم اس پر جم کر بیٹھ جائو اور پھر کہو: پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے حالانکہ ہمارے بس میں نہ تھا کہ ہم اس پر قابو پا سکیں ‘اور بے شک ہم اپنے ربّ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔‘‘
ملاحظہ ہو کہ پہلے’’وَمَا کُنَّا لَہٗ مُقْرِنِیْنَ ‘‘میں ایک طرح سے قسم کا شائبہ ہے‘ پھر ’’ اِنَّا‘‘ میں ضمیر ’’نا‘‘ سے قبل ’’اِنَّ‘‘ بطور تاکید شامل ہے‘ اور پھر لام تاکید’’لَمُنْقَلِبُوْنَ ‘‘میں لایا گیا جو مشرکین کے اعتقاد کی نفی کر رہا ہے۔ گویا اہل ایمان یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم! اللہ کی ذات حق ہے۔ یہاں لامِ تاکید کا لایا جانا بالکل مناسب تھا‘ جب کہ سورۃ الشعراء کی آیت میں اس کا نہ لایا جانا ہی مناسبت رکھتا تھا۔ واللہ اعلم!
(۲۷۳) آیات۶۹تا۷۱
{وَاتْلُ عَلَیْہِمْ نَبَاَ اِبْرٰہِیْمَ (۶۹) اِذْ قَالَ لِاَبِیْہِ وَقَوْمِہٖ مَا تَعْبُدُوْنَ(۷۰) قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَہَا عٰکِفِیْنَ(۷۱)}
’’اور انہیں ابراہیم کی خبر بھی سنا دو‘ جب اُسؑ نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان پر مجاور بنے بیٹھے رہتے ہیں۔‘‘
اور سورۃ الصافات میں ارشاد فرمایا:
{وَاِنَّ مِنْ شِیْعَتِہٖ لَاِ بْرٰہِیْمَ(۸۳) اِذْ جَآئَ رَبَّہٗ بِقَلْبٍ سَلِیْمٍ(۸۴) اِذْ قَالَ لِاَبِیْہِ وَقَوْمِہٖ مَا ذَا تَعْبُدُوْنَ(۸۵) اَئِفْکًا اٰلِہَۃً دُوْنَ اللہِ تُرِیْدُوْنَ(۸۶) فَمَا ظَنُّکُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ(۸۷) }
’’اوراُس (نوحؑ) کی جماعت میں سے ابراہیم تھے۔جب وہ ایک صاف شفاف دل کے ساتھ اپنے رب کے پاس آئے۔جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا: تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے خدائوں کو پوجتے ہو؟ تو پھر تم تمام جہانوں کے رب کے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟‘‘
یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی آیت میں’’ مَا تَعْبُدُوْنَ ‘‘ کا لفظ تھا اور دوسری آیت میں مَا کے ساتھ ’’ذَا‘‘ کا بھی اضافہ ہے یعنی ’’ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ‘‘کہا تو اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں رسولوں اور ان کی اُمتوں کے واقعات ایک خاص ڈگر پر نہیں بیان ہوئےکہ انہیں کیسے دعوت دی‘ ان کے کیا سوال وجواب تھے‘ ان سے بات چیت کی نوعیت کیا تھی؟ یہ سب وہ باتیں ہیں جو قوموں کے حالات اور واقعات کے اختلاف کی بنا پر مختلف ہو سکتی ہیں‘ ہر مقام پر اس کا ایک خاص طرزِ بیان ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قصے میں صرف دین کی طرف بلانے کا‘ اس کے دلائل کا اور نافرمانی کی شکل میں اس کے نتائج کا بیان ہوتا ہے۔ لوگوں نے کیا جواب دیا‘ اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ صرف اتنا بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے انکار کیا تھا۔ کبھی اختصار کے ساتھ ان حُجّت بازیوں کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے جو مختلف قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیں اور کبھی یہ بیان خوب تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلی قسم میں سورۃ الصافات کی آیات آتی ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے جس کا آغاز بایں طور ہے کہ قوم سے متوجہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام یہ سوال کرتے ہیں:
{مَا ذَا تَعْبُدُوْنَ} ’’تم کس کی عبادت کرتے ہو؟‘‘
ان کی طرف سے کوئی خاص حُجّت بازی نہیں ہوئی سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا تھا:
{قَالُوا ابْنُوْا لَہٗ بُنْیَانًا فَاَلْقُوْہُ فِی الْجَحِیْمِ (۹۷) }
’’اس کے لیے ایک عمارت بنائو اور اسے دہکتی آگ (کے الائو) میں پھینک دو۔‘‘
اور یہاں بھی کوئی سوال و جواب نہیں ہے‘ صرف اپنی من مانی کا اظہار ہے۔
دوسری قسم میں سورۃ الشعراء کی آیات ہیں‘ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سوال(مَا تَعْبُدُوْنَ) کے جواب میں قوم کا یہ جملہ نقل کیا گیا ہے :
{نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَہَا عٰکِفِیْنَ(۷۱)}
’’ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان پر مجاور بنے بیٹھے رہتے ہیں۔‘‘
پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خاموش کر دینے کے لیے ڈانٹ پلانے کے انداز میں کہا:
{ ہَلْ یَسْمَعُوْنَکُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ(۷۲) اَوْ یَنْفَعُوْنَکُمْ اَوْ یَضُرُّوْنَ(۷۳) }
’’کیا جب تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہیں سنتے بھی ہیں ؟ یا کیا وہ تمہیں نفع یانقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟‘‘
تو وہ صرف اتنا جواب دے پائے:
{ بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآئَ نَا کَذٰلِکَ یَفْعَلُوْنَ(۷۴) }
’’(نہیں! )بلکہ ہم نے تو اپنے آباء واَجداد کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا۔‘‘
تیسری قسم میں سورئہ ہود اور اس سے ملتی جلتی سورتوں میں شعیب علیہ السلام کا قصہ شامل ہے جو بہت تفصیل سے بیان ہواہے۔ اگر آپ قرآن کریم میں بیان کردہ قصوں کا مطالعہ کریں گے تو انہی تین قسموں کوپائیں گے۔ اب اگر سورۃ الشعراء اور سورۃ الصافات دونوں کا مقابلہ کیاجائے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ سورۃ الصافات میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات چیت کا ذکر ہے وہاں کچھ تفصیل بھی ہے‘ انہیں سرزنش بھی کی گئی ہے :{اَئِفْکًا اٰلِہَۃً دُوْنَ اللہِ تُرِیْدُوْنَ(۸۶) }’’کیا اللہ کو چھوڑ کر مَن گھڑت خدائوں کو پوجتے ہو؟‘‘اور یہ بھی کہا:{اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ(۹۵)} ’’ کیا تم انہیں پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو!‘‘تو وہ کوئی جواب نہ دے سکے‘ صرف ان کا ایک قول نقل کیا گیا:{ابْنُوْا لَہٗ بُنْیَانًا فَاَلْقُوْہُ فِی الْجَحِیْمِ(۹۷)} ’’اس کے لیے ایک عمارت بنا دو اور پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں اسے پھینک دو۔‘‘
یہاں ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی طوالت دیکھتے ہوئے ’’مَا‘‘ کے ساتھ اسم اشارہ ’’ذَا‘‘ کا اضافہ مناسب تھا۔اس کے مقابلے میں سورۃ الشعراء میں قوم کی طرف سے جواب در جواب نقل کیے گئے ہیں۔ تو یہاں مناسب تھا کہ اسم اشارہ (ذَا) کو نہ لایا جاتا صرف ’’مَا‘‘ بطور استفہام لایا جاتا۔نحوی لحاظ سے ’’مَا تَعْبُدُوْنَ‘‘ جملہ فعلیہ ہے۔ ’’مَا‘‘ مفعول متقدم ہے‘ اس لیے ’’مَا‘‘ محل نصب میں ہے (بحیثیت مفعول) اور ’’مَاذَا تَعْبُدُوْنَ‘‘ میں ’’مَاذَا ‘‘ کو اگر ایک کلمہ شمار کیا جائے تو وہ بھی مفعول ہونے کی بنا پر محل نصب میں ہو گا۔ لیکن اگر اسے دو کلمات سمجھا جائے‘ تو ’’مَا‘‘ استفہام کے لیے ہے‘ اور مبتدأ ہے۔ ’’ذَا‘‘ اسم ہے جوکہ خبر ہونے کی وجہ سے محل رفع میں ہے (کیونکہ خبر یہاں مرفوع ہے) اورپھر ’’تَعْبُدُوْنَ‘‘ (فعل اور فاعل ملا کر) پورا ایک جملہ ہے جسے خبر کا صلہ کہا جائے گا۔ اور مبتدأ اور خبر پر مشتمل جملہ جو ’’قَالَ‘‘ کے بعد آ رہا ہے ’’قول‘‘ کے معنی میں ہے (یعنی کیا کہا؟) گویا یہ سوال کیا تھا: اَیّ شیء الذی تعبدونہ؟ ’’وہ کیا چیز ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟‘‘ واللہ اعلم!
[اضافہ از مترجم:مؤلف کتاب نے جس انداز میں ’’مَا‘‘ اور’ ’مَاذَا‘‘ کے فرق کو سمجھانے کی کوشش کی ہے‘ وہ مزید الجھن کا شکار کر دیتی ہے‘ لیکن ابن عاشور نے اپنی تفسیر میں اسے بڑی آسانی سے حل کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سورۃ الشعراء میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم سے یوں سوال کر رہے ہیں جیسا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ وہ کس کی پوجا کررہے ہیں (اسے تجاہل عارفانہ کہا جائے گا)۔ گویا ان کا مقصد تھا کہ جب وہ میرے سوال کا جواب دیں گے تو میں مزید سوال کروں گا اور پھر انہیں قائل کر سکوں گا کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بے سود اور لاحاصل ہے اور یہی انداز سورۃ الانبیاء میں بھی اپنایا گیا ہے۔
اور سورۃ الصافات کہ جہاں ’’مَاذَا‘‘ سے کلام شروع ہوتا ہے‘ یہاں استفہامِ انکاری ہے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودات کے بارے میں خوب علم رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ انکار کے لہجے میں مخاطب ہیں کہ یہ جو تمہارے خدا ہیں‘ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ یعنی یہ تو اس لائق ہی نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اور پھر دوسرا انکاری سوال جڑ دیاکہ کیا اللہ کو چھوڑ کر اپنے مَن گھڑت خدائوں کی پوجا کرتے ہو؟تو واضح ہو گیا کہ ’’مَا‘‘ استفہامیہ کے بعد ’’ذَا‘‘ اسم موصول ہے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کے مشاہدے میں ان کے سارے کے سارے دیوتا ہیں‘ وہ ان کے بارے میں سوال نہیں کر رہے بلکہ انکارکے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ مَن گھڑت دیوتا ہی تمہاری عبادت کے لائق ہیں؟ خلاصۂ کلام یہ ہوا کہ سورۃ الشعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال و جواب دعوت کے ابتدائی مراحل کا ہے اور سورۃ الصافات کا سوال وجواب بعد کے مراحل کا ہے۔]
(۲۷۴) آیات۷۸ تا ۸۱
{الَّذِیْ خَلَقَنِیْ فَہُوَ یَہْدِیْنِ(۷۸) وَالَّذِیْ ہُوَ یُطْعِمُنِیْ وَیَسْقِیْنِ(۷۹) وَاِذَا مَرِضْتُ فَہُوَ یَشْفِیْنِ(۸۰) وَالَّذِیْ یُمِیْتُنِیْ ثُمَّ یُحْیِیْنِ(۸۱)}
’’وہی (اللہ) ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو وہی مجھے ہدایت دیتا ہے‘۱ ور وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اورپلاتا بھی ہے‘ اور جب میں بیمار پڑ جاتاہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے‘ اور وہی ہے جو مجھے موت دیتا ہے پھر مجھے زندہ کرتا ہے۔‘‘
یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تین افعال (ہدایت‘ کھانا پلانا‘ شفا دینا) میں ’’ھُوَ‘‘ کی ضمیر لائی گئی ہے‘ یعنی ان افعال کا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے‘ لیکن آخری آیت جس میں مارنے اور زندہ کرنے کا تذکرہ ہے تو یہاں یہ ضمیرنہیں لائی گئی تو اس کا کیا سبب ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک مارنے اور زندہ کرنے کا تعلق ہےتو کوئی شخص بھی اس کام پر قدرت نہیں رکھتا۔ لیکن جہاں تک کھانے پلانے وغیرہ کا تعلق ہے تو ایک بے بصیرت شخص یہ گمان کر سکتا ہے کہ یہ کام تو لوگ بھی کر سکتے ہیں‘ صرف اللہ کے ساتھ تویہ کام خاص نہیں ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں نے مجھے کھلایا اور پلایا‘ اور پھر وہ اسے حقیقی معنوں میں لیتے ہیں ‘ حالانکہ ایسا بطور مجاز بولا جاتا ہے‘جبکہ یہ نہیں کہا جاتا کہ فلاں نے مار دیا یا فلاں نے زندہ کر دیا اور اگر کہہ بھی دیاجائے تو اسے مجاز پر محمول کیا جاتا ہے۔
چونکہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کیا جاتا کہ موت دینا یا مردہ کو زندہ کرنا صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اس لیے یہاں ضمیر لانے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی‘ برخلاف کھلانے اور پلانے کے‘ کہ چونکہ اس میں شک و شبہ واقع ہو سکتا ہے (کہ انسان بھی اس پر قادر ہے) اس لیے ضمیرکا لانا ضروری تھا تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے کہ حقیقی طور پر کھانا پلانا‘ مریض کو شفا دینا‘ ہدایت کی توفیق بخشنا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مزید وضاحت سورۃ النجم کے تحت ذکر کی جائے گی۔
(۲۷۵) آیت۱۵۴
یہاں صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے جب انہوں نے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا:
{مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَاج فَاْتِ بِاٰیَۃٍ اِنْ کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ(۱۵۴) }
’’تم ہم جیسے ایک بشر ہی تو ہو‘ اگر سچے ہو تو پھر کوئی نشانی لے کر آئو!‘‘
اور شعیب علیہ السلام کے قصے میں قومِ شعیب کا ایسا ہی قول یوں نقل کیا گیا:
{وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا} (آیت۱۸۶) ’’اور تم ہم جیسے ایک بشر ہی تو ہو۔‘‘
سوال یہ ہے کہ اس آیت کے شروع میں واو عطف کا اضافہ ہے جو صالح علیہ السلام کی بابت نہیں کیا گیا؟
اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں آیات کی باہم دگر مناسبت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ قومِ شعیبؑ کے قصے میں ابتدائی آیات ملاحظہ ہوں جن میں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو باندازِ نصیحت کئی چیزیں گنوائی ہیں۔ فرمایا:
{اَوْفُوا الْکَیْلَ وَلَا تَکُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِیْنَ(۱۸۱)}
’’ناپ پورا کیا کرو اور کم تولنے والوں میں سے نہ بنو۔‘‘
{وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیْمِ(۱۸۲)}
’’اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو۔‘‘
{وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیَآئَ ہُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ(۱۸۳)}
’’اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھاٹے سے نہ دو اور زمین میں بے باکی سے فساد نہ پھیلائو۔‘‘
{وَاتَّقُوا الَّذِیْ خَلَقَکُمْ وَالْجِبِلَّۃَ الْاَوَّلِیْنَ(۱۸۴)}
’’اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پچھلے لوگوں کو۔‘‘
یہاں پانچ مرتبہ اُن خصال میں واو عطف لایا گیا ہے جن کاتعلق امر اور نہی سے ہے‘ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب نقل کیا تو اس میں اسی اسلوب کے ساتھ مطابقت کا لحاظ رکھتے ہوئے واوِ عطف لایا گیا:
{قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِیْنَ(۱۸۵)}
’’انہوں نے کہا: بے شک تُو اُن میں سے ہے جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔‘‘
{وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّکَ لَمِنَ الْکٰذِبِیْنَ(۱۸۶)}
’’اور تم ہم جیسے ایک انسان ہی تو ہو‘ اور ہم پورے یقین کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔‘‘
اور یوں واوِ عطف لانے کی مناسبت واضح ہو جاتی ہے۔
اب ذرا صالح علیہ السلام کے بارے میں وارد آیات پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا:
{اَتُتْرَکُوْنَ فِیْ مَا ہٰہُنَآ اٰمِنِیْنَ(۱۴۶)}
’’کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جائو گے؟‘‘
{فِیْ جَنّٰتٍ وَّعُیُوْنٍ(۱۴۷) وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُہَا ہَضِیْمٌ(۱۴۸)}
’’ان باغوں اور چشموں میں‘ اور ان کھیتوں اور کھجوروں کے باغات میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں!‘‘
{وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوْتًا فٰرِہِیْنَ(۱۴۹)}
’’اور تم پہاڑوں کو تراش خراش کر کے پُرتکلف مکانات بناتے ہو۔‘‘
{فَاتَّقُوا اللہَ وَاَطِیْعُوْنِ(۱۵۰)}
’’تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔‘‘
{وَلَا تُطِیْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِیْنَ(۱۵۱)}
’’اور اسراف کرنے والوں کی باتیں نہ مانو۔‘‘
{الَّذِیْنَ یُفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ وَلَا یُصْلِحُوْنَ(۱۵۲)}
’’جو زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔‘‘
یہاں ان تمام آیات میں سوائے ایک ایک آیت کے کوئی امر اور نہی بیان نہیں ہوا: {فَاتَّقُوا اللہَ وَاَطِیْعُوْنِ(۱۵۰) وَلَا تُطِیْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِیْنَ(۱۵۱)} اس لیے جب قوم کا جواب آیا تو اس میں صرف بشریت کے ساتھ مماثلت کا انکار بیان ہوا اور اسے بطور معطوف نہیں لایا گیا‘ صرف کہا گیا:{وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا}۔ اور اس طرح واضح ہو گیا کہ ہر دو آیات اپنی اپنی جگہ پوری مناسبت رکھتی ہیں۔ واللہ اعلم!
سُورۃُ النَّمْل
(۲۷۶) آیات ۱۰۔۱۱
{فَلَمَّا رَاٰہَا تَہْتَزُّ کَاَنَّہَا جَآنٌّ وَّلّٰی مُدْبِرًا وَّلَمْ یُعَقِّبْ ط یٰمُوْسٰی لَا تَخَفْقف اِنِّیْ لَا یَخَافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُوْنَ(۱۰) اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا م بَعْدَ سُوْٓئٍ فَاِنِّیْ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ(۱۱) }
’’اور جب انہوں نے عصا کو ہلتے دیکھا گویا کہ وہ ایک سانپ ہو تو پیٹھ پھیر کے بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ (ارشاد ہوا:)اے موسیٰ! ڈرو مت‘ میرے حضو ررسول ڈرا نہیں کرتے ۔ مگر یہ کہ کوئی شخص ظلم کرے اور پھر برائی کے بعد اچھائی کرے تو مَیں بخشنےو الا ‘مہربان ہوں۔‘‘
اور سورۃ القصص میں ارشاد فرمایا:
{ یٰمُوْسٰٓی اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْقف اِنَّکَ مِنَ الْاٰمِنِیْنَ(۳۱)}
’’اے موسیٰ !آگے بڑھو اور ڈرو مت‘ تم امن و امان والوں میں سے ہو۔‘‘
سورۃ القصص کی اس آیت سے قبل بھی وہی الفاظ بیان ہوئے ہیں جو سورۃ النمل میں وارد ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب قصہ ایک ہے جو کہ ابتدائے نبوت میں آپ ؑکے ساتھ پیش آیا تھا تو پھرآیت کے اختتامی الفاظ میں اختلاف کیوں واقع ہوا ہے؟
جواباً عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق اور حفاظت کا طالب ہوں‘ کہ جیسے ہم سورئہ طٰہٰ میں بیان کر چکے ہیں کہ جہاں تک ان قصوں کا تعلق ہے تو وہاں ہوبہو الفاظ نقل نہیں کیے جاتے بلکہ معانی و مطالب کو نقل کیا جاتا ہے‘ اور وہ اس لیے کہ قرآن اہل ِعرب پر نازل ہوا تھا‘ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی زبان عبرانی تھی۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سُنّت کا بیان کیا ہے :
{وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِہٖ } (ابراھیم:۴)
’’اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اُسی کی قوم کی زبان میں۔‘‘
اور ہمارے ربّ کا کلام حرف اور آواز سے اعلیٰ و ارفع ہے اور بشر کے کلام سے قطعاً کوئی مشابہت نہیں رکھتا ۔یہ بات جہاں جہاں مناسب تھی بیان کر دی گئی ہے۔
[اضافہ از مترجم:اللہ تعالیٰ کے کلام اور بندوں کے کلام میں کوئی مشابہت نہیں‘ یہ درست ہے‘ لیکن اسے حرف و صوت سے مبرا سمجھنا درست نہیں ہے‘ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا‘خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کلام کو سنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سوال کرنے پر جواب بھی دیا تھا اور یہ اسی وقت ممکن تھا کہ جب انہوں نے حرف اور صوت کے ساتھ اسے سنا ہو۔ اس ضمن میں سورئہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کیا جانامناسب ہے۔]
جب یہ بات طے ہو گئی کہ ہمیں ہماری زبان میں مخاطب کیا گیا‘ اور یہ بات بھی مخفی نہیں کہ زبانوں میں اختلاف ہوسکتا ہے لیکن معانی میں اختلاف نہیں ہوتا تو دونوں سورتوں کی مذکورہ آیات کا حاصل ِکلام یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر اطمینان ہو گیا کہ اب وہ حالت خوف سے باہر آ چکے ہیں اور دائرئہ امن و سلامتی میں داخل ہو چکے ہیں۔ امن میں آنے والوں میں سرفہرست ہیں اللہ کے تمام رسول اور وہ تمام لوگ جو ان سے ہدایت یافتہ ہیں اور ان کے لیے حُسنیٰ (اچھے انجام) کی بشارت پہلے ہی ہو چکی ہے ۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تھا لیکن پھر بدی کے بعد نیکی کا راستہ اختیار کر لیا اور ایسے لوگوں کے لیے بھی حُسنیٰ کی بشارت آچکی‘ تو یہ سب لوگ امن میں رہیں گے۔
اب دوبارہ ان آیات پر نظر ڈال لیں کہ دونوں میں اسی امن کی بات کی گئی ہے :
{ وَلَا تَخَفْقف اِنَّکَ مِنَ الْاٰمِنِیْنَ(۳۱) } (القصص)
{لَا تَخَفْقف اِنِّیْ لَا یَخَافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُوْنَ(۱۰) اِلَّا مَنْ ظَلَمَ } (النَّمل)
یہاں یہ واضح رہے کہ اس آیت میں استثناء ( اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ) متصل نہیں بلکہ منقطع ہے‘ یعنی یہ سمجھنا کہ’’ رسولوں میں سے بھی کچھ ایسے رسول ہو سکتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہو اور پھر نیکی کی ہواور اس بنا پر انہیں معاف کر دیا گیاہو‘‘۔یہ بات کچھ گمراہ کن لوگوں نے کہی ہے جن میں فرقہ ’’الشَّوذِیہ‘‘ (ابوعبداللہ الشوذی الاشبیلی کےپیروکار) شامل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے تمام رسول کفر میں مبتلا ہونے سے بچائے گئے ہیں۔ ظلم میں کفر اور اس سے کم درجے کے گناہ شامل ہیں اور اللہ جسے چاہے ظلم کی مختلف شاخوں سے بچا لیتا ہے ‘ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ رسول تو بہرصورت ظلم سے بچے رہیں گے لیکن باقی لوگوں میں سے بھی کوئی اگر ظلم (چاہے وہ کفر ہو یا اس سے کم کوئی گناہ ہو)کا مرتکب ہو‘ تو اگر وہ تائب ہو جائے اور نیکی کرنا شروع کر دے تو وہ بھی امن کا مستحق ہے‘ اور اگر کسی شخص نے کفر و شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو (جو کہ ظلم عظیم کہلاتا ہے) تو وہ پھر اللہ کی مشیت کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے :
{اِنَّ اللہَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِہٖ وَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآئُ ط} (النساء:۴۸)
’’بے شک اللہ اس کی مغفرت تو نہیں کرتا جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اگر اس سے کم کوئی (گناہ) کیا ہوتو جسے چاہے معاف کردیتا ہے۔‘‘
گویا سورۃ النمل میں جو تفصیلی بیان ہوا ہے ‘ وہی سورۃ القصص میں اجمالی طور پر ان الفاظ میں بیان ہو گیا کہ:
{اِنَّکَ مِنَ الْاٰمِنِیْنَ(۳۱)} ’’تم امن و امان والوں میں سے ہو۔‘‘
یہ بھی ملحوظِ خاطر رہے کہ سورۃ النمل کی آیت میں صرف رسولوں کا ذکر کیا گیا کہ جنہیں ظلم کا ارتکاب نہ کرنے کی بنا پر امن کا استحقاق حاصل ہوا‘ یعنی یہ بات اختصار کے ساتھ بیان کی گئی ‘ اس لیے کہ اگر کوئی بھی شخص ظلم کے ارتکاب کے بعد نیکی کی راہ اختیار کر لے تو وہ بھی امن کا استحقاق حاصل کر سکتا ہے‘ تو جس نے سرے سے ظلم نہیں کیا تو اسے تو بدرجہ ٔ اولیٰ امن حاصل ہو گا۔
موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ہم کلامی کے بعد یہ ساری بات پوری طرح ذہن نشین کر لی ہو گی‘ اور انہی معانی و مطالب کو قرآن میں نقل کر دیا گیا ہے‘ یعنی چاہے الفاظ کا اختلاف ہو لیکن معانی و مطالب تو وہی ہیں‘ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔
آپ پھر بھی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جو معانی و مطالب سورۃ النمل میں بیان ہوئے ہیں وہ اسی سورت میں کیوں بیان ہوئے ہیں اور جو سورۃ القصص میں وارد ہوئے ہیں وہ اسی سورت کے ساتھ خاص کیوں ہیں؟
اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ النمل میں ملکہ سبا کا قصہ بیان ہوا کہ وہ اور اس کی قوم کیسے سورج کی عبادت کیا کرتےتھے۔ ارشاد ہوا:
{وَجَدْتُّہَا وَقَوْمَہَا یَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللہِ} (آیت۲۴)
’’(ہدہد نے کہا:) میں نے اسے اور اس کی قوم کو اس حالت میں پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔‘‘
اور قصے کے آخر میں بتایا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی اور یہ الفاظ کہے:
{ قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمٰنَ لِلہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ(۴۴) }
’’(ملکہ سبا نے) کہا: اے میرے ربّ! مَیں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا اور مَیں سلیمانؑ کے ساتھ تمام جہانوں کے ربّ کی فرمانبرداری اختیار کرتی ہوں۔‘‘
یہاں بالکل مناسب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دِل دَہی کے لیے یہ الفاظ لائے جاتے:
{اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْٓئٍ }
’’سوائے اُس کے جس نے ظلم کیا اور پھر بدی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا‘‘
اب آیئے سورۃ القصص کی طرف جہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بشارت دی گئی تھی:{اِنَّکَ مِنَ الْاٰمِنِیْنَ(۳۱)} ’’تم امن میں آجانے والوں میں سے ہو۔‘‘سورۃ القصص کا سیاق ملاحظہ ہو‘ فرمایا:
{تِلْکَ الدَّارُ الْاٰخِرَۃُ نَجْعَلُہَا لِلَّذِیْنَ لَا یُرِیْدُوْنَ عُلُوًّا فِی الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًاط} (آیت۸۳)
’’یہ وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد۔‘‘
یہ آیت عام ہے‘ ہر اُس شخص کے لیے بشارت ہے جو مذکورہ صفات اپناتا ہے ۔ ایسے لوگوں کے لیے سورۃ الانبیاء کی آیت کے مطابق پہلے ہی اچھے انجام کی خوش خبری دے دی گئی ہے:
{اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَہُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓی لا اُولٰٓئِکَ عَنْہَا مُبْعَدُوْنَ(۱۰۱)} (الانبیاء)
’’بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی لکھی جا چکی ہے وہ (عذابِ جہنم) سے دور کردیے جائیں گے۔‘‘
اس کے بعد فرمایا: {لَا یَحْزُنُہُمُ الْفَزَعُ الْاَکْبَرُ} (آیت ۱۰۳) ’’ایک بڑی حالت ِ خوف بھی انہیں غمگین نہ کرسکے گی۔‘‘یعنی وہ حالت امن میں آجائیں گے۔تو بالکل مناسب تھا کہ مذکورہ آیت {تِلْکَ الدَّارُ الْاٰخِرَۃُ ... الخ} یہاں خاص طور پر لائی جاتی۔
ایک دوسرا جواب یوں ہو سکتا ہے کہ جب پہلے یہ بیان ہوچکا تھا کہ امن رسولوں کے لیے ہو گا اور ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے گو اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا لیکن بعد میں نیکی کا راستہ اختیار کر لیا تھا‘ تو اس آیت سے ہی معلوم ہو گیا کہ جن لوگوں نے سرے سے ظلم نہیں کیا تھا تو وہ بھی رسولوں کی طرح حالت ِامن میں آجائیں گے۔
اور جب سورۃ القصص سے پہلے یہ تفصیل بیان ہو چکی تھی کہ کون امن کا مستحق ہو گا اور کون نہیں تو یہاں دوبارہ یہ تفصیل بتانے کی چنداں ضرورت نہ تھی ۔ اسی لیے مختصراً یہ الفاظ کہہ دیے گئے : {اِنَّکَ مِنَ الْاٰمِنِیْنَ(۳۱)} ’’بےشک تم امن والوں میں سے ہو۔‘‘اور اسی لحاظ سے بھی مناسبت ِآیات کا بیان ہو گیا۔ واللہ اعلم!
(۲۷۷) آیات ۵۹ تا ۶۴
{قُلِ الْحَمْدُ لِلہِ وَسَلٰمٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی ط ئٰٓ اللہُ خَیْرٌ اَمَّا یُشْرِکُوْنَ(۵۹)}
’’کہہ دیجیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سلام ہو اس کے برگزیدہ بندوں پر۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟‘‘
اب سوال یہ ہے کہ اگلی تمام آیات میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت کے دلائل بیان ہو رہے ہیں لیکن ہر آیت کا آخری مقطع مختلف ہے ‘ جیسے :
{بَلْ ہُمْ قَوْمٌ یَّعْدِلُوْنَ(۶۰) } ’’بلکہ یہ لوگ حق سے انحراف کرتے ہیں۔‘‘
{بَلْ اَکْثَرُہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ(۶۱)} ’’بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔‘‘
{قَلِیْلًا مَّا تَذَکَّرُوْنَ(۶۲) } ’’تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔‘‘
{تَعٰلَی اللہُ عَمَّا یُشْرِکُوْنَ(۶۳)} ’’جنہیں یہ شریک کرتے ہیں اللہ ان سے بالاتر ہے!‘‘
{قُلْ ہَاتُوْا بُرْہَانَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ(۶۴) } ’’کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لائو۔‘‘
جواباً عرض ہے کہ ان میں سے پہلی آیت کو لے لیجیے۔اس میں وہ چند باتیں بیان ہوئی ہیں جن کی گواہی عقل دیتی ہے اور زبانیں اس کا برملا اعتراف کرتی ہیں۔ اگر وہ زمین و آسمان کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس حکمت اور پائیداری کے ساتھ انہیں پیدا کیا ہے اور ان میں کیا کیا عجائب اور نشانیاں رکھی ہیں‘ لیکن ان میں تغیرات بھی آ سکتے ہیں۔ ان کی حیرت انگیز بناوٹ اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً ان کا کوئی بنانے والا ہے‘ ان کی صنعت گری کرنے والا ہے‘ اور وہ خود بخود وجود میں نہیں آئے۔ اور نہ ہی انہیں کسی ایسی ہستی نے بنایا ہے جو انہی کی طرح حاجت مند اور قابل تغیر رہی ہو۔ یہی بات تمام موجود چیزوں کے بارے میں کہی جا سکتی ہے‘ اور پھر عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان کا بنانے والا انہی کی جنس میں سے نہیں ہے اور نہ ہی ان کے مشابہ ہے‘ کیونکہ اگر وہ ان کے مشابہ ہو تو پھر وہ ایک اور مُوجد کا محتاج ہو گا۔ اس بات کی وضاحت کے لیےآخر میں ارشاد فرمایا:{بَلْ ہُمْ قَوْمٌ یَّعْدِلُوْنَ(۶۰) } یعنی معاملہ مخفی نہیں ہے‘ سمجھ میں آتا ہے‘ لیکن یہ لوگ ہٹ دھرمی کی بنا پر اس کے ماننے سے انحراف کرتے ہیں۔
سورۃ البقرۃ کی ابتدا ہی میں اس مضمون کو اس انداز میں بیان کیا گیا تھا:
{یٰٓـاَیـُّھَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّــکُمُ الَّذِیْ خَلَـقَـکُمْ وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ } (آیت۲۱)
’’اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ ‘‘
اور اس کے بعدزمین کا ذکر کیا کہ کیسے اُسے بچھونا بنایا‘ آسمان کا ذکر کیا کہ کیسے اُسے تعمیر کیا‘ آسمان سے پانی برسانے کا ذکر کیا کہ جس سے پھل پودے اُگتے ہیں اور لوگوں کو رزق بہم پہنچاتے ہیں اور آخر میں کہا:
{فَلَا تَجْعَلُوْا لِلہِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ(۲۲)}
’’تو پھر اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہرائو اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو۔‘‘
یہ بالکل وہی انداز ہے جو سورۃ النمل میں پیش کیا گیا ہے‘ وہاں بھی زمین و آسمان کی خلقت کا ذکر ہے‘ آسمان سے پانی برسانے کا تذکرہ ہے‘ خوش نما باغات اُگانے کی بات کی گئی ہے اور پھر آخر میں کہا گیا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الٰہ ہو سکتا ہے ؟نہیں! بلکہ یہ لوگ انحراف کرتے ہیں۔
دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ یہ عرب اللہ کی ربوبیت کے قائل تھے۔ سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرمایا:
{وَلَئِنْ سَاَلْتَہُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَلَیَقُوْلُنَّ اللہُ ج } (آیت۶۱)
’’اور اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا ؟تو وہ کہیں گے : اللہ نے!‘‘
اور اس کے بعد (آیت۶۳میں)فرمایا:
{ وَلَئِنْ سَاَلْتَہُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآئِ مَآئً فَاَحْیَا بِہِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِہَا لَیَقُوْلُنَّ اللہُ ط }
’’اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا اور پھر زمین کو جب کہ وہ مر چکی تھی‘ کس نے زندہ کیا؟ تو وہ کہیں گے : اللہ نے! ‘‘
ان کا یہ اعتراف کرنا اور اس کے بعد اللہ کے لیے اس کا مثیل اور شریک ٹھہرانا واضح طور پر ان کے انحراف (یعنی عدول عن الحق) کی علامت ہے جب کہ ان پر حُجّت قائم ہو چکی تھی۔
اگلی آیت میں ارشاد فرمایا:
{اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا .... } (آیت۶۱)
’’بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا ہے .... ‘‘
اور اس کے بعد جو باتیں بیان ہوئی ہیں کہ پھر اس میں نہریں بنائیں‘ اس میں پہاڑ کھڑے کر دیے اور میٹھے اور کڑوے پانی کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دی تاکہ زمین تمہاری رہائش کے لیے سازگار ہو سکے۔ یہ سب باتیں سمجھنے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے اس قدر واضح نہیں ہیں جتنا کہ وہ باتیں جواس سے قبل کہی گئی تھیں۔ یعنی زمین و آسمان کو پیدا کرنا‘ آسمان سے پانی برسانا اور پھر اس سے کھیتیاں پیدا کرنا ۔ چونکہ ان نشانیوں میں کچھ رازدارانہ نوعیت کی بھی ہیں‘ اس لیے آخر میں ارشاد فرمایا:{بَلْ اَکْثَرُہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ(۶۱)}’’لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔‘‘
اس کے بعد تدریجی طور پر اس سے بھی بڑھ کر ایک مخفی اَمر کی طرف توجہ دلائی:
{اَمَّنْ یُّجِیْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَیَکْشِفُ السُّوْٓئَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَآئَ الْاَرْضِ ط } (آیت۶۲)
’’کون ہے جو ایک بے کس کی پکار کو سنتا ہو اور پھر اس کی مشکل کو آسان کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟‘‘
یہاں جس بات کا تذکرہ ہے اس کی حقیقت کو وہی جان سکتا ہے جو خوب غور و خوض کر سکتا ہو‘ تو یہاں آخر میں یہ کہنا مناسب تھا:{قَلِیْلًا مَّا تَذَکَّرُوْنَ(۶۲) }’’تم بہت کم نصیحت پکڑ سکتے ہو۔‘‘
اس کے بعد ایک ایسی بات ذکر کی گئی جو تدبر کریں تو بالکل واضح ہے لیکن اُسے کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا:
{اَمَّنْ یَّہْدِیْکُمْ فِیْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} (آیت۶۳)
’’وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتاہے؟‘‘
اور اسی طرح اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلا دیتا ہے‘ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو قبول کرتے ہی بنتی ہے۔ اس لیے یہاں آخر میں ارشاد فرمایا:{تَعٰلَی اللہُ عَمَّا یُشْرِکُوْنَ(۶۳) }’’یہ جو کچھ شرک کرتے ہیں‘ اللہ ان سے بالاتر ہے۔‘‘
اس کے بعد فرمایا:{اَمَّنْ یَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُہٗ} ( آیت۶۴)’’بھلا وہ کون ہے جو اول دفعہ پیدائش کرتا ہے اور پھر وہی اسے لوٹا ئے گا۔‘‘ اوریہ کہ وہ کون ہے جوتمہارے لیے آسمان اور زمین سے رزق کے خزانے کھولتا ہے؟ یہ وہ سب نشانیاں ہیں کہ ان میں جتنا غور کیا جائے گا‘ اللہ کے علم اور قدرت سے متصف ہونے کاشعور حاصل ہوگا‘ کیونکہ ان دونوں صفات کی روشنی میں اوّلین پیدائش اور پھر بعد از موت دوبارہ اٹھائے جانے کا ادراک ہوتا ہے۔یہی نہیں‘ اللہ کی دوسری صفاتِ عالیہ کا بھی شعور حاصل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ جب حُجّت واضح ہوگئی تو اب سوائے حق کے اعتراف کے اور اللہ پر ایمان لانے کے بغیر کوئی چارا باقی نہیں رہتا کہ وہی خالق ارض و سماء ہے‘ دونوں دنیائوں کا مالک ہے‘ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے‘ تو اگر کوئی نہ مانے اور ضد پر اتر آئے تو اس سے یہی کہا جائے گا جو آیت کے آخر میں بیان ہوا:{قُلْ ہَاتُوْا بُرْہَانَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ(۶۴)}’’تو پھر لائو اپنی دلیل اگر تم سچے ہو!‘‘یعنی اگر پھر بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک ہے تو پھر اس کی دلیل بھی پیش کرو!
یوں واضح ہوگیا کہ ہر آیت کا مقطع اپنے اپنے مضمون سے پوری مناسبت رکھتا ہے‘ واللہ اعلم!