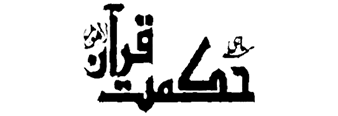(ایمانیات) مباحث ِعقیدہ(۲۴) - مؤمن محمود
9 /مباحث ِعقیدہ(۲۴)مؤمن محمود
متشابہات میں مذہب ِسلف
امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب’’ الجام العوام عن علم الکلام‘‘ یقیناً اس قابل ہے کہ اس کا سبقاً سبقاً مطالعہ کیا جائے۔ ۴۰ ،۵۰صفحوں پر مشتمل مختصر کتاب ہے لیکن اپنے معنی اور گہرائی کے اعتبار سے اتنی جامع ہے کہ اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اس وقت ہمارا موضوع چونکہ یہ کتاب نہیں ہے تو ہم اس کتاب کا اس طریقے پر تو مطالعہ نہیں کریں گے لیکن عقیدے کے حوالے سے یہ موضوع اور عنوان ہم شروع کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں مستحیل باتیں یا مستحیل صفات کیا ہیں۔ وہ باتیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نہ ہوناماننا ضروری ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں کہ جن میں تشابہ ہے ‘جو متشابہات ہیں ‘بلکہ تمام صفات ہی ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت ہم پر نہیں کھلی ۔ہم ان صفات کو کچھ مظاہر اور آثار کے اعتبار سے جانتے ہیں‘ اپنی حقیقت کے اعتبار سے نہیں جانتے۔ ان صفات کے حوالے سے سلف کا طرزِ عمل کیا تھا یا مذہب سلف کیا تھا اور وہی مذہب سلف ہے کہ جس کو امام صاحب علیہ الرحمہ عوام الناس کے لیےمفید سمجھتے ہیں کہ سب کو اسی مسلک پر کھڑے ہو ناچاہیے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی بھی صفت کی تاویل نہیں ہوسکتی‘ لیکن تاویل کرنے کی بڑی کڑی شرائط ہیں ۔تاویل کی بھی شرائط ہیں اورجو تاویل کرنے والا(مؤول) ہے‘اس میں بھی سخت اور کڑی شرائط پائی جائیں گی تو وہ شخص اہل ہوگا اس بات کا کہ وہ تاویل کر سکے۔ آج جو باتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان کو اس حوالے سے سنیے گا کہ امام صاحب علیہ الرحمہ ہم عوام کو کچھ باتیں تجویز فرما رہے ہیں۔ جو خطبات ہوتے ہیں یا مقدمہ ہوتا ہے کتاب کا وہ براءۃ الاستھلال پر مبنی ہوتا ہے۔ براءۃ الاستھلال علماء بلاغت کی ایک اصطلاح ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کوئی مصنف جب کوئی مسئلہ شروع کرنا چاہتا ہے‘ کسی موضوع پر کتاب لکھتا ہے یا کوئی تحریر کرتا ہے تو جو مقدمہ درج کرتا ہےاس میں اس کتاب کے یا اس تحریر کے مقاصد اور موضوعات کا ایک طریقے پر ذکر کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں براءۃ الاستھلال۔
مقدمہ: الجام العوام عن علم الکلام
الجام العوا م عن علم الکلام کا مقدمہ یا خطبۃ الرسالہ بہت مختصر سا ہے۔ وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ امام صاحب علیہ الرحمہ اس کتاب کا شانِ نزول اور وجہ ٔتحریر کیا بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:
الحمد للّٰہ الذی تجلی لکافۃ عبادہ بصفاتہ و اسمائہ
’’ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنے تمام بندوں کے سامنے متجلی ہوا( ظاہر ہوا) اپنی صفات اور اپنے اسماء کے ذریعے۔‘‘ ظاہر ہو گیا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ سب نے اسے پہچان لیا جیسا کہ وہ ہے؟کہتے ہیں ایسا نہیں ہے !
وتیہ عقول الطالبین فی بیداء کبریائہ
’’(اللہ کے) طالبین کی عقلیں اللہ کی کبریائی کے میدان (اور صحرا میں‘ بیابان) میں گم ہو گئیں ‘‘کھو گئیں‘ ششدر رہ گئیں‘ متحیر ہو گئیں۔گویا اس میں ایک بات یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک معرفت تو سب کو حاصل ہے جبکہ ایک اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوجھل ہیں ‘پردے میں ہیں۔
وقص اجنحۃ الافکار دون حمیٰ عزتہ وتعالیٰ بجلالہٖ عن ان تدرک الافہام کنہ حقیقتہ
’’اللہ تعالیٰ نے انسانی افکار کے پر کاٹ دیے ہیں کہ وہ اللہ کی عزت اور جلال کی حدود میں داخل ہو سکے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کنہہ اور حقیقت کو جان سکے۔‘‘
گویا انسانی افکار کی وہاں تک پرواز ہی نہیں ہے اس لیے کہ انسانی افکار کے پر کاٹ دیے گئے۔ پھر فرماتے ہیں:
و استوفیٰ قلوب اولیائہ و خاصتہ، و استغرق ارواحھم حتیٰ احترقوا بنار محبتہ، وبھتوا فی اشراق انوار عظمتہ و خرست السنتھم عن الثناء علٰی جمال حضرتہ الا بما اسمعھم من اسمائہ و صفاتہ و انبأھم علی لسان رسولہ محمد ﷺ خیر خلیقتہ صلی اللّٰہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ
’’اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے دلوں کو اس طرح اپنی طرف کھینچ لیا اور ان کی ارواح کو اس طرح اپنی محبت کے سمندر میں غرق کر دیا کہ وہ اللہ کی محبت کی آگ میں جل گئے۔ اور اللہ کی عظمت کے انوار کے سامنے مبہوت ہو کر رہ گئے اور ان کی زبانیں بند ہو گئیں اس بات سے کہ وہ اللہ کے حضورکے جمال کو بیان کرسکیں۔ انسانی زبانوں میں یہ صلاحیت نہیں رہی سوائےاس کے کہ وہ بات بیان کریں کہ جو اللہ نے انہیں سنائی ہے اپنے اسماء اور صفات میں سے اپنے رسول محمدﷺ کی زبانی جو اللہ کے بہترین خلیقہ ہیں یعنی سب سے افضل مخلوق ہیں۔ ان پر بھی صلاۃ اور سلام ہو اور ان کے اصحاب ‘ ان کی آل اور عترت پر بھی۔‘‘
یہ خطبۃ الرسالہ ہے۔ اس میں گویا وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے عوام‘ تم یہ جان لو کہ وحی میں اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں جتنا آگیا ‘اتنا تم جان سکتے ہو ۔اس سے زیادہ معرفت کی خواہش تمہارے لیے ممکن نہیں ہے بلکہ اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کے لیے بھی ممکن نہیں ہے‘ کیونکہ وہاں پہنچ کر ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا نور انہیں مبہوت کر دیتا ہے۔
اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے۔کسی صاحب نے انہیں خط لکھا کہ ہمیں ذرا بتائیے ان اخبار اور نصوص کے بارے میں کہ جو وحی میں آئی ہیں جن سے کچھ جاہل قسم کے لوگ جو حشویہ اور گمراہ ہیں‘ جسمانیت برآمد کرلیتے ہیں۔ فرمایا: وہ لوگ کہ جو گمراہ ہیں اور حشویہ ہیں‘ مشبہ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ جس سے جسمانیت لازم آتی ہے‘ صورت لازم آتی ہے اور بتاتے ہیں کہ اللہ کا ید اور قدم اور نزول اور انتقال ہے اور جلوس علی العرش استقرار کے مانند ہے‘ اور جس طرح انسان کے یہ اعضاء ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی یہ اعضاء ہیں۔ یہ سب لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں یہ باتیں بیان کرتے ہیں ان کا زعم یہ ہےکہ وہ سلفیہ ہیں۔
و زعموا ان معتقدھم فیہ معتقد السلف
’’ان کا زعم یہ ہے کہ وہ مذہب سلف کے پیروکار ہیں۔ ‘‘
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جسمانیت اور تشبیہ کے قائل ہو گئےہیں۔
مذہب سلف کیاہے؟
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں جسمانیت کا عقیدہ رکھنا مذہب ِسلف نہیں ہے تو پھر مذہب سلف کیا ہے؟ فرماتے ہیں:
و أردتُ ان أشرح لک اعتقاد السلف
’’میرا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں بتا دوں کہ سلف کا اعتقاد کیا ہے!‘‘گویا امام صاحب علیہ الرحمہ کی یہ کتاب الجام العوام عن علم الکلام کہ جس کا مطلب ہے عوام کو علم الکلام سے دور رکھنا‘ تو اس کتاب کابنیادی مقصد مذہب ِسلف کا بیان ہے۔چنانچہ آگے جتنی بھی باتیں امام صاحب فرما رہے ہیں وہ ان کے مذہب سلف کی تفہیم ہے۔
پہلا باب اصل میں اعتقاد سلف کی شرح کا بیان ہے تو کہتے ہیں جان لو کہ سچی بات یہ ہے کہ ایسا حق جس میں اولی الابصار کے ہاں کوئی شک نہیں ہے وہ کیا ہے : ھو مذھب السلف یعنی ان الحق الصریح ھومذھب السلف ’’سچی اور حق بات مذہب سلف ہے‘‘۔سلف کوئی مبہم لفظ نہیں ہے بلکہ میری مراد صحابہ اور تابعین ہیں۔ مذہب سلف کی حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس بھی عوام الناس کے درجے میں یہ اخبار پہنچیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسی باتوں کا اثبات ہے جس سے بظاہر تشبیہ لازم آتی ہے تو اس پر سات چیزیں لازم ہیں۔
اب یہاں سے اصل میں بیان شروع ہو رہا ہے کہ جس تک بھی یہ اخبار پہنچیں گی کہ جس سے کچھ جاہل اور گمراہ قسم کے لوگ جسمانیت کا اعتقاد پیدا کرتے ہیں تو اس بارے میں یا ان صفات کے بارے میں یا ان صفات کی نصوص کے حوالے سے سات باتیں ہر عامی پر لازم ہیں۔ ان سات باتوں کو پہلے انہوں نے اجمالاً بیان کیا اور اس کے بعد تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔
متشابہات : سات لازم باتیں
سب سے پہلی بات ہے تقدیس‘ پھر ہے تصدیق ‘پھر ہے اعترافِ عجز‘پھر ہے سکوت‘ پھر ہے امساک‘ پھر ہے کف اور پھر ہے تسلیم۔ تقدیس کیا ہے ؟مجملاً پہلے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جسمانیت اور اس کے لواحق سے منزہ سمجھا جائے۔ یعنی یہ ہر عامی پر لازم ہے۔
تصدیق کیا ہے ؟ ایمان رکھا جائے کہ جو رسول اللہﷺ نے فرمایاہے وہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولﷺ نے اس سے جو ارادہ کیا ہے وہ بھی حق ہے‘ چاہے وہ ہمیں معلوم نہ ہو سکے۔
تیسری بات یہ کہ ہر آدمی یہ اعتراف کر لے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی حقیقت نہیں جان سکتا‘ یعنی اعترافِ عجز کرے۔ اس کتاب میں جا بجا وہ یہ بات سکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہر انسان اپنے اندر ایک علمی تواضع پیدا کرے۔ وہ جان لے کہ اس کی عقل کی کچھ حدود ہیں‘ اس کی کچھ پرواز ہے جس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ انسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان یہ جان لے کہ اس کی حدود کیا ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے: ((رَحِمَ اللّٰہُ اِمْرَأً عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِہِ)) ’’اللہ تعالیٰ اس بندے پر خصوصی رحمت فرمائے کہ جس نے اپنی قدر پہچان لی‘‘۔ اس نے پہچان لیا کہ وہ کون ہے ‘ اس کی حدود کیا ہیں ‘وہ کہاں تک جا سکتا ہے ‘ کون سے علوم اس کی دسترس سے خارج ہیں۔ اکثر انسان یہ نہیں جانتے بلکہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر وہ کام کر سکتے ہیں اور ہر وہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو دوسرا سمجھ لیتا ہے۔
اس کے بعد ہے سکوت۔اس طرح کے مسائل میں بحث مباحثہ اور سوال نہیں کرنا۔ امام مالک ؒ نے اس شخص کو ڈانٹ دیا جس نے سوال کیا کہ استویٰ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا : والسؤال عنہ بدعۃ یعنی اس طرح کی باتیں پوچھنا بدعت ہے۔ بس اللہ نے جو مراد لی ہے وہ حق ہے۔ اس مراد کو جاننے پر کوئی آخرت کی نجات کا دارومدار تو ہے نہیں۔ آخرت کی نجات کا دارومدار جن چیزوں پر ہے ان پر توجہ دو۔
اس کے بعد فرماتے ہیں امساک: رُک جانا۔ رُک جانے سے مراد ہے کہ ان الفاظ میں تبدیلی نہیں کرنی‘ ان الفاظ کو پھیرنا نہیں ہے ۔پھیرنے اور تبدیلی سے کیا مراد ہے‘ امام صاحب خود واضح فرمائیں گے اس لیے ہم ابھی اس کو چھوڑتے ہیں۔
اس کے بعد فرماتے ہیں کفّ : رُک جانا۔ اس بات سے رُک جائے کہ جس طرح وہ ان صفات کے بارے میں سوال نہیں کر رہا‘ دوسروں سے بحث مباحثہ نہیں کر رہااسی طرح اپنے باطن میں بھی غور و فکر نہ کرے‘کیونکہ اگرکرے گا تو گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے۔
آخری بات : تسلیم۔ سر تسلیم خم کر دے اور یہ نہ سمجھے کہ اگر اس پر یہ معاملات نہیں کھل سکے تو رسول اللہ ﷺپر بھی نہیں کھلے تھے یا صحابہ پر بھی نہیں کھلے تھے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان صفات کے کچھ معنی خاص درجے میں کھل جائیں‘ یہ نہیں کہ تمام معانی کی حقیقت کھل جائے گی۔ ہاں خاص درجے میں کچھ تاویلات کھل گئی ہیں اہل علم پر‘ رسول اللہﷺ پر اور بعد میں آنے والے علماء اور اولیاء پر ‘تو وہ جو بات کر رہے ہیں ان کے سامنے سر تسلیم خم کردے۔
یہ سات وظائف ہیں کہ جو امام صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہر عامی پر یعنی ہم جیسے لوگوں پر واجب ہیں۔
پہلا وظیفہ :تقدیس
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مقدس سمجھا جائے ۔ اس سےاجمالاً مراد یہ ہے کہ جو بھی نصوص اس طرح کی آجائیں‘جیسے ید آگیا‘ استویٰ آگیا ‘صورت آگئی توپہلی بات جو سب کو جاننا ضروری ہے جس کو ہم نے ایک لیکچر میں تاویل اجمالی کہا تھا ‘کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسمانیت اور اس کے توابع اور لواحق سے ماوراء ہے۔ یعنی یہ ابھی غور و فکر کیے بغیر ہی سمجھ لے کہ یَدٌ سے مراد جسم نہیں ہو سکتا۔ جب بھی اللہ کے لیے اس طرح کا کوئی لفظ آگیا تو اس سے مراد جسم نہیں ہوگا۔ جیسے مثال ہے لفظ یَدٌ کی‘ یا اللہ کے لیے اصْبَع انگلی کا لفظ آتا ہے ۔کہتے ہیں کہ کچھ غور و فکر کیے بغیر‘ اس کی حقیقت جانے بغیر پہلی بات یہ سمجھ لے کہ ید سے مراد یہ لحم اور جسم نہیں ہو سکتا‘ کچھ اور مراد ہے۔ پھر وہ یہ بھی جان لے کہ لفظ ید لغت میں بھی مشترک ہوتا ہے یعنی یہ ہاتھ کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو ایک عضو ہے ‘جارحہ ہے جبکہ لفظ یَد عربی زبان میں نعمت کے لیے ‘فضل کے لیے ‘تفضل کے لیے‘ احسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے :
لفلان علیھا یدیہ یا لفلان علیھا ید کہ’’ فلاں پر اس کے ہاتھ ہیں یا ایک ہاتھ ہے‘‘ ۔ یہاں ہاتھ سے مراد احسان ہے ۔یا فلاں نگرانی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ لغت میں یہ مشترک لفظ ہے اور ایک سے زیادہ معنی میں مستعمل ہے تو میں نے طے نہیں کرنا کہ یَد سے کیا مراد ہے کیونکہ میں عامی ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی تاویل کیا ہے لیکن میں تاویل اجمالی کروں گا کہ جب ید کے ایک سے زیادہ معنی ہیں تو کم از کم جسمانیت والا معنی مراد نہیں ہے۔ یہ بات میرے اوپر بالکل واضح ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں : علی العامی و غیر العامی ۔ عامی پر بھی اور غیر عامی پر بھی یہ بات لازم ہے کہ:
ان یتحقق قطعاً ویقیناً ان الرسول ﷺلم یرد بذٰلک اللفظ جسما
’’یقیناً جان لے (یاتحقیقاً جان لے )کہ اللہ کے رسول ﷺکی مراد جسم نہیں تھی‘‘۔ یعنی جب آپ ﷺنے یَد بولا یا وحی میں ید آگیا تو اس سے مراد جسم نہیں ہے۔
وان ذٰلک فی حقّ اللہ محال وھو عنہ مقدس
’’ اللہ کے حق میں یہ محال ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے مقدس ہے ۔ ‘‘
اگلی بات بہت سخت ہے جو امام صاحب میرے لیے اور ہر عامی کے لیے بیان فرما رہے ہیں‘ یعنی میرے اور عامی میں جو عطف ہے وہ تفسیر کا ہے۔ فرمایا:
فان خطر ببالہ ان اللہ جسم مرکب من اعضائہ فھوعابد صنم
’’جس کے دل میں یہ بات آگئی کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے اور اُس کے اعضاء بھی ہیں تو وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ۔وہ صنم (بت) کا عابد ہے(وہ اللہ کا عابد نہیں ہے ۔)۔‘‘
فان کل جسم فھو مخلوق وعبادۃ مخلوق کفر
’’کیونکہ ہر جسم مخلوق ہے اورمخلوق کی عبادت کفر ہے‘‘۔تو جو جسم کی عبادت کر رہا ہے یا اللہ کو جسم سمجھ کے عبادت کر رہا ہے وہ صنم کی عبادت کر رہا ہے۔اور کہتے ہیں:
وعبادۃ صنم کانت کفرا لانّہ مخلوق، فمن عبد جسما فھو کافرباجماع الامۃ السلف منھم والخلف ’’پس جس نے جسم کی عبادت کی تو سلف اور خلف کے اجماع سے ثابت ہو جائے گا کہ وہ شخص کافر ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جسم سمجھتا ہے۔‘‘ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ جوبھی جسم سمجھتا ہے اس کو کافر قرار دے دیا جائے بلکہ وہ تو علماء یا قاضی کا کام ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جسم سمجھنا ایک کفریہ عقیدہ ہے جو ایک مسلمان کے شایانِ شان نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ایک مثال دی۔ یہ تقدیس والی بات چل رہی ہے‘ یعنی اب اس کے سامنے لفظ یَد آیا ہے تو وہ تاویل نہیں کرے گا۔ بس کہہ دے گا کہ لفظ ید سے وہ مراد نہیں ہو سکتی جس سے جسمانیت لازم آ جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک اور مثال دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
((اِنَّ اللّٰہَ خَلَقَ آدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ))
صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے ’’اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا‘‘۔ صورۃ کا لفظ بھی لغت میں مشترک ہے۔صورت کا لفظ ظاہری ہیئت کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور معنوی ہیئت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جب معلوم ہوگیا کہ لغت میں یہ لفظ مشترک ہے ( مشترک لفظی ہے مشترک معنوی نہیں ہے) تو جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں صورت سے مراد صورتِ جسمانی نہیں ہو سکتی۔ بس اتنی بات عامی کے لیے ماننا ضروری ہے اور وہ لغت میں بھی دیکھ سکتا ہے کہ وہاں بھی یہ لفظ مشترک المعنیٰ ہے (ایک سے زیادہ معنی رکھتا ہے)
امام صاحب علیہ الرحمہ تیسری مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی ﷺکا یہ قول سنے :
((یَنْزِلُ اللّٰہُ تعالٰی فِی کُلِّ لَیْلَۃٍ اِلَی السَّماءِ الدُّنْیا))
’’ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمائے دنیاوی پر ہر رات نزول فرماتے ہیں (رات کے آخری پہر میں۔) ‘‘
تو وہ جان لے کہ لفظ نزول مشترک ہے۔ نزول ایک اوپر کی جگہ سے نیچے کی جگہ آنے کو بھی کہتے ہیں اور نزول سے مراد لغت میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں امام شافعیؒ کا قول نقل کیا :
دخلتُ مصر فلم یفھموا کلامی فنزلتُ ثم نزلتُ ثم نزلتُ
’’ میں مصر میں آیا لیکن لوگ میری بات سمجھے نہیں (تو میں نے اپنی بات سمجھانے کے لیے) اپنی بات کا درجہ کچھ کم کیا ‘ پھر مزید کم کیا ‘ پھر مزید کم کیا ۔‘‘
امام صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ زمین میں اترتے چلے گئے۔نزلتُ سے مراد ہے کہ درجہ کلام کے اعتبار سے نزول فرما رہے ہیں۔ جب اتنی بات معلوم ہو گئی کہ لفظ نزول مشترک ہے تو عامی یا میرے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اتنا جان لوں کہ نزول سے مراد نزولِ جسمانی نہیں ہو سکتا ۔ نزولِ جسمانی کے لیے تین جسم چاہئیں: ایک جسم تو وہ مکان ہے جہاں سے انتقال ہوگا۔ دوسرا جسم وہ کہ جو منتقل ہوگا ۔ تیسرا جسم وہ کہ جہاں انسان یا وہ شے منتقل ہو کر پہنچے گی۔ تو یہ تین جسم لازم آ جاتے ہیں اگر نزول سے مراد نزولِ جسمانی لیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے منزہ ہیں۔ عامی کے لیے اس تاویل کی ضرورت نہیں رہے گی ۔بس وہ اتنی بات مان لے کہ نزول سے مراد نزولِ جسمانی نہیں ہے۔
امام صاحبؒ چوتھی مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ فَوْقَ آتا ہے ۔مثلاً:
{وَہُوَ الْقَاہِرُ فَوْقَ عِبَادِہٖ } (الانعام:۶۱)
’’اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے۔ ‘‘
اس کے متعلق بھی جان لو کہ یہ بھی مشترک ہے۔ چنانچہ کبھی فَوْقَ سے مراد فوقِ مکانی ہوتا ہے اور کبھی فَوْقَ سے مراد فوقِ رتبی ہوتا ہے (یعنی رتبے کے اعتبار سے بلند ہونا)۔ہر عامی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے معنی سے مقدس قرار دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے فوقیت ِمکانی نہیں ہوتی۔ تاویل نہ کرے‘ بس اتنی بات مانے کہ فوقیت ِمکانی نہیں ہے۔ تو یہ پہلا وظیفہ ہے ایک عام آدمی کا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مقدس جانے جسمانیت اور اس کے لوازم‘ لواحق ‘ توابع اور سوابق سے۔
دوسرا وظیفہ :تصدیق اور ایمان
امام غزالی ؒ فرماتے ہیں کہ ایمان اور تصدیق سے مراد ہے:
وھو انہ یعلم قطعا ان ھذہ الالفاظ ارید بھا معنا یلیق بجلال اللّٰہ وعظمتہ
’’وہ قطعی طور پر یہ بات جان لے کہ ان الفاظ سے ( جو نصوص میں آئے ہیں) ایک ایسے معنی کا ارادہ کیا گیا ہے جو اللہ کے جلال اور اُس کی عظمت کے لائق ہے۔ ‘‘
اس نے یہ تصدیق کرنی ہے ‘چاہے اس کو وہ معنی معلوم نہیں ہیں ۔آگے فرماتے ہیں (یہ اہم بات ہے جس سے وہ عامی شخص فلاسفہ یا ابن رشد وغیرہ کے مذہب پر کھڑا نہیں ہوگا):
وان رسول اللّٰہ ﷺ صادقٌ فی وصف اللّٰہ تعالٰی بھا
’’اور اللہ کے رسولﷺ نے جو بھی اللہ کا وصف بیان کیا ہے وہ سچ بیان کیا ہے ۔‘‘
فلاسفہ یا ابن رشد وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ وحی میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے‘ عوام الناس کی مصلحت کے لیے ‘یعنی عوام الناس کو چونکہ جسمانیت ہی سمجھ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا بتا دیا کہ میں جسم ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کی مصلحت کی خاطر وحی میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ابن رشد واضح طور پر اس کا اقرار کرتے ہیں۔ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ غلط ہے کہ عوام کے لیے ایسی باتیں کی گئی ہیں بلکہ اس سے صحیح معنی مراد ہے اور اللہ کے رسول ﷺ نے سچ فرمایا ہے۔
یہاں وہ ایک بہت اہم سوال کرتے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ تصدیق کرو اور معنی تو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کی تصدیق کرنی ہے۔ یعنی پہلی بات جو تم نے کی ہے کہ عامی کے لیے تو تاویل بھی نہیں ہے ‘ عامی نے تو تقدیس کرنی ہے اور تاویل اجمالی پر کھڑا ہونا ہے‘تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ عامی جب مراد کو جانتا نہیں ہے تو ایمان اور تصدیق کس کی کرے گا ؟ ایمان اور تصدیق تو فرع ہے مراد کو جاننے کی۔ مراد تو مجہول ہے تو کس کی تصدیق کرنی ہے؟ عجیب بات ہے کہ یہ سوال یہاں امام صاحب نے ذکر کیا‘ اس کا تفصیلی جواب دیا ‘لیکن آج تک کچھ لوگ یہ سوال دہرائے چلے جا رہے ہیں‘ جن کے متعلق امام صاحب نے شروع میں فرمایا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا عقیدہ معتقد سلف ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو امام صاحب نے فرمائی ہیں اس سے صرف تجہیل لازم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نےجو آیات اتاری ہیں ہمیں ان کی مراد ہی نہیں معلوم تو اللہ تعالیٰ نے گویا آیات اس لیے اتاری تھیں کہ ہمیں مراد نہ معلوم ہو۔ اللہ نے تو آیات اس لیے اتاری تھیں کہ ہمیں مراد معلوم ہو اور ہم اس پر غور و فکر کریں‘ تدبر کریں ‘تذکر کریں اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ عامی کے لیے تو اس کی مرادہی معلوم نہیں ہے۔
امام صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم مراد تفصیلی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ عام آدمی کو نہیں معلوم‘ لیکن اجمالی معلومات اور اجمالی مراد تو سب کو معلوم ہے ۔ مثال کے طور پر جب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :
(( یَنْزِلُ رَبُّنَا اِلَی السَّماءِ الدُّنْیا کُلَّ لَیْلَۃٍ))
’’ہمارا رب ہر رات سمائے دنیاوی کی طرف نزول فرماتا ہے۔ ‘‘
تو ایک مراد تو سب کو یہاں معلوم ہو رہی ہے نا کہ اللہ نزول کا جو ذکر فرما رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے اندر شوق پیدا ہو کہ تم اس موقع پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو ‘تہجد کی نماز پڑھو‘ اللہ سے دعائیں کرو‘ اللہ سے استغفار کرو ‘کیونکہ وہ پکار لگا رہا ہے:
(( ھَلْ مِنْ دَاعٍ یُسْتَجَّاَبُ لَہُ؟ ھَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ یُغْفَرُ لَہُ ))(صحیح مسلم)
’’کیا کوئی پکارنے والا ہے کہ اس کی دعا کا جواب دیا جائے؟ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے؟‘‘
گویا نزول کا ذکر کرنے سے اصل مراد ترغیب و تشویق تھی کہ تم کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرو۔ چنانچہ یہ مراد تو سب کو حاصل ہو رہی ہے۔ باقی اصل میں نزول سے کیا مراد ہے‘ اس کو جاننے پر اس معنی کا انحصار نہیں ہے کہ جو معنی اصل میں مراد تھا۔ لہٰذا اگر کسی کو یہ معلوم نہ بھی ہو کہ نزول سے نزولِ جسمانی کے علاوہ کیا مراد ہے تو پھر بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اس مرادِ اصلی پر کہ جو اس حدیث سے مراد تھی۔ وہ مرادِ اصلی کیا تھی؟رات کی نماز کی ترغیب و تشویق ۔ تو یہ مراد اجمالی تو ہمیں حاصل ہو گئی اور یہی اصل مراد تھی۔ لہٰذا اس خاص مراد کو نہ جاننے سے تجہیل لازم نہیں آتی کہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہ ہوا۔ ہمیں ایک معنی اجمالی معلوم ہو جاتا ہے لیکن تفصیلی معنی معلوم نہیں ہو رہا اور وہ اس لیے معلوم نہیں ہو رہا کیوں کہ نزول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت کی کنہ اور حقیقت ہم نہیں جان سکتے۔ لہٰذا یہ اعتراض بالکل باطل ہے کہ اگر تم مراد ہی نہیں جانتے تو ایمان اور تصدیق کس کی کرو گے ؟ ہم ایک اجمالی مراد جان لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں تفصیلی مراد معلوم نہیں ہوئی اس میں بھی اللہ کے رسول ﷺ صادق اور سچے ہیں۔
اسی طریقے پر کہتے ہیں کہ جیسے استویٰ علی العرش کا حقیقی معنی اگر ہمیں معلوم نہ بھی ہو تو اتنی بات تو معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرش کی طرف ایک خاص نسبت فرمائی ہےجس کو استویٰ سے تعبیر کیا۔ اب اس نسبت کی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں نہ بھی معلوم ہو تو اس سے مراد اجمالی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ تو امام صاحب ؒ یہاں یہ جواب دیتے ہیں ۔ دوسرا وظیفہ ہمارے لیے انہوں نے یہ بیان فرمایاکہ تقدیس کے بعد ایمان اور تصدیق ضروری ہے‘ کہ جو بھی مراد ہے اس پر ایمان لایا جائے۔یہاں ایمان لانے سے مراد ہے اجمالیات پر ایمان لانا۔یہاں ایک جملہ ہے ان کا :فاذن الایمان بالجملیات التی لیست مفصلۃ فی الذھن ممکن ’’اجمالی باتوں پر کہ جن کی مراد تفصیلی طور پر ذہن میں معلوم نہ ہو ‘ایمان لانا ممکن ہے۔ ‘‘
تیسرا وظیفہ: الاعتراف بالعجز
یہ ہم عوام الناس کے لیے ہے ۔اعتراف کرنا اس بات کا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کنہ اور حقیقت سے واقف نہیں ہو سکتے۔ اعترافِ عجز اور علمی تواضع کا اظہار کہ میری عقل کی کچھ حدود ہیں‘ اس سے آگے میری عقل نہیں جاسکتی۔ یہ ہر عامی پر نہیں بلکہ ہر خاص پر بھی ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ عامی تاویل اور حقیقی معنی نہیں جان سکتا تو غیر عامی ہی جان سکتا ہے‘بلکہ جو رَاسِخون فی العلم ہیں اور اللہ کے عارفوں اور اولیاء میں سے ہیں‘ اگرچہ وہ معرفت میں حدود عوام سے بہت آگے پہنچے ہیں لیکن پھر بھی کوئی نسبت نہیں ہے ان اشیاء کی جو ان سے مخفی ہیں‘ ان چیزوں سے جو ان پر ظاہر ہو چکی ہیں۔ لہٰذا اعترافِ عجز عامی نے تقلیداً کرنا ہے اور عارف نے تحققاً کرنا ہے۔ تحققاً کا مطلب ہے کہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور ذات کی حقیقت اور کنہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں اللہ کے نبی ﷺ کی حدیث نقل کی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ((لَا أُحْصِی ثَنَاءً عَلَیْکَ)) اس میں اللہ کے نبی ﷺ اس بات کا اعتراف فرما رہے ہیں کہ اللہ کی جو حمد بیان کی جانی چاہیے وہ میں نہیں بیان کر سکتا ‘اس کا احصا نہیں کر سکتا۔ ((أَنْتَ کَمَا اَثْنَیْتَ عَلٰی نَفْسِکَ))(رواہ الترمذی) اور پھر سید الصدیقین ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی نقل کر دیاکہ العجز عن درک الادراک ادراک! ’’ادراک کے ادراک سے عاجزآجانا ہی ادراک ہے ۔‘‘
چوتھا وظیفہ: السکوت عن السوال
یعنی سوال کرنے میں بھی خاموشی کا مظاہرہ کرنا۔ عوام الناس اگر ان مسائل میں سوال کریں گے تو اپنے آپ کو ان امور میں ڈالیں گے جن کے وہ اہل نہیں ہیں‘ لہٰذا اندیشہ کفر ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم ہے۔ یعنی یہ جو مسائل ہیں‘ کچھ دقائق ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور ذات کی دقیق قسم کی بحثیں ہیں‘یعنی جتنی بحثیں ہم کر رہے ہیں وہ تو عوام الناس کے لیے ضروری ہیں لیکن اس سے بڑھ کر جو مباحث ہیں ان میں سوال کرنا بھی عوام کے لیے جائز نہیں کہ وہ جا کر پوچھیں کہ مجھے’’ اسْتَویٰ عَلَی الْعَرْشِ‘‘ کی حقیقت سمجھا دو ‘مجھے فلاں شے کی حقیقت سمجھا دو‘ مجھے وحدت الوجود کی حقیقت سمجھا دو۔ پھر کہتے ہیں کہ ان امور کو عوام الناس کے سامنے منبر پر بیٹھ کر بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنے جھوٹے علم کے اظہار کے لیے اس طرح کے دقائق اوردقیق مسائل پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ۔ اگر سوال کرنے والا اپنے جیسے جاہل سے پوچھے گا تو وہ جاہل اس کے جہل ہی میں اضافہ کرے گا۔ اگر وہ کسی عارف سے بھی پوچھ لے گا تو عارف بھی اسے سمجھانے پر قادر نہیں ہوگا۔ لہٰذا نہ اس سوال کا فائدہ جاہل سے ہے اور نہ عارف سے ہے۔
پھرانہوں نے مثالیں دی ہیں کہ ایک بڑھئی ہوتا ہے اور ایک سنار ہوتا ہے۔ بڑھئی سنار کی صنعت اور اس کے پیشہ کی باریکیاں نہیں جان سکتا۔ اسی طرح سنار بڑھئی کی صنعت اور اس کے پیشہ کی باریکیاں نہیں جان سکتا۔ لہٰذاجو۲۴ گھنٹے دنیا میں گھرا ہوا ہے‘ دنیا ہی کی یاد اور اس کا ذکر اس کے دل پر مستولی اور غالب ہے‘ وہ اچانک چاہے کہ مجھے دین کے گہرے مسائل بھی سمجھ میں آ جائیں‘ یہ ممکن ہی نہیں‘ کیونکہ دنیا اور آخرت اور حب ِدنیا اور حب اللہ میں بعدالمشرقین کا فاصلہ ہے ۔لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے۔ فرماتے ہیں: فالمشغول الدنیا ’’جو دنیا میں مشغول ہیں‘‘ وبالعلوم التی لیست من قبیل معرفۃ اللّٰہ تعالیٰ ’’اور ایسے علوم میں مگن ہیںکہ جو اللہ کی معرفت کے علوم نہیں ہیں‘‘ عاجزون عن معرفۃ الامور الالہٰیۃ ’’یہ سب لوگ عاجز ہیں امورِ الٰہیہ کی معرفت سے۔‘‘ پھر فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے تو اسے آپ بڑوں کی غذا کھلا دیں تو اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا‘ ہو سکتا ہے وہ مر ہی جائے ‘تو اسی طریقے پر عوام کو عرفاء کی غذا کھلا دی جائے تو وہ بھی اس کو ہضم نہیں کر سکیں گے اور اندیشہ کفر لازم آجائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ عوام کے سامنے یہ باتیں نہ کی جائیں اور ان کو سوال سے روکا جائےبلکہ ان کو ڈرایا جائے اور مارا جائے ۔یہ خیراس وقت ہمارے لیے نہیں ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دُرّے سے مارا کرتے تھے۔ فرمایا: کذٰلک العوام اذا طلبوا بالسوال ھذہ المعنٰی یجب زجرھم ومنعھم وضربھم بالدرۃ ’’اگر عوام الناس آ کر اس طرح کے سوال کرنا شروع کر دیں تو انہیں روکا جائے‘ انہیں ڈانٹا جائے ‘انہیں دُرّے کے ذریعے مارا جائے ‘‘۔ کـما کان یفعلہ عمر’’جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے‘‘ ایک سے زیادہ واقعات ہیں کہ آیات متشابہات کے بارے میں کوئی آ کر پوچھتا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دُرّے سے اسے مارتے تھے۔
اللہ کے نبیﷺ نے جب ان لوگوں کو دیکھا کہ جو بیٹھ کر مسائل ِقدر میں گفتگو کر رہے تھے تو آپﷺ کا رنگ بدل گیا اور انہیں منع فرمایا کہ اسی طریقے پر تم سے پہلے لوگ بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ پھر کہتے ہیں: میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ واعظ پر اور خطبہ دینے والوں پر بھی یہ حرام ہے کہ وہ منابر پر بیٹھ کر دروس میں اس طرح کی باتیں کریں ۔ پھر کرنا کیا ہے؟ امام صاحب ہر جگہ یہ فرما رہے ہیں کہ عوام الناس کے سامنے یہ کرنا ضروری ہے کہ تشبیہ اور تجسیم کی نفی میں مبالغہ کیا جائے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے عوام الناس میں کہ ٹھیک ہے یہ جو تجسیم کی نفی ہے‘ یہ بھی ایسے مسائل ہیں کہ جو عوام نہیں سمجھ سکیں گے ‘تو ہم اس کی نفی نہیں کرتے ۔بلکہ نفی ضروری ہے کیونکہ عوام الناس میں تشبیہ اور تجسیم کے جراثیم زیادہ تیزی سے سرایت کر جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں: بل الواجب علیہم الاقتصار علی ما ذکرناہ وذکرہ السلف’’ان پرواجب ہے کہ اسی پر رک جانا جس پر سلف رکے تھے‘‘ وھو مبالغۃ فی التقدیس و نفی التشبیہ وانہ تعالیٰ منزہ عن الجسمانیۃ و عوارضھا ولہ المبالغۃ فی ھذا بما اراد حتیٰ یقول ’’اور وہ یہ ہے کہ مبالغہ کریں تقدیس میں‘ نفی تشبیہ میں اور اس میں کہ اللہ تعالیٰ جسمانیت سے اور اس کے عوارض سے ماورا ہے۔ اور اتنا مبالغہ کرے کہ یہ بھی کہہ دے:‘‘ کل ما خطر ببالکم و ھجس فی ضمیرکم و تصور فی خواطرکم فانہ تعالیٰ خالقھا وھو منزہ عنھا وعن فشابھتھا وان لیس المراد بالاخبار شیئا من ذٰلک ’’جو بھی تمہارے تصور میں آئے‘ جو بھی تمہارے ضمیر میں حوادث آئیں‘ جو بھی صورت تمہارے ذہنوں میں بنے‘ اللہ سب سے منزہ ہے اور اس کا خالق ہے اور وہ اللہ نہیں ہے۔اور جو بھی اخبار اس بارے میں آئے ہیں ان سے یہ مراد قطعاً نہیں ہے ۔‘‘ اور جیسا کہ ہم قبل ازیں دیکھ چکے ہیں کہ جو جسم کی عبادت کرتا ہے وہ عابد صنم ہے ‘وہ خدا کی عبادت نہیں کر رہا۔ تو یہ چوتھا وظیفہ ہو گیا یعنی سکوت عن السوال۔
پانچواں وظیفہ: الامساک
الوظیفۃ الخامسہ: الامساک عن التصرف فی الالفاظ الواردۃ یجب علی عموم الخلق الجمود علی الفاظ ھذہ الاخبار والامساک عن التصرف فیھا من ستۃ اوجہ جو الفاظ آگئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بس انہی الفاظ تک رہنا ہے‘ ان الفاظ میں مزید تصرف نہیں کرنا ۔تصرف سے کیا مراد ہے؟ تصرف کی چھ وجوہ ہیں: التفسیر والتاویل والتصریف والتفریع والجمع و التفریق ۔ یہ چھ باتیں ہیں کہ جس سے ہم(عوام) نے خبردار رہنا ہے کہ وہ ان الفاظ میں یہ کام کریں۔ اب امام صاحب ان وجوہ کی الگ الگ وضاحت کریں گے :
تصرف اوّل : تفسیر: فرمایا کہ تفسیر سے میری مراد یہ ہے کہ عربی کے لفظ کی جگہ کسی اور زبان کے لفظ سے اس کی وضاحت کر دی جائے۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن امام صاحب اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر‘ لفظ آیا ہے استوی علی العرش تو میں اس کا فارسی میں ترجمہ کروں۔ چونکہ امام صاحب فارسی جانتے تھے تو انہوں نے فارسی کے کچھ الفاظ نقل کر کے کہا استویٰ علی العرش عربی کی جس ترکیب میں آ رہا ہے اور جو اس کے اندر مجاز کے امکانات ہیں‘ غیر عربی زبان میں جا کر وہ سارے امکانات باقی نہیں رہتے۔ لہٰذا مفہوم کے خلط ملط ہوجانے کے امکانات بہت قوی ہیں۔ چنانچہ لفظ کو کسی دوسری لغت سے نہ بدلا جائے۔ بعد میں آنے والے علماء نے کہا کہ اگر بدل بھی دیا جائے تو پھر نیچے حاشیے میں یا تفسیر میں وضاحت کی جائے کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو متشابہات میں سے ہیں اور ان کا حقیقی معنی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ تفسیر سے امام صاحب مراد لیتے ہیں لفظ کو دوسری لغت میں لے جانا۔کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے میرے ہاں۔ پھر اس میں انہوں نے استوی علی العرش کی مثال دی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ’’ اصبع‘‘ جیسے عربی میں آیا اللہ کے لیے کہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں تو کہتے ہیں کہ فارسی میں اسے انگشت کہتے ہیں۔البتہ انگشت فارسی میں وہ مجازی معنی نہیں رکھتا جو عربی میں لفظ’’ اصبع‘‘ رکھتا ہے ۔ کہتے ہیں کہ فارسی میں ترجمہ کیا تو جاتا ہے لیکن ترجمے کی وجہ سے بہت سے معنی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو عربی زبان کی اس ترکیب میں نہیں ہوتے۔ اس کے بعد انہوں نے لفظ’’ عین ‘‘آنکھ کی بھی یہی مثال دی ہے۔
تصرفِ ثانی:تاویل : اس کے بعد جو تصرف ثانی ہے‘ پانچویں قسم کی دوسری قسم‘ وہ ہے تاویل۔یہ بات ذہن میں رکھیے کہ امام صاحب تاویل کے قائل ہیں اور اس میں انہوں نے ایک تفصیلی بحث کی ہے کہ تاویل کب قطعی ہوتی ہے‘ کب مذموم ہوتی ہے ‘کب دوسرے کو بتائی جا سکتی ہے اور دوسرا کون ہو گا جس کو بتائی جا سکتی ہے ۔وہ عامی ہوگایا طالب علم ہو گا یا عالم ہو گا۔ہر ایک کی الگ الگ شرائط ہیں لیکن چونکہ وہ اس وقت عوام الناس(ہم )سے بات کر رہے ہیں تو ہمارے لیے تاویل جائز نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہی مناسب ہے کہ ہم تاویل نہ کریں‘تاویل وہ لوگ کریں گے جوعارفین ہیں ‘ راسخین فی العلم ہیں۔ وہ لوگ ضرورتاً تاویل کو بیان کریں گے تشبیہ اور تجسیم کی نفی کے لیے۔ ہم نے تاویل اجمالی پر کھڑے ہونا ہے ۔تاویل اجمالی میں جسمیت کی نفی کر دی تو ایک نوع کی تاویل تو ہو گئی۔اس کے بعد تاویل کا مطلب یہ ہے کہ یَدٌ سے مراد جسم تو ہو نہیں سکتا ‘تو پھر مراد کیا ہے؟مراد بیان کرنا یہ تاویل ہے۔ کہتے ہیں یہ کام عوام الناس کے کرنے کا نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر عام آدمی اس طرح کے مسائل میں مشغول ہوتا ہے تو حرام ہے۔ فرماتے ہیں : تاویل العامی علی سبیل الاسقلال بنفسہ وھو حرام، یشبہ خوض البحر المغرق ممن لایحسن السباحۃ یہ حرام ہے کہ ایک عام آدمی بیٹھ کر اس طرح کے مسائل میں تاویل شروع کر دے اور تفسیر شروع کر دے اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ وہ شخص جس کو تیراکی نہیں آتی وہ ایک گہرے سمندر میں چھلانگ مار دے۔ جو چھلانگ مارے گا وہ گم ہو جائے گا اس سمندر میں۔ وہ بحر کفر میں غرق ہو جائے گا۔ یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ وہ معرفت کے سمندر میں گم ہو جائے گا‘ مراد یہ کہ اس کو تیرنا نہیں آتا اس سمندر میں تو ایسے معنی اپنے ذہن میں پیدا کر لے گا جس سے کفر لازم آتا ہے۔ کہتے ہیں :
و بحر معرفۃ اللہ ابعد غورا واکثر معاطب ومھالک من بحر الماء
’’اللہ کی معرفت کا جو سمندر ہے ‘اس کی گہرائی تو تم نہیں جانتے ۔ اس میں بگاڑ اور ہلاکت کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں۔‘‘ اس لیے کہ وہاں اگر انسان نور وحی سے اپنے آپ کو مقید نہ کرے تو پھر کہیں بھی نکل سکتا ہے‘ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے اور گمراہ ہو جائےگا۔
اب یہاں ایک اہم بات ہے کہ عامی کا لفظ بار بار آ رہا ہے تو عامی کون ہے! یہاں وہ عامی کا دائرہ اتنا وسیع کر رہے ہیں کہ عوام الناس کیا ‘علماء اور خواص بھی عوام ہی ہیں‘ یعنی عامی کا دائرہ اس باب میں کہ اللہ کی صفات پر تفصیلی گفتگوکون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں: وفی معنی العوام عوام کے معنی میں کون کون شامل ہے۔ الادیب :ادیب بھی شامل ہے‘ والنحوی: جو علم لغت اور نحو کا ماہر ہے وہ بھی ہے‘ والمحدث: محدث بھی‘ والمفسر: مفسر بھی ہے۔ یہ علمائے دین ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیںکہ اد یب اور نحوی ہو سکتا ہے عالم دین نہ ہوں لیکن مفسر بھی ہے اور محدث بھی ہے اور فقیہہ بھی ہے اور متکلم بھی ہے۔ بل کل عالم بلکہ ہر عالم ہے‘ سوائےکچھ خاص لوگوں کے ۔ یہ امام صاحب کا ذاتی مسلک ہے۔ عموماً متکلمین کا مسلک اور ہے کہ متکلم خاص شرائط کے ساتھ تاویل کے باب میں گفتگو کر سکتا ہے لیکن امام صاحب فرما رہے ہیں میرے لیےیہ سب عوام میں ہیں اور جو خواص ہیں وہ ہیں: سوی۔اب’’ سوی ‘‘کے ذریعے استثنا کر دیا۔ المتجردین: جو اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں‘ جو تجرد حاصل کر چکے ہیں ۔کس کام کے لیے؟ لتعلم السباحۃ فی بحار المعرفۃ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے کہ معرفت کے سمندر میں غوطہ زنی کریں اور تیراکی کریں۔ القاصرین اعمارھم علیہ اورانہوں نے اپنی پوری زندگی اس میں کھپائی ہے۔ صرف کھپانا کچھ نہیں ہے‘ یہ کوئی مینٹل ایکسرسائز نہیں ہے بلکہ الصارفین وجوھھم عن الدنیا والشھوات اور اپنے چہروں اور اپنی ذات کو دنیا اور شہوات سے پھیر دیا ہے۔ المعرضین عن المال والجاہ والخلق وسائر اللذات اعراض کرتے ہیں (یہ لوگ جو اس سمندر میں تیراکی کر سکتے ہیں)‘ مال سے‘ جاہ سے‘ مخلوق سےاور ہر قسم کی لذتوں سے المخلصین للّٰہ تعالیٰ فی العلوم و الاعمال اللہ کے لیے مخلص ہیں علوم اور اعمال میں العاملین بجمیع حدود الشریعۃ وآدابھا تمام حدودو شریعت اور آداب پر عمل کرنے والے ہیں فی القیام بالطاعات و ترک المنکرات قیام اطاعت میں اور ترک منکرات میں المفرغین قلوبھم بالجملۃ عن غیر اللّٰہ تعالیٰ اپنے دلوں کو بالکلیہ فارغ کر چکے ہیں غیر اللہ سے المستحقرین للدنیا بل اللآخرۃ والفردوس الاعلیٰ فی جنب محبۃ اللّٰہ اور حقیر سمجھتے ہیں دنیا کو بلکہ آخرت اور فردوس کو بھی اللہ کی محبت کے مقابلے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جواس سمندر میں غوطہ زنی کے اہل ہیں۔ فھولاء ھم اھل الغوص یہ ہیں وہ جو غوط لگا سکتے ہیں۔ کہاں؟ فی بحر المعرفۃ بحر معرفت میں ۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان دنیا اور اس کی لذات میں منہمک رہے اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ یہ راستہ ہے ‘اس پر چلنا پڑتا ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ یہ سارے معالم فی الطریق ہیں جس کے ذریعے گویا علم مکاشفہ کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مزید معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے ۔ معرفت ہوتے ہوتےحقیقت نہیں کھلتی لیکن بس اجمالی معرفت تفصیل میں بدلتی چلی جاتی ہے اوروہ تفصیلی معرفت اپنے آنے والی منازل معرفت کے مقابلے میں پھر اجمالی ہوتی ہے۔
ایسے لوگ جو اللہ کی معرفت ‘ صفات اور اس طرح کے مسائل میں گفتگو کرنے کے اہل ہیں پھر بھی وہ بڑے خطرے میں ہیں‘ لہٰذا ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے ۔یہ ساری چیزیں بیان کر کے کہتے ہیں: وھم مع ذٰلک کلہ علی خطر عظیم اس سب کے باوجودوہ عظیم خطرے میں ہیں کہ کہیں زبان اور قدم پھسل نہ جائیں ۔کہتے ہیں نا زلۃ العالمِ زلۃ العالَمِ یعنی ایک عالِم کی گمراہی پورے جہاں کی گمراہی ہو سکتی ہے‘ کیونکہ سب اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس بحر معرفت میں کیا ہوتا ہے ؟ یھلک من العشرۃ تسعۃ ان اہل لوگوں میں سے بھی بحر ِ معرفت میں جو اُترتا ہے‘ دس میں سے نو ہلاک ہو جاتے ہیں۔یہ امام صاحب کا بیان ہے اور وہ خود اس میں غوطہ زنی بھی کر چکے ہیں۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم ایک عام آدمی ہو کہ نہ علوم میں کوئی مہارت‘ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ ہے لیکن ان مسائل میں فلسفیانہ اوردقیق قسم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہو۔ وہ بحر معرفت کہ جہاں یہ سب کچھ اہلیت رکھنے والے اورکچھ خاص صفات رکھنے والے کہ جن کا بیان ہو چکا ‘وہ بھی خطر عظیم میں ہیں ‘اور۱۰ میں سے نو ہلاک ہوجاتے ہیں اور شیطان بہت سی جگہوں پر ان عارفین کو بھی اُچک کر لے جاتا ہے‘ عقائد میں خلل پیدا ہو جانے کی وجہ سے اور نورِ وحی سے وہاں مقید نہ ہونے کی وجہ سے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی اگر خطرے میں ہیں تو ایک عام آدمی کہاں کھڑا ہوگا۔ یہ ہے مراد! پھر ہمارے لیے اصل میں کیا ہے ‘یعنی پھر کیا کریں! ان مسائل میں غور و فکر چھوڑ دیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر نہ چھوڑو بلکہ تم اپنے آپ کو عملی کاموں میں لگاؤ۔ تلاوتِ قرآن کرو‘ ذکر کرو‘ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور حرام سے اجتناب کرو۔ اللہ کا تقرب نوافل اور فرائض کے ذریعے حاصل کرو۔ تمہیں کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ لیکن یہ کتابیں پڑھ کر سمجھنا اور باقی چیزوں میں بالکل فارغ ہو جانا ‘یہ انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جو پھر ان میں سے ایک بچتا ہے وہ ہے کہ جو یسعد واحد بالدر المکنون والسر المخزون سمندر کی گہرائی سے وہ در مکنون (چھپا ہوا موتی )نکال کے لاتا ہے اور سر مخزون لے کر آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ فرمایا:
{اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَہُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓی لا اُولٰٓئِکَ عَنْہَا مُبْعَدُوْنَ(۱۰۱)} (الانبیاء)
’’یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ اس(جہنم) سے دُور رکھے جائیں گے۔‘‘
یہ ہم پانچواں وظیفہ پڑھ رہے ہیں کہ الفاظ میں تصرف نہ کیا جائے۔ الفاظ میں تصرف کی چھ اقسام تھیں۔
ان میں سے پہلی قسم تھی: تفسیر‘ ایک لغت سے دوسری لغت میں نہ بدلا جائے ۔
دوسری قسم ہے: تاویل اور تاویل عامی نے تو کرنی ہی نہیں ہے‘ وہ تو سمندر میں چھلانگ مارنے کے مانند ہے جس کو تیراکی نہیں آتی۔ پھر عامی سے کیا مراد ہے ‘اس کی وضاحت ہو رہی تھی۔
تصرفِ ثالث:تصریف: اس کے بعد ہے تصرف ثالث یعنی تصریف ‘پانچویں وظیفے میں لفظ میں تصرف کی تیسری قسم۔ صرف کس کو کہتے ہیں؟ صیغے کواس کے مادے کے اعتبار سے مختلف صورتوں میں پھیر دینا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب صرف کے اعتبار سے ماضی کا صیغہ آگیا تو اب تم نہ اس کو مستقبل میں پھیرو‘ نہ علم اشتقاق کی رو سے اس سے اسم الفاعل نکالو۔ یعنی مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:{ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْش} یہ جملہ فعلیہ ماضیہ ہے تو اب اس سے اگر انسان یہ کہے کہ استوی سے اسم الفاعل مستوی ہوا تو اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جو معنی مستوی علی العرش دے رہا ہے وہ { اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْش} کا تو نہیں ہے۔ {اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْش} تو بتا رہا ہے کہ ایک فعل تھا جو ماضی میں ہوا اور ختم ہو گیا اور مستوی علی العرش بتا رہا ہے کہ وہ فعل ابھی تک جاری ہے ۔چنانچہ اس طرح لفظ میں تصرف سے معنی بدل جاتا ہے۔ صیغہ ماضی ‘فعل ماضی ایک الگ معنی رکھتا ہے‘ اسم الفاعل ایک الگ معنی رکھتا ہے۔ یعنی آپ کہیں فُلانٌ سَرَقَ فلاں نے چوری کی اور آپ کہیں فلانٌ سارِقٌ دونوں میں فرق ہے۔ ایک ہے کہ چوری کی‘ ہو سکتا ہے اس کے بعد اس نے کبھی چوری نہ کی ہو‘ توبہ تائب ہو گیا ہوجبکہ سارق کا مطلب ہے کہ یہ تو اس کا وصف بن گیا ہے‘ اب تو یہ چوریاں ہی کرتا ہے۔ امام صاحب علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ تصریف نہ کرو‘ صرف کے اعتبار سے صیغوں کو پھیرتے نہ چلے جاؤ ۔انہوں نے مثال دی ہے : فلا ینبغی ان یقال مستو ویستوی مستویا مضارع کا صیغہ استعمال کر کے کہہ دو۔ کیونکہ جو دلالت { اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْش} کی ہے وہ مستوی علی العرش کی دلالت نہیں ہے‘ دونوں میں فرق ہے۔ لہٰذا یہ کام نہیں ہوگا ۔ جو لفظ آیا ہے اس کو ہم علم اشتقاق سے دوسرے صیغوں میں تصریف(صرف) نہیں کریں گے۔ یعنی صرفِ صغیر اور کبیر کا موضوع یہ صفات نہیں ہوں گی۔
تصرف رابع: تفریع و قیاس :پانچویں وظیفے میں تصرف رابع کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تفریع اور قیاس بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ایک لفظ آگیا‘ وہ لفظ اسی طرح رہے گا۔اس کی تفسیر بھی نہیں ہوگی‘تاویل بھی نہیں کریں گے‘ صیغوں میں بھی نہیں پھیریں گے‘ تفریع بھی نہیں کریں گے(یعنی اس سے فروعات نکالنا )اور قیاس بھی نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ لفظ’’ ید ‘‘آ گیا : یَدُ اللّٰہِ‘ اگر یدہے تو کوئی اس سےیہ قیاس کرے کہ پھر بازو بھی ہوگا ‘کیونکہ یدبازو پر لگا ہوتا ہے‘ یہ قیاس ہو گیا نا بازو کا۔ ذکر تو نہیں آیالیکن قیاس سے آپ نے ثابت کیا ہے جس کو قیاسِ لزومی کہتے ہیں‘ کیونکہ یدسے باہر کی شے پر آپ نے یدکے ذریعے قیاس کیا ہے۔ پھر آپ کہیں کہ اچھا ید ہے تو خِنسر بھی ہوگی اور بِنصر وغیرہ بھی اور یہ پانچ انگلیاں بھی ہوں گی ۔ کہہ رہے ہیں یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہوسکتا۔ ید آیا ہے تو بس ید ہی رہے گا۔ اس کے بارے میں تقدیس اور وہ سارے وظائف تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم مزید تفریع اور قیاس بھی نہیں کریں گے۔ اسی طرح کہا کہ اگر اذن یا عین کا لفظ آ گیا ہے تو عین کے ذریعے استدلال کیا جائے گاکہ دو آنکھیں ہوں گی۔ پھراس سے استدلال کیا جائے کہ وہاں‘ نعوذ باللہ ‘ گڑھا بھی ہوگا اور پھر پیچھے تصویر بھی‘ وغیرہ وغیرہ ۔ کہتے ہیں یہ سب قیاس باطل ہے۔ پھرکہتے ہیں کہ کچھ احمق قسم کے مشبہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے‘ اور مشبہ اور مجسمہ کی طرف سے اس طرح کی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جب ید ہے تو پھر بازو کے اثبات میں بھی‘ نعوذ باللہ‘ ایک باب باندھ دیاوغیرہ ۔کہتے ہیں کہ اس طریقے پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔یعنی امام صاحب کے زمانے میں بھی یہ رواج تھا۔
تصرفِ خامس : منع اجتماع متفرقین:یہ پانچویں قسم ہے ہمارے وظائف میں سے جس میں ہم نے لفظ میں تصرف نہیں کرنا اور تصرف کی چھ اقسام تھیں‘ اس میں سے پانچویں قسم آرہی ہے۔ وہ کیا ہے: لایجمعوا بین متفرق جو متفرق آیا ہے شریعت میں اس کو جمع نہ کیا جائے۔اللہ کے نبی ﷺ نے مختلف احادیث میں جیسے اللہ کے لیے یَدٌ کا ذکر کیا‘ رَأسٌ کا ذکر ہو گیا ‘ وَجْہٌ کا ذکر ہو گیا ‘ہنسنے کا ذکر ہوا ‘سَاقٌ کا ذکر ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی ایک مجلس میں نہیں کر رہے‘ مختلف مجالس میں کر رہے ہیں۔کسی مجلس میں جب آپ وہ لفظ لے کر آتے ہیں تو اس کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے‘ جس کے ذریعے اس کے معنی سمجھ میں آرہے ہوتے ہیں ۔تو یہ متفرق الفاظ وارد ہوئے ۔ اب کچھ لوگوں نے ایسی کتابیں لکھیں کہ ان سب چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا کہ باب فی اثبات الرأ س و باب فی الید یا باب فی الساق اور باب فی فلان وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری نصوص جمع کرنے سے جو نصوص الگ الگ جگہ وارد ہوئی تھیں تو وہ معنی جو الگ الگ سیاق و سباق ہونے کے اعتبار سے واضح تھا ‘وہ جمع کرنے میں اب مختلف ہو گیا۔ لہٰذا وہ معنی نہیں رہے کہ جو صحابہؓ اس سیاق میں سمجھ رہے تھے ۔ اور انہیں معلوم تھا کہ اس سے ہمارے جیسا اصلی رَأسٌ مراد نہیں لیا جا رہا ۔ اس طرح متفرقات کو جمع کرنے سے تخلیط ہو جاتی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے ۔کہتے ہیں کہ اللہ کے رسولﷺ سے یہ باتیں صادر ہوئی ہیں متفرق اوقات میں اور ایسے قرائن کے ساتھ کہ جو سننے والوں کو صحیح معنی سمجھادیتے تھے ۔ اب آپ یہ قرائن بھی نکال لیں اور وہ متفرق مقامات سب ایک جگہ جمع کردیں تو اللہ کے رسولﷺ کی وہ مراد حاصل نہیں ہوگی جو آپ کی مراد اس مجلس میں حاصل ہوتی تھی۔پھر عموماً یہ ہوتا ہے یعنی اس طرح تھوڑی ہے قرآن میں یا حدیث میں کہ اللہ کی ایک صفت رأس ہے‘ ایک صفت ید ہے ‘اس طرح تو نہیں آیا لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے اس طرح جمع کر لیا اور بہت غلط کیا ۔چنانچہ فرماتے ہیں: صنَّف کتاباً فی جمع الاخبار خاصۃ و رسم فی کل عضو بابا ’’ ایسی کتابیں لکھیں جن میں ان اخبارکو جمع کر دیااور ہر عضو کے بارے میں ایک باب الگ سے باندھا۔‘‘یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تصرف خامس ہے‘ جو حرام ہے کہ آپ متفرق کو جمع کر لیں ۔
تصرف سادس: منع تفریق مجتمعین: تصرف سادس یہ ہے کہ جو جمع ہے اس کو متفرق کرنا۔ یعنی جو تصرف خامس تھا اس کے بالکل برعکس۔ تصرف خامس تھا کہ آپ متفرق کو جمع کر لیں اور تصرف سادس یہ ہے کہ جو جمع ہے اس کو متفرق کر لیں۔ اس کی بہت زبردست مثال دی ہے ‘جس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب علیہ الرحمہ کی نگاہ کتنی گہری تھی۔ کہتے ہیں قرآن میں آیا:
{وَہُوَ الْقَاہِرُ فَوْقَ عِبَادِہٖ } (الانعام:۶۱)
’’اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے ۔‘‘
یہ پورا ایک جملہ ہے ‘صرف فوق نہیں آیا بلکہ {وَہُوَ الْقَاہِرُ فَوْقَ عِبَادِہٖ} ۔ اب قرآن میں فَوْقَ کا لفظ اس سیاق میں آ رہا ہے تو آپ اس میں سے صرف فَوْقَ نکال کر کہیں کہ اللہ کی صفت ایک فَوْقَ ہے‘ یعنی لہ فوقیہ! کہتے ہیں جو معنی قاھر کے لفظ کے ساتھ اور عبادہ کے لفظ کے ساتھ فَوْقَ کا سمجھ آ رہا ہے ‘ فَوْقَ کو اس جملے سے نکال کر الگ بیان کریں گے تو وہ معنی کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا {وَہُوَ الْقَاہِرُ فَوْقَ عِبَادِہٖ} سے بات واضح ہو رہی ہے کہ اس کی یہ فوقیت غلبے کی ہے‘ یہ مکانی فوقیت نہیں ہے۔ یہاں سے قاھر اور عباد کو حذف کر کے‘ الگ سے کتاب لکھ کر کہ باب فی اثبات الفوق‘ اور اس میں صرف فوق کا بیان ہو تو کہتے ہیں اس سے جو معنی پیدا ہوگا وہ قرآن کے سیاق و سباق سے نہیں ہو رہا ہوتا۔یہ بہت اہم بات ہے۔ اس میں انہوں نے{ اسْتَوی عَلَی الْعَرْشِ} کی مثال نہیں دی‘ وہاں بھی ایسا ہی ہے۔ { اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ} جہاں بھی قرآن میں آرہا ہے‘ آپ آگے پیچھے دیکھیں تو تدبیر امر کے بیان میں آتا ہے۔ اس بات کے بیان میں نہیں آ رہا کہ‘ نعوذ باللہ‘ اللہ تعالیٰ کہیں عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو سارے سیاق و سباق سے کاٹ کر { اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْش} کو الگ سے بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو اس سے وہ معنی پیدا ہو جائیں گے کہ جو قرآن کا مقصود نہیں ہیں ‘جو قرآن کے سیاق و سباق کے برعکس ہیں۔لہٰذا یہ تصرف بھی نہیں کیا جائے گا ۔
سات وظائف میں سے پانچ وظائف ہم نے پڑھ لیے ہیں جن میں سب سے پہلے تقدیس ہے ۔یہ پہلا وظیفہ ہے اور اس سے مراد جسمانیت سے تقدیس ہے۔ پھر تصدیق ہے کہ جو معنی برحق ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اجمالی معنی ہمیں حاصل ہوتا ہے ۔پھر اپنے عجز کا اور کم مائیگی کا اعتراف ہے۔ پھر سکوت ہے اور پھر اِمساک (رُک جانا) ہے۔رُکنے سے کیا مراد ہے:الفاظ میں تصرف نہ کیا جائے ۔پھر تصرف کی چھ اقسام انہوں نے بتائیں: وہ تفسیر ہے‘ وہ تاویل ہے‘ وہ صرف ہے یعنی پھیرنا صیغوں کو اور پھر تفریع ہے‘ اس پر قیاس نہیں کرنا اور پھر یہ ہے کہ جو متفرق ہے اس کو جمع نہیں کرنا اور جو جمع ہے اس کو متفرق نہیں کرنا ۔ بہرحال امام صاحب علیہ الرحمہ سلف کاجومسلک بیان کرتے ہیں ‘اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان باتوں میں دخل نہ دو جو تمہارے لیے لایعنی ہیں
((مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرکَہ مَا لَا یَعْنِیْہِ))(رواہ الترمذی)
’’آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی(کام) چھوڑ دے۔‘‘
ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں ‘ہماری قدر کتنی ہے ‘ ہمارا ظرف کتنا ہے ‘ ہمارا علم کتنا ہے ‘ ہمارا تقویٰ کتنا ہے اور پھر اس کے بقدر ہی ہمیں چھلانگیں مارنی چاہئیں۔